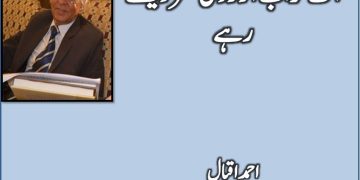کارو کاری
سُورج بالکل اس کے سَر سے چمٹا ہوا آگ بگولا ہو رہا تھا۔ گرمی کی شدت اور مسلسل بھاگنے کی وجہ سے اس کا وجود تپ کر اَنگارے کا رُوپ دھار چکا تھا۔ جبکہ منہ اور زُبان پاپڑ کی مانند خشک تھے۔ اسے معلوم تھا کہ اگلے کئی گھنٹے پانی کا ایک گھونٹ بھی ملنے والا نہیں‘ لبوں پر خشک زُبان پھیرتے ہوئے وہ اور تیزی سے قریبی ٹیلے پر چڑھنے لگی۔ ٹیلے پر چڑھنے کے بعد اس نے لمحے بھر کیلئے اپنی پھولتی سانسوں کو نارمل کیا اور پھر دُور پیچھے دیکھنے لگی۔ حدِنگاہ تک ریت کا سنسان کھیت لیٹا ہوا تھا جس کے اُوپر گرم لُو کی لہریں عجیب سے نقش و نگار بنا رہی تھیں۔ یہ سب دیکھتے ہوئے اسے گھر میں تپتے ہوئے تندور کا خیال آیا جو گرم ہو کر حرارت کی ایسی ہی لہریں اُگلا کرتا تھا اور آج وہ اسی تپتے تندور میں اُتر آئی تھی۔ اس کا سارا وجود ریت کے ذرّوں سے لتھڑا ہوا تھا اس نے معمولی سی پھول دار قمیض شلوار پہنی ہوئی تھی جو پسینے سے گیلی ہو کر اس کے وجود کے ساتھ چمٹ چکی تھی‘ اس نے دوپٹے میں کوئی چیز لپیٹ کر مضبوطی سے پکڑ رکھی تھی۔ ننگے پاؤں ریت کی حرارت سے سُرخ انگارہ ہو رہے تھے لیکن وہ انہیں نظرانداز کرتے ہوئے خوفزدگی سے پیچھے دیکھ رہی تھی۔
پھر وہ چونک اُٹھی۔ دُور اُونچے نیچے ٹیلوں کے درمیان کتنے ہی لوگ متحرک سایوں کی مانند اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ٹیلے کی اُونچائی سے وہ سب چونٹیوں کی مانند قطار دَر قطار تیزی سے چل رہے تھے جن کے ہاتھوں میں ہانپتے ہوئے شکاری کتوں کی زنجیریں اور خُونی برچھیاں دَبی ہوئی تھیں اگرچہ کم اَز کم چار گھنٹوں کی مسافت کا ان کے درمیان فرق تھا لیکن اتنے فاصلوں کے باوجود وہ جان سکتی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں کس قسم کے ہتھیار تھے اور وہ کیوں تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ پھر وہ انہیں نظرانداز کر کے اس جانب دیکھنے لگی جس جانب اسے اگلے چار پانچ گھنٹے مزید سفر کرنا تھا۔ اس کا ذہن ساری کاروائی کی حقیقت سمجھنے سے عاری تھا۔ وہ اس غلطی کی متلاشی تھی جس سے برادری والوں اور گاؤں والوں پر ان کے فرار کا راز افشا ہو چکا تھا۔
تبھی وہ ٹیلے سے نیچے اُتری اور اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ وہ تیزی سے قدم اُٹھا رہی تھی۔ اس کی منزل چار یا پانچ گھنٹوں کی مسافت پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے پُراُمید نگاہوں سے دور اپنے سامنے دیکھا اور ایسا کرتے ہوئے پچھلے دِنوں کے خیالوں میں کھو گئی۔ دُور پیچھے چالیس پچاس گھروں پر مشتمل ایک گاؤں تھا۔ جہاں اس نے اپنی زندگی کے بہترین دِن گزارے تھے‘ خوبصورت‘ حسین‘ شب و روز۔۔۔ ان کچے گھروں سے ذرا ہٹ کر قلعہ نما حویلی میں وہ بیاہ کر لائی گئی تھی۔ کتنی بھاگوان سمجھتی تھی خود کو۔۔۔ اس کا بچپن ایک تنگ و تاریک کمرے میں انتہائی غربت اور کسمپرسی کی زندگی گزارتے ہوئے گزرا تھا لیکن تنگ و ترش حالات کے صلہ میں قدرت نے اس پر ٹوٹ کر اپنی نوازش کی تھی۔ بس چڑھتی جوانی میں ایک دن چوہدری نواز کی نظر اس پر جا اَٹکی۔ خود وہ بھی بانکا جوان تھا۔ سفید گھوڑی پر سوار ہو کر جب دُھول اُڑاتا گاؤں کے قریب کچے راستے سے گزرتا تو مٹیاریں کھڑی ہو ہو کر اسے دیکھتیں۔ پھر بیاہ کر اسے وہ اس اُونچی قلعہ نُما حویلی میں لے آیا تھا اور یہی وہ دِن تھے جو اس کی زندگی کے خوشگوار ترین ایّام کہلا سکتے تھے۔
پتا نہیں یہ سوچتے سوچتے کیوں اس کی آنکھیں نمناک ہونے لگیں۔ پھر چلتے چلتے یکدم وہ رُک گئی اور اپنی دُھندلی نگاہوں سے اس آواز کو سننے کی کوشش کرنے لگی جو اس کے حواس کا دھوکا تھا۔۔۔ ہاں ایسے ہی وہ پکارتا تھا بہت دھیمے لہجے میں۔۔۔ جس میں انتہائی درجے کی شیرینی‘ ملاہٹ اور مٹھاس ہوتی تھی۔۔۔
جب وہ اپنی چمکدار آنکھیں اس پر گاڑ کر آہستہ آہستہ سے کہتا۔
’’زیبی۔۔۔‘‘ اور وہ بدک جاتی۔۔۔
پر وہ بدکی ہوئی اتھری سے اتھری گھوڑی کو بھی سدھانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔
’’زیبی۔۔۔ میری زندگی۔۔۔ میری رُوح۔۔۔ میری جان
ادھر دیکھ۔۔۔ تو اس پیاسی زمین پر میرے لیے نخلستان ہے۔ میری جان نخلستان۔۔۔ اے زیبی۔۔۔‘‘ کوئی اس کے بہت قریب سے پکارا۔۔۔
اس نے چاروں اور دیکھا۔۔۔ پر ہر طرف وہی ویرانی تھی۔ دُور دُور تک اسے کوئی ذِی رُوح نظر نہ آیا۔۔۔ تبھی یکدم ایک چیخ اس کے حلق سے نکلنے کے لیے بے قرار ہو گئی جس کا گلا گھونٹ کر وہ پھر چل پڑی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر اس کے چہرے کو تَر کرنے لگے۔
نواز کے بڑے بھائی اور باپ نے اس کے وجود کو کبھی بھی تسلیم نہ کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے شدید بغض رکھتے ہیں لیکن چوہدری نواز کے پیار کی موجودگی ہر دُکھ پر بھاری تھی۔ ہونی تو ہو کر رہتی ہے۔ ایک دن جب وہ سفید گھوڑی پر چڑھ کر نکلا تو پھر کبھی واپس نہ آیا۔ بس اسی روز سے اس کی زندگی کے دوسری قسم کے ایّام کا آغاز ہو گیا تھا۔
اب وہ اس حویلی میں ایک قیدی کی سی زندگی بسر کر رہی تھی۔ بالکل ایسے ہی جیسے گھر کے کسی کمرے میں کاٹھ کباڑ پڑا ہو جس کا کوئی مصرف نہ تھا۔ اِک فضول چیز‘ جس کی کوئی ضرورت اب کسی کو نہ تھی۔ ٹوٹی ہوئی کُرسی‘ میز یا ایسی ہی کوئی اور چیز۔۔۔ شائد وہ کاٹھ کباڑ کی طرح کی زندگی بھی خاموشی سے گزار لیتی۔ پر جلد ہی چوہدری نواز کے باپ اور بڑے بھائی کے ارادے اس پر کھلنے لگے۔
اور پھر اکیلی عورت ذات‘ کہاں تک مزاحمت کرتی۔۔۔ یوں ہر رات ایک نیا ڈرامہ سٹیج ہونے لگا۔۔۔ اُونچی حویلی جو دُور دُور کے گاؤں میں انصاف‘ ایمانداری اور رحمدلی کے سلسلہ میں مشہور تھی۔ اس سے انصاف کرنے لگی‘ اور وہ خاموشی سے یہ سب سہتی رہی۔ بے زُبان جانور کی مانند۔۔۔ اس کا اپنا آپ تو کب کا مر چکا تھا۔ ایک گوشت پوست کا وجود تھا جو زندہ تھا جس سے وہ دِن رات کھیل رہے تھے جو اس کا نصیب تھا۔۔۔ دو تین بار اس جہنم سے ناکام فرار کی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد آخر کار اس نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ تبھی اچانک اُمید کی ایک ناتواں سی کِرن چمکی۔ سکول ماسٹر کی صورت میں۔ گاؤں کا سکول برائے نام گورنمنٹ کا ادارہ تھا‘ حقیقت میں چوہدری نے کبھی بھی اس کو پنپنے نہ دیا تھا۔۔۔ یوں آنے والا ہر اُستاد چوہدری کی سازش کا شکار ہو کر بھاگ جاتا۔۔۔ اور سکول ویران ہو جاتا۔
اس روز وہ قریب ہی تھی جب چوہدری کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ ’’ماسٹر صاحب شودوں کو علم کی روشنی بانٹو گے تو صدیوں سے تاریکی میں رہنے والوں کی آنکھیں چندھیا جائیں گی۔۔۔ بابا۔۔۔ چندھیائی آنکھوں سے وہ چھوٹے بڑے کو کیا پہچانیں گے۔۔۔
جتنا علم چاہیئے۔ وہ انہیں ہم سے مل جاتا ہے۔ بابا۔۔۔
اس سے زیادہ کی انہیں ضرورت ہے نہ خواہش‘ یہاں جو پیدا ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ جوان ہو کر اپنے پُرکھوں کا سہارا بنے اور اپنے باپ دادا کا کام سنبھالے۔ یہ کام جیسا بھی ہو۔۔۔
علم۔۔۔ روشنی یہ سب فضول ہے۔۔۔ جاؤ بابا۔۔۔ اپنا کام کرو۔۔۔ اپنے گھر بیٹھو۔۔۔ روٹی لگ گئی تو اس کو کھاؤ بابا۔۔۔ ہم نہیں روکتے۔۔۔ پر ہم یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی کمی کمین کے گھر سے اُٹھے اور پڑھ لکھ کر ایسی زُبان میں ہمیں گالیاں دے کہ ہم سمجھ ہی نہ سکیں کہ تعریف کر رہا ہے یا کُچھ اور۔۔۔ اور وہ یہ سب گردن ڈالے حیرت سے گنگ خاموشی سے سُن رہا تھا۔ اس کی نگاہیں کبھی کبھی خُود کو گھیرے ہوئے نوکروں کے بازوؤں کی مچھلیوں پر بھی اُٹھ جاتیں تھیں جن کی آنکھوں میں خُون اُترا ہوا تھا۔
’’بابا پڑھانا ہے تو میرے بچوں کو پڑھا۔۔۔ جن کو ضرورت ہے۔۔۔ انہیں سکھا کہ کیسے بادشاہی کی جاتی ہے۔۔۔ ان کمی کمینوں پر۔۔۔
اگلے چند روز ہی میں اسے اس لنگڑے ماسٹر پر حقیقی رحم آنے لگا تھا جو اَب ایک طرح سے اسی کی مانند اس حویلی کا قیدی تھا۔ اگرچہ سرکار اسے تنخواہ دیتی تھی لیکن اس علاقے میں سرکار کی جگہ چوہدری کا سکّہ چلتا تھا۔ بس یہی جذبہ ایک خواب میں بدل گیا تھا جب اسے اس ماسٹر سے مُراد آباد شہر کی آزادی کا علم ہوا تھا۔۔۔
جہاں۔۔۔ عورت اور مرد دونوں برابر تھے۔
جہاں عورت کو تقدس کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔
بس یہی خواب آہستہ آہستہ ماسٹر سے بے نام سی محبّت کا رُوپ دھار گیا۔ اِک شدید خواہش۔۔۔
ذِلت کی اس زندگی سے چھٹکارا۔۔۔
اس نے چلتے چلتے کسی سایہ دار درخت کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن دُور دُور تک ریت کے ٹیلوں کے سوا اسے کُچھ نظر نہ آیا۔۔۔ پہلے بھی وہ فرار کی کوششیں کر چکی تھی۔۔۔ لیکن ناکام رہی تھی۔ اس بار۔۔۔ سب عین پروگرام کے مطابق ہوا تھا۔۔۔ ماسوائے اس کے کہ برادری والوں اور گاؤں والوں کو اس بابت پتا چل گیا تھا۔۔۔ اس علاقے میں چار گھنٹے کے سفر کا فاصلہ کافی تھا۔۔۔ اسے اس دوزخ سے نکل کر اس سڑک تک پہنچنا تھا جہاں پہلے سے ہی ماسٹر سواری کا انتظام کیئے اس کا انتظار کر رہا تھا۔۔۔
تپتی دُوپہر‘ آگ اُگلتا سورج‘ پیاس سے بے تاب حلق‘ تھکاوٹ سے چُور اعضاء‘ یہ سب اس پَل کوئی معنی نہ رکھتے تھے جس آگ میں وہ پچھلے دِنوں جلتی رہی تھی‘ جو عذاب ناک زندگی وہ گزار چکی تھی اس کے سامنے یہ سب حقیر تھا۔ اب یہ ساری تکلیفیں قریب المرگ تھیں۔۔۔
ظاہری شکل و صورت عام سی ہونے کے باوجود‘ ماسٹر کے لب و لہجے میں کُچھ ایسا جادو تھا کہ ایک دَم سے اسے نوازے کی رُوح ماسٹر کی آنکھوں میں مقید نظر آئی۔۔۔ اسے لگا جیسے ماسٹر ابھی سفید گھوڑی پر چڑھ کر آئے گا۔۔۔ اور یوں اس کے سارے دُکھوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بس اسی وجہ سے وہ ماسٹر کی اس لنگڑاہٹ کو بھی بھول گئی جو چلتے وقت اس کے سارے وجود کو عجیب سا دھچکا لگاتی تھی۔۔۔ چلتے چلتے اچانک اس کے قدم لڑکھڑائے۔۔۔ اور اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔۔۔ سنبھل تو وہ گئی لیکن اس جدوجہد میں اس کے ہاتھ میں پکڑی چیز دوپٹے سے علیحدہ ہو کر ریت پر جا گِری۔ جو سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ یہ شکاری چاقو تھا۔۔۔ تیز اور چمک دار دَھار والا چاقو۔۔۔ جو اس نے اس لیے ساتھ لے لیا تھا کہ آج وہ فیصلہ کر کے گھر سے نکلی تھی کہ آزادی کی زندگی یا عزت کی موت۔۔۔
اس نے جلدی سے چاقو کو اُٹھایا اور دوپٹے میں لپیٹ کر چل پڑی اَب اس کے قدم اور تیزی سے اُٹھنے لگے تھے۔۔۔ سورج سَر سے اُتر کر کندھوں پر چلا آیا تھا۔۔۔ لیکن اس کی حرارت پہلے سے بھی زیادہ چبھنے لگی تھی۔ آبرو مندانہ گھر کا سپنا پھر جاگ اُٹھا تھا۔ اس کے دُکھ کے دِن اَب کٹنے والے تھے۔ یہ سوچتے ہوئے اچانک اس خوفناک صحرا کے آگ برساتے موسم میں خوب صورت پھول کھلنے لگے۔ اِک عجیب سی ٹھنڈک اس کے خُون میں بہنے والی چنگاریوں کو ٹھنڈا کرنے لگی۔ خیالوں کے عجیب سے بہاؤ نے اسے اپنے سحر میں لے لیا لیکن یہ جذبے بھی زیادہ دیر اس کا ساتھ نہ نبھا سکے پھر وہ دوبارہ اسی تپتے صحرا میں آ موجود ہوئی۔۔۔ قریبی ٹیلے پر چڑھنے کے بعد اس کی نظریں پیچھا کرنے والے وجودوں پر ساکت ہو گئیں۔۔۔ اب وہ قدرے قریب پہنچتے نظر آ رہے تھے۔ وہ گھبرا کر ٹیلے سے اُتری اور بھاگنے لگی۔ تیز بھاگتے بھاگتے اس کا دَم گھٹنے لگا‘ اس کے حلق میں کانٹے سے اُگ آئے تھے۔ احساسات پر اِک عجیب سی دُھند اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پاؤں اپنی جسامت بڑھانے لگے تھے۔ اسے یوں لگا جیسے ایک ریت کے ٹیلے کے بعد دوسرا ٹیلہ اپنے آپ اُگ رہا ہو۔۔۔ اور یہ سلسلہ قیامت تک تمام نہ ہونے والا تھا۔ اگر اس دوزخ سے دُور ایک نئی زندگی کا سپنا اس کے وجود میں اپنے پنجے گاڑے موجود نہ ہوتا تو وہ خود کو وہیں ختم کر کے اس قصّے کو اس کے انجام تک پہنچا دیتی لیکن اسی شدید خواہش کے زیرِاثر وہ اپنے وجود کی لمحہ لمحہ مرتی ہوئی توانائیوں کو متحد کر کے بھاگ رہی تھی۔ اگرچہ تیز سیٹیوں جیسی آوازیں اس کے دماغ میں پیدا ہو کر اپنی شدت بڑھاتی جا رہی تھیں لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ وقفہ وقفہ سے کسی بلند جگہ سے اپنے دُشمنوں کو دیکھ کر اور تیزی سے متحرک ہو جاتی۔
پھر پتا نہیں دن کا وہ کون سا پہر تھا جب اس کی نظر کے سامنے ریت کے ٹیلوں نے ایک دَم اُگنا بند کر دیا۔ اب اس کی ڈھارس بندھ گئی تھی۔ اس کی منزل زیادہ دُور نہ تھی۔
وہ اس مقام پر پہنچنے ہی والی تھی جہاں اس کو صدیوں کی نسلی غلامی کے طوق کو توڑ کر ایک آزاد دُنیا میں چلے جانا تھا۔ وہ حیران تھی کہ یہ سب اتنی آسانی سے کیسے ہو رہا تھا۔۔۔ اس کا تعاقب کرنے والے لوگ پیچھے رہ چکے تھے۔ ان کا اس تک پہنچا اَب بہت مُشکل تھا۔
ایک نشیبی نالے سے نکل کر جیسے ہی وہ اُوپر چڑھنے لگی ایک عجیب سی آواز نے اس کے قدم تھام لیے اور اگلے ہی لمحے اس نے خود کو اس نشیبی نالے میں دوبارہ دَھکیل دیا۔
’’سرکار میں سچ کہتا ہوں۔۔۔ وہ اِدھر ہی آئے گی۔۔۔ ضرور آئے گی ادھر‘ میں معذور آدمی ٹھہرا۔۔۔ مجھے عشق وِشق سے کیا۔ یہ سب تو مَیں نے آپ کو دکھانے کے لیے کیا ہے۔ اَب کاروکاری کا انجام مجھ سے زیادہ کون جانے۔ پھر دو بیگھے زمین جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے۔۔۔ میرے تو نصیب بن گئے۔ آپ خاموشی سے ادھر ان جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپ جائیں جیسے ہی وہ آئے گی میں چیخ کر آپ کو مطلع کر دوں گا۔ ’’دیکھ ماسٹر یہ ہماری عزّت کا سوال ہے ساری برادری ہم پر تھوکے گی۔ مدت سے ہم نے کسی کو کاٹا نہیں۔۔۔ پر اگر وہ کسی اور سمت سے فرار ہو گئی تو‘ تو جانے تیرا کیا انجام ہونے والا ہے۔۔۔ ہم تو اس کا پہلے ہی ناش چاہتے تھے جو ہمارے بھائی کو نگل گئی۔۔۔ پر اب تو وہ خود ہی ہمارے بنے جال میں آ پھنسی ہے۔۔۔‘‘
’’سرکار خود ہی تو آپ نے کُچھ دوسرے لوگوں کو پروگرام کے مطابق اس کا پیچھا کرنے کو کہا تھا۔۔۔ وہ کہاں بھاگے گی۔۔۔ بس آنے ہی والی ہو گی۔‘‘
یہ سب سنتے ہوئے وہ اس نالے میں پڑی‘ اس لمحے عجیب و غریب جذبات کے اژدھام میں پھنس چکی تھی۔۔۔ اس کا وجود نالے میں بے جان سا پڑا تھا جیسے ماسٹر کی ساری محبّت اس کے وجود سے بہہ کر اس برساتی نالے کی مٹی میں مل جانے والی ہو۔
سارے سپنے‘ اس کے سہانے خواب پَل بھر میں اسی برساتی نالے میں دَفن ہو گئے تھے۔ تو کیا وہ سارے الفاظ اس کو پھنسانے کے لیے جال تھے۔ وہ محبّت صرف ایک سودا تھا دو بیگھے زمین کا سودا۔۔۔
تبھی نفرت کا ایک خوفناک جذبہ پیدا ہوا جس نے اس کے اَندر عجیب سی لہریں پیدا کرنی شروع کر دیں۔
’’سالے نے دو بیگھے زمین کے لیے اس کی نسل کو بیچ دیا۔۔۔ دوبارہ غلام کر دیا۔۔۔ پھر اس کا جی چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر سماج کے ان سب افراد‘ پر لعنت بھیجے جو صدیوں سے اپنے مفادات اور لالچ سے اَندھے ہو کر ایک پوری غلام نسل پیدا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پتا نہیں وہ اس عجیب سی کیفیت کا شکار ہو کر اس برساتی نالے میں کتنی دیر پڑی رہی۔ اس کے سامنے تارکول کی وہ سڑک جس پر چل کر اسے مرادآباد پہنچنا تھا خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی۔۔۔ چوہدری کا باپ اپنے نوکر کے ساتھ دُور جھاڑیوں کی اَوٹ میں چھپ چکا تھا۔ لنگڑا ماسٹر بے قراری سے ٹہل کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔۔۔ تبھی اس نے دوپٹے میں لپٹا ہوا شکاری چاقو نکالا۔۔۔ اور پھر تیزی سے نالے سے یوں نکل بھاگی کہ لنگڑا ماسٹر اس معاملے کی حقیقت کو نہ جان سکا اور حیرت سے اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھتا رہا۔۔۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچی اس کا ہاتھ ماسٹر کے نرخرے پر تیزی سے متحرک ہوا اور وہ منہ سے آواز بھی نہ نکال سکا۔۔۔ خون کی دھار سے اس کے سارے کپڑے لتھڑ گئے۔۔ پر وہ اس سے بے پروا خُون آلود چاقو لیے اس کے تڑپتے وجود کے قریب سینہ تانے کھڑی تھی۔۔۔
اس کے منہ سے اضطرابی طور پر دُکھ اور نفرت کے ملے جلے جذبات سے مغلوب لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ ’’اپاہج۔۔۔ سب اپاہج اس جاگیرداری نظام میں۔۔۔ سوچیں۔۔۔ قانون۔۔۔ سماج۔۔۔ تو پہلے ہی اپاہج تھا۔۔۔ پر اَب علم بھی اپاہج کر دیا سالے لنگڑے ماسٹر نے اور پھر اس نے نفرت سے تھوک دیا تھا۔ کتنی محبّت تھی اسے اس سے‘ لیکن اَب سب کُچھ جل کے راکھ ہو چکا تھا سُوکھی لکڑی کی مانند۔۔۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ نفرت اگلے چند لمحوں کے اَندر اس کے وجود کو بھی خاکستر کر دینے والی تھی۔
بڑھتے قدموں کی آوازیں آہستہ آہستہ اس کے قریب تر آتی جا رہی تھیں۔ برادری اور گاؤں کے دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑی برچھیوں کی زُبانیں کسی بھی پَل خُون چاٹنے کے لیے اس پر جھپٹنے والی تھیں۔ اس نے لمحے بھر کے لیے ان آوازوں کو نظرانداز کر کے اس سنگِ میل کو دیکھا جو شام کے اس جھٹ پٹے‘ میں افسردہ کھڑا اسے بے چارگی سے دیکھ رہا تھا اور جس کے وجود پر جلی حروف میں لکھا تھا ’’مُراد آباد سو کلومیٹر‘‘ پر اسے لگا جیسے مرادآباد سو کلومیٹر نہیں بلکہ سو صدیوں کے فاصلے پر ہو۔ تبھی وہ اپاہج ماسٹر کی ٹھنڈی ہوتی لاش‘ جس کے اِردگرد خُون کا تالاب سا بن کر جم چکا تھا کو اپنے قدموں تلے کچلتی ہوئی آگے بڑھی اور پھر بمشکل دوچار قدم اُٹھانے کے بعد بیچ سڑک کے ڈھ گئی۔
یہ تحریر فیس بُک کے اس پیج سے لی گئی ہے۔