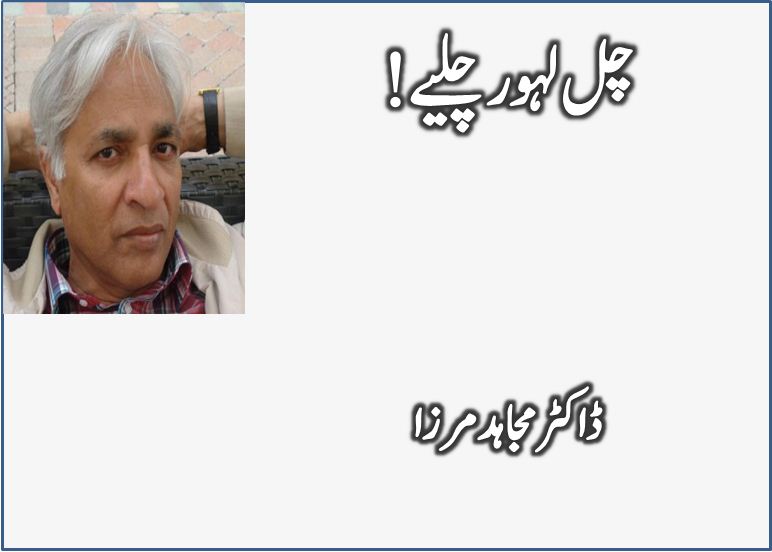چل لہور چلیے!
میں کئی ماہ سے ایک مضافاتی قصبے میں مقیم ہوں جہاں اب میرا کوئی شناسا نہیں رہا ویسے تو بیشتر شناسا اس عمر میں خود ناشناس ہو چکے ہیں تاہم مجھے گمان ہے کہ لاہور میں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جن سے ملنے کی تمنا اور سعی کی جا سکتی ہے۔ اور نہیں تو لاہور میں کچھ ادبی تقاریب ہوتی ہیں ان میں شرکت کی جا سکتی ہے۔
اب دنیا کچھ اور طرح کی ہو گئی ہے۔ فرزند محترم دن کے تین بجے بیدار ہوتے ہیں۔ شام چھ بجے کے بعد روانہ ہوتے ہیں اور سات ساڑھے سات بجے لاہور پہنچاتے ہیں۔ رات بہن کے ہاں کاٹنا پڑتی ہے۔ اگلے روز کسی سے ملاقات کرنی ہو یا کسی تقریب میں شریک ہونا ہو تو کریم ٹیکسی یا رکشا کام آتے ہیں۔
لندن سے میرے ہم جماعت عمومی جراح ( ختنہ ساز نہیں اصلی سرجن) لندن کی ایک مسجد کے خطیب، عربی خطبات اور خطوط پر مشتمل ایک اردو کتاب کے مصنف میر جمیل لاہور تشریف لا رہے تھے۔ دوستوں نے ان کے ساتھ "لا آتریم ریستوران" میں ملنا طے کیا تھا۔ وقت ملاقات ساڑھے تین سے ساڑھے پانچ سہ پہر مقرر تھا۔ فرزند موصوف نے بددلی سے نماز جمعہ کے بعد روانہ ہونے کی بات کر دی تھی لیکن میرے نماز جمعہ سے واپس آنے کے بعد بھی جناب محو خواب تھے۔ چنانچہ میں نے اپنے طور پر لاہور جانے کی ٹھان لی۔ خاتون خانہ نے کہا کہ وہ ٹیکسی کار منگوا دیتی ہیں لیکن نہ میں تین ہزار خرچ کرنے کا متحمل ہو سکتا تھا اور نہ ان پر بوجھ ڈالنا چاہتا تھا اس لیے کپڑے بدلے اور گھر سے چل دیا۔
جی ٹی روڈ کی بے مہابا ٹریفک سے گذر کر سڑک کے اس پار پہنچا، جہاں بہت سے "چنگ چی رکشے" کھڑے تھے۔ میں آتی ہوئی ایک لوکل بس پر اس کے اگلے دروازے سے سوار ہو گیا۔ پچھلا دروازہ مستقل بند تھا۔ میرے چڑھتے ہی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر گپ لگاتے ایک شخص نے کہا، "باؤجی نوں جگہ دیو" ۔ کنڈکٹر نے ڈرائیور کے ساتھ جڑی دو آدمیوں کی سیٹ کے پیچھے بند ایک سیٹ کو کھول کر مجھے بٹھا دیا۔ سیٹ کے پچھلی جانب کی سیٹ پر بیٹھی عورت کچھ بولی تو کنڈکٹر نے کہا،"میں نے سیٹ ہی تو کھولی ہے"۔ عورت بولی،" سیٹ کے پیچھے لوہا ہے۔ انسان لوہے کا مقابلہ نہیں کر سکتا"۔
میں بس کے اندر کی تصویر بنانے کے چکر میں تھا مگر ڈرتا تھا کہ عورتیں اعتراض نہ کر دیں۔ اگر وڈیو کیمرہ ہوتا تو سب گردن اونچی کرکے تصویر بنوا لیتیں کہ شاید کسی چینل پر دکھائی جائے گی یہ وڈیو۔ پھر میں نے سیلفی بنانے کا سہارا لیا اور تصویر اپ لوڈ کر دی، ساتھ لکھا،" لوکل بس میں ٹھنسا ہوا" حالانکہ بالکل بھی ٹھنسا ہوا نہیں تھا البتہ سیٹ کی بلندی کم ہونے اور اگلی سیٹ کے نزدیک ہونے کی وجہ سے پھنسا ہوا ضرور تھا۔
ڈرائیور اپنے ساتھی سے باتیں کرتا جاتا تھا۔ سواری اتارنے چڑھانے کے لیے بس روک لیتا تھا اور پھر چلا دیتا تھا، بالکل ایسے جیسے اہم بات باتیں کرنا ہے، بس تو چلتی رہتی ہے۔ جب شاہدرہ چوک نزدیک آنے کو تھا تو میں نے کنڈکٹر سے پوچھا،"میٹرو بس کہاں سے چلتی ہے؟" ڈرائیور کے ساتھ محو گفتگو شخص نے پوچھا،" آپ کو میٹرو بس میں سوار ہونا ہے، ہم وہیں آپ کو اتاریں گے۔ ایک جگہ پر کنڈکٹر نے بس روکے جانے پر " شاہدرہ چوک، میٹرو بس" کی آواز لگائی تو میں نے پوچھا کہ کیا یہیں اترنا ہے تو وہ بولا آپ بیٹھے رہیں۔ دور کچھ فاصلے پر میٹرو بس سٹیشن کی سیڑھیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ڈرائیور نے ان کے پاس جاکر بس روکی تو اس سے ہم کلام شخص نے کہا،"وہ دیکھیں اوپر لوگ ٹکٹ لے رہے ہیں"۔ کنڈکٹر بولا،" آپ پہلی بار سوار ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو یہاں اتارا ہے ورنہ ہم پہلے والی جگہ پر اتارتے ہیں"۔ میں "مہربانی، شکریہ" کہہ کر بس سے اترا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ احساس ہوا کہ معمر اور مریض لوگوں کے لیے زینے کچھ زیادہ ہیں۔ دیکھا تو لوگ لائن بنا کر ٹکٹ لے رہے تھے۔ جلد ہی مجھے بھی بیس روپے کے عوض ایک ٹوکن مل گیا۔ ٹوکن سلاٹ پر رکھنے سے پہلے میں نے وہاں کھڑے ہوئے چیکر سے پوچھا آیا پرنٹڈ سائڈ نیچے رکھنی ہے۔ اس نے کچھ کہا لیکن میں بتی سبز ہونے پر ٹرن پائک جھلا کر نکل لیا تھا۔ سٹیشن بے کی جانب گئے وہاں بھی لوگوں نے دو دروازوں پر قطاریں بنائی ہوئی تھیں۔ یہاں بس چونکہ خالی تھی اس لیے سیٹ آسانی کے ساتھ مل گئی۔ میں چونکہ پیچھے دروازے سے چڑھا تھا اس لیے سیٹ پیچھے تھی چنانچہ مجھے ایک سیلفی اور ایک تصویر بنانی پڑی۔ سیلفی میں بار بار میری شکل بہت اداس آ رہی تھے اس لیے میں نقلی مسکراہٹ مسکرایا اور اپ لوڈ کرتے ہوئے اس پر لکھا،" میٹرو کے پہلے سفر میں خوش ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے" دوسری تصویر پر لکھا، "میٹرو بس کا اندرونی منظر"۔ بس بھرنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک نقص فورا" سمجھ آ گیا کہ ہمارے لوگوں کو ابھی تک "سویلائزڈ ٹرانسپورٹ" میں سوار ہونا اور اترنا نہیں آتا۔ اصولی طور پر پہلے اترنے والوں کو اترنے دینا چاہیے اور پھر سوار ہونے والےچڑھیں مگر یہاں ہر دو اوتاولے تھے۔ اس طرح سبھی کے کندھے ٹکراتے ہیں اور الجھن ہوتی ہے، دل کھٹا ہوتا ہے، مزاج بگڑتا ہے۔
پہلا سفر تھا۔ نشست میسر تھی اگرچہ ساتھ بیٹھا نوجوان مسلسل موبائل پر باتیں کر رہا تھا۔ میٹرو بس میں بیٹھا کرولا دیے جانے کا مطالبہ کر رہا تھا کسی سے۔ میں نے فیس بک پر سٹیٹس لگایا،" میں میٹرو بس پر اپنے پہلے سفر کا لطف لے رہا ہوں۔ نجانے کیوں ( ایک کالم نگار کا نام ) اس کی مخالفت کرتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، کالم نگار کے حامیوں اور نواز حکومت کے مخالفوں کی آراء کی بھرمار شروع ہو گئی۔ ہمسفر نے جونہی بات تمام کی میں نے اس سے پوچھا کہ ٹوکن کیا اترتے ہوئے کام آئے گا۔ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ بس ضلع کچہری کے پاس سے گذر رہی تھی۔ بلندی سے اپنی الما ماتر گورنمنٹ کالج اور ناصر باغ کا منظر بہت دیدہ زیب تھا اوپر سے سنبل کے درختوں کے گل مہر جل رہے تھے۔
بس اب جنازگاہ کے نزدیک پہنچ چکی تھی۔ یہاں میٹرو بس کا ایک بڑا نقص نگاہوں کے سامنے آیا کہ بس بلندی پر ہونے کے سبب نچلے درمیانے اور غریب لوگوں کے گھر بے پردہ ہو گئے ہیں۔ لگتا ہے میٹرو بس کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے سماجی پہلووں کو مدنظر نہیں رکھا گیا یا پھر لوگ اتنے غیر روایتی ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کے بے پردہ ہونے پر بے پرواہ رہے۔
بڑے شہروں میں لوگوں کے لیے "مہذب ٹرانسپورٹ" کی فراہمی ضروری ہے۔ جی ہاں ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں کی بھی ضرورت ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ لاہور میٹرو بس پر ایک سو ارب روپے لاگت آئی اور جو سبسڈی دی جا رہی ہے وہ ملکی خزانے پر بوجھ ہوگی۔ درست کہتے ہونگے مگر سبسڈی سے لوگوں کے لیے سہولت ہو رہی ہے۔ لوگ خصوصا" نچلے درمیانے اور درمیانے طبقے کے لوگوں کے لیے۔
اگر اس پیسے سے ہسپتال بنانے ہوتے تو بہت اچھے ہسپتال دو چار ہی بن سکتے تھے اور کالج سکول بھی درجن یا چند درجن مگر کیا ملک بھر میں نظام صحت اور نظام تعلیم میں رائج انحطاط کا اثر ان پر نہ پڑتا۔ بالکل درست کہ اس منصوبے کی تکمیل میں بہت پیسے کھائے گئے ہونگے۔ سیڑھیوں پر لگی ٹائلیں ٹوٹ رہی ہیں۔ ٹکٹ گھر کے آگے لگا لکڑی کا چبوترہ بھر رہا ہے کیونکہ واپسی پر اس میں میرا پاؤں دھنسنے ہی والا تھا مگر ایک سہولت بہر حال لوگوں کو میسر آئی ہے۔ اس کی پذیرائی نہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں لگتی۔ جو کاروں میں بیٹھتے ہیں وہ میٹرو کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں یا انہیں علم ہی نہیں کہ اس سے لوگوں کو ایرکنڈیشند تیز رفتار ٹرانسپورٹ میسر آئی ہے۔ تبھی تو ان میں اتنا رش ہوتا ہے۔
میں کلمہ چوک پر اتر گیا۔ سڑک کے اس طرف آیا۔ وہاں آٹو رکشا کھڑے "مین مارکیٹ، میں مارکیٹ" کی آوازیں لگا رہے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک رکشے والے سے پوچھا کہ کیا مجھے حفیظ سنٹر جانے کے لیے سڑک کے پار دوسری سڑک پر جانا ہوگا۔ تو اس نے بتایا کہ رکشے اس طرف ہی جا رہے ہیں۔ فی سواری پندرہ روپے اور سالم رکشا ساٹھ روپے چنانچہ میں ساٹھ روپے دے کر مریدکے سے "لاآتریم ریستوران" میں ایک گھنٹے میں پہنچ گیا۔ ہم جماعت اور دوست پہنچے ہوئے تھے، سب خوش ہوئے۔ ڈاکٹر شبیر گورایا سے تو قریب چالیس برس بعد ملاقات ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دو کرسیاں چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ایک جوان شخص کو سلام کیا تو کسی نے پوچھا کہ "مرزا اسے جانتے ہو" میں نے کہا نہیں، وہ ڈاکٹر گورایا کا ڈاکٹر بیٹا تھا اور اس میں باپ کی جوانی کا نقشہ تھا۔
جب سب جانے لگے تو مجھے معروف ہارٹ سرجن بریگیڈیر ریٹائرڈ بلال بن یوسف نے کہا کہ وہ مجھے جہاں میں کہوں چھوڑ دے گا۔ جب ہم میری بہن کے گھر کے نزدیک تھے تو میں نے احتیاطا" فون کیا وہ دو روز کے لیے کہیں اور گئی ہوئی تھی۔ بلال سے میں نے کہا "چلو کرنل قمر کے ہاں چلتے ہیں"۔ قمر کے ہاں چل کر گپ شپ لگائی۔ مجھے تو اب مریدکے ہی جانا تھا چنانچہ پھر بریگیڈیر کو تکلیف دی اور وہ مجھے عسکری نائن سے سیکرٹریٹ چھوڑ گیا۔
جی ہاں اس سٹیشن کے ٹکٹ آفس کے باہر ٹکٹ لینے کی خاطرکھڑے ہونے کے لیے بنے لکڑی کے قدمچے میں میرا پاؤں دھنستے دھنستے بچا، لکڑی ٹوٹی ہوئی تھی۔
اس بار بس بھری ہوئی تھی۔ میں بس کے اگلے دروازے سے داخل ہوا اور مجھے خواتین کے حصے میں "ہینگنگ گرپ" پکڑ کر کھڑا ہونا پڑا۔ ایک اور خامی دکھائی دی کہ بس میں کھڑے ہونے کے لیے صرف کھلے حصے میں "گرپس" لگی ہوئی ہیں جبکہ باقی بس میں کھڑے ہوئے لوگوں کو نشستوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہینڈل بارز میں بہت سے گرپس لگائی جا سکتی ہیں۔
رات پڑ چکی تھی۔ جب شاہدرہ میٹرو سٹیشن کی سیڑھیوں سے اتر کر شاہدرہ موڑ کی جانب چلنے لگا تو مغالطہ ہوا کہ کہیں میں الٹی سمت تو نہیں جا رہا۔ گذرتے ہوئے ایک لڑکے سے پوچھا، شاہدرہ موڑ اس طرف ہی ہے تو اس نے اثبات میں جواب دینے کے ساتھ پوچھ لیا کہ آپ کو کہاں جانا ہے۔ میں نے بتایا تو اس نے کہا مجھے بھی وہیں جانا ہے۔ میں نے پوچھا "بس ملے گی"۔ اس نے جواب دیا بس تو نہیں، رکشا ملے گا۔ بند بھی ملتا ہے اور کھلے بھی۔ کتنی دیر میں پہنچتا ہے، میں نے پوچھا۔ پینتیس چالیس منٹ میں، اس نے بتایا۔ لیتے کیا ہیں کا جواب دیتے ہوئے اس نے کہا چالیس روپے سواری۔ بہتر ہے بس کا انتظار کرنے کی بجائے رکشا پکڑا جائے۔ میں روز جاتا ہوں، اس نے کہا۔ میرے کہنے پر اس نے بڑی کوشش کی کہ کوئی بند آٹو رکشا مل جائے لیکن کوئی تیار نہ تھا۔ وہی چنگ چی رکشا تھا جس کی اگلی نشست بھر چکی تھی۔ لڑکے نے کہا، "بیٹھ جائیں پیچھے"۔ ہم دونوں بیٹھ گئے، پھر تیسرا بھی اور رکشا چل پڑا۔ پچھلی نشست کے آگے پردے پڑے ہوئے تھے۔ لڑکے نے مسکرا کر کہا،"بند جیسا ہی مل گیا ہے"۔ اب اس رکشے نے اڑنا شروع کیا۔ پردوں میں ہوا بھر گئی وہ منہ کو آنے لگے۔ میں درمیان میں بیٹھا تھا اس لیے دونوں پردوں کو کھل جانے سے بچانے کے لیے ان کو جوڑ کر پکڑ لیا۔ کوفت ہوئی کیونکہ پردے غلیظ تھے۔ شاید مسافر عورتوں نے بچوں کی ناکیں ہی ان پردوں سے پونچھ دی ہوں۔ شام کو بارش ہوئی تھی۔ جب میں گھر سے نکلا تھا تو گرمی تھی۔ میں نے کوٹ کے نیچے آدھے بازووں والی سویٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ سردی سے کندھوں کے پٹھے اکڑ گئے مگر اڑتے ہوئے رکشے نے ہم دونوں کو منزل مقصود پر لا پھینکا تھا۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر میٹرو بس شاہدرہ سے مریدکے تک آتی ہوتی۔ یوں میں نے لاہور کا یہ چکر 160 روپے میں مکمل کر لیا۔
میں گذشتہ بائیس برس سے روس کی پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کر رہا ہوں۔ ماسکو کے علاوہ نیویارک، پیرس، لندن اور دیگر شہروں کا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم بھی دیکھا ہوا ہے چنانچہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ماسکو کا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم سب سے سریع، اچھا اور سستا ہے۔ میٹرو بس سروس لاہور پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے مجھے تو اچھی لگی۔ باقی جس کی مرضی کاروں میں بیٹھ کر اس بارے میں سیاست کرتا رہے۔
آخری بات کرنل قمر حسب معمول سماجی انصاف وغیرہ کی بات کر رہے تھے۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے نچلے درمیانے طبقے کی چمپا احمد کا حوالہ دیا جو لندن، روم، فرانس سے ڈگریوں کے ڈھیر سمیٹ کر مراد آباد کے اسی محلے میں اسی پسماندہ گھر میں پہنچی تھی، جہاں سے وہ گئی تھی۔ اذان ہونے پر غیر شعوری طور پر دوپٹہ بھی سر پر رکھ لیتی تھی۔ انقلابی تھی، تبدیلی لانے کی خواہاں تھی۔ جب قرہ العین کے ناول "آگ کا دریا" کے دوسرے کردار ابوالمنصور کمال الدین احمد نے، جو ویسا ہی پڑھا لکھا تھا اور ماضی میں ویسا ہی انقلابی لیکن بالآخر مصلحت اور صلح جوئی کے تحت پاکستان پہنچ کر بیوروکریٹ بن گیا تھا، اس سے پوچھا "باجی چمپا، اب آپ کیا کریں گی؟" تو چمپا احمد نے کہا تھا،" کمال میں تم سے بہت اچھی رہی ہوں کیونکہ میں نے سراغ پا لیا ہے اور وہی کروں گی جو کرنا چاہیے"۔ میں نے کرنل قمر اور بریگیڈیر بلال سے کہا کہ چار چار بنگلے اور کئی کئی گاڑیاں رکھ کر، بچوں کو اعلٰی تعلیم دلوا کر ہم جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟
یہ کالم فیس بُک کے اس پیج سے لیا گیا ہے۔
“