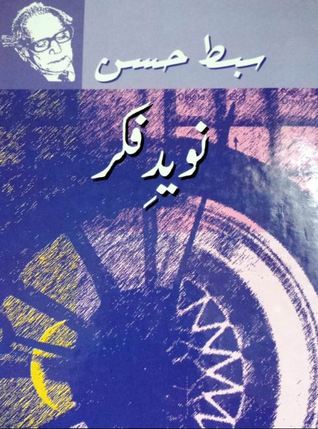ملائیت
لاہور 13 اپریل 1981ء
مولانا محمد عبداللہ درخواستی ، امیر نظام علمائے پاکستان نے فرمایا کہ سیاسی رہنماؤں ، کارکنوں اور مولویوں کو چاہیے کہ ملک میں سیکولرازم کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو جائیں۔ وہ کل شام جامعہ مدینہ کریم پارک میں علما سے خطاب کررہے تھے 1 علم و حکمت کا درخت بہتوں کو شجرِ حیات سے گمراہ کردیتا ہے اور جہنم کے عذابوں کی تمہید ہوتا ہے۔ پادری یوناؤن ترا۔ (1221ء۔ 1274ء)
سیکولراِزم
جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ کیسے مان لیں کہ بیماریاں اُڑ کر لگتی ہیں جب کہ شرعی قوانین ان سے انکار کرتے ہیں تو ان کو ہمارا جواب ہے کہ وبائی امراض کا وجود تجربے، تحقیق، حواسِ خمسہ کی شہادتوں اور معتبر روایتوں سے ثابت ہے۔ وبا کی حقیقت اس وقت واضح ہو جاتی ہے جب کوئی محقق یہ دیکھتا ہے کہ مریض کو چھونے والا خود اسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے جب کہ دور رہنے والا اس مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ وبائی مرض کپڑوں، برتنوں اور زیوروں کے ذریعے دوسروں کو لگتا ہے۔
(ابن خطیب غرناطوی، 1313ء۔ 1374ء)
کہتے ہیں کہ سقراط جب زہر کا پیالہ پی چکا تو اس کے شاگرد کریٹو نے پوچھا کہ اے استاد بتا کہ ہم تیری تجہیزو تکفین کن رسموں کے مطابق کریں۔ ” میری تجہیزو تکفین؟” سقراط ہنسا اورپھر سنجیدہ ہو کر کہنے لگا کہ ” کریٹو! میں نے تم لوگوں کو تمام عمر سمجھایا کہ لفظوں کو ان کے صحیح معنی میں استعمال کیا کرو مگر معلوم ہوتا ہے کہ تمھیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ کریٹو! یاد رکھو کے لفظوں کا غلط استعمال سب سےبڑا گناہ ہے۔”
ہمارے ملک میں ان دنوں سیکولرازم کی اصطلاح کے ساتھ یہی ناروا سلوک ہو رہا ہے۔ ملاؤں کا تو ذکر ہی کیا اچھے خاصے پڑھے لکھے سیاسی لیڈر اور اخباروں کے ایڈیٹر حضرات بھی لوگوں کو سیکولرازم سے بدگمان کرنے کی غرض سے اس کے معنی و مفہوم کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور یہ تاثر دینا چاہتے ہیں گویا سیکولرازم ایک عفریتی نظام ہے جس سے بے دینی، دہریت اور بد اخلاقی پھیلتی ہے اور فتنہ و فساد کے دروازے کھلتے ہیں لہذا سیکولر خیالات کا سدِ باب نہایت ضروری ہے ورنہ اسلام اور پاکسان دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ آئیے اس جھوٹ کا جائزہ تاریخی سچائیوں کی روشنی میں لیں۔
سیکولر اور سیکولرازم خالص مغربی اصطلاحیں ہیں۔ لاطینی زبان میں ” سیکولم” Seculum کے لغوی معنی دنیا کے ہیں۔ قرونِ وسطیٰ میں رومن کیتھولک پادری دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک وہ پادری جو کلیسائی ضابطوں کے تحت خانقاہوں میں رہتے تھے۔ دوسرے وہ پادری جو عام شہریوں کی سی زندگی بسر کرتے تھے۔ کلیسا کی اصطلاح میں آخر الذکر کو ” سیکولر” پادری کہا جاتا تھا۔ وہ تما م ادارے بھی سیکو لر کہلاتے تھے جو کلیسا کے ماتحت نہ تھے اور وہ جائیداد بھی جس کو کلیسا فروخت کردیتا تھا۔ ” آج کل سیکولرازم سے مراد ریاستی سیاست یا نظم ونسق کی مذہب یا کلیسا سے علیحدگی ہے اور سیکولر تعلیم د ہ نظام ہے جس میں دینیات کو تعلیم سے الگ کردیا جاتا ہے۔” 2
انسائکلوپیڈیا امریکا نا میں سیکولرازم کی تشریح اور زیادہ وضاحت سے کی گئی ہے۔ انسائیکلو پیڈیا امریکانا کے مطابق ” سیکولرازم ایک اخلاقی نظام ہے جو قدرتی اخلاق کے اصول پر مبنی ہے اور الہامی مذہب یا مابعد الطبیعات سے جدا ہے۔ اس کا پہلاکلیہ فکر کی آزادی ہے یعنی ہر شخص کو اپنے لیے کچھ سوچنے کا حق۔ 2۔ تمام فکری امور کے بارے میں اختلافِ رائے کا حق۔ 3۔ تمام بنیادی مسائل مثلاً خدا یا روح کی لافانیت وغیرہ پر بحث مباحثے کا حق۔ سیکولرازم یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ موجودہ زندگی کی خوبیوں کے علاوہ کوئی اور خوبی نہیں ہے۔ البتہ اس کا مقصد وہ مادی حالات پیدا کرنا ہے جن میں انسان کی محرومیاں اور افلاس نا ممکن ہو جائیں۔” 3
ڈاکٹر مولوی عبدالحق کی انگلش اردو ڈکشنری کے مطابق سیکولرازم اس معاشرتی اور تعلیمی نظام کو کہتے ہیں جس کی اساس مذہب کے بجائے سائنس پر ہو اور جس میں ریاستی امور کی حد تک مذہب کی مداخلت کی گنجائش نہ ہو۔4
سیکولر خیالات بہت قدیم ہیں لیکن سیکو لر ازم کی اصطلاح جارج جیک ہولی اوک George J. Holyoake نامی ایک آزاد خیال انگریز نے 1840ء میں وضع کی۔ وہ شہر برمنگھم کے میکنکس انسٹی ٹیوٹ میں استاد تھا۔ برطانیہ کے مشہور خیالی سوشلسٹ رابرٹ اووین (1771ء۔1857ء) کے ہم نوا ہونے کے جرم میں بر طرف کردیا گیا تھا اور کل وقتی مبلغ بن گیا تھا۔ ان دنوں لندن سے آزاد خیالوں کا ایک رسالہ ” ندائے عقل” نکلتا ہے۔ 1841ء میں جب رسالے کے ایڈیٹر کو دینِ مسیح کی بے حرمتی کے جرمیں ایک سال قید اور سو پونڈ جرمانے کی سزا ہو گئی تو ہولی اوک کو رسالے کا ایڈیٹر مقرر کردیا گیا لیکن ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ہولی اوک کو بھی ایک تقریر کی پاداش میں چھ ماہ کی قید کی سزا بھگتنی پڑی۔ جیل سے نکلنے کے بعد آزاد خیالی کے حق میں مسلسل تقریریں کرتا اور رسالے لکھتا رہا۔ 1851ء میں اس نے لندن میں سینٹرل سیکولر سو سائٹی کے نام سے ایک انجمن قائم کی۔ ہولی اوک کا موقف یہ تھا کہ:
1۔ انسان کی سچی رہنما سائنس ہے ۔
2۔ اخلاق مذہب سے جدا اور پرانی حقیقت ہے۔
3۔ علم و ادراک کی واحد کسوٹی او ر سند عقل ہے۔
4۔ ہر شخص کو فکر اور تقریر کی آزادی ملنی چاہیے۔
5۔ ہم کو اس دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
سیکولر ازم کو معاشرتی نظام کے لیے درست سمجھنے سے دین دار بے دین اور خدا پرست دہریہ نہیں ہو جاتا لہذا سیکو لر ازم سے اسلام کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے اور نہ اس سے پاکستان کی بقا و سالمیت پر کوئی ضرب پڑتی ہے بلکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ سیکو لر اصولوں ہی پر چل کر پاکستان ایک روشن خیال ، ترقی یافتہ اور خوش حال ملک بن سکتا ہے۔سیکولرازم کا مقصد معاشرے کی صحت مند سماجی اور اخلاقی قدروں کو پامال کرنا نہیں بلکہ سیکو لر ازم ایک ایسا فلفسہ حیات ہے جو خرد مندی اور شخصی آزادی کی تعلیم دیتا ہے اور تقلید و روایت پرستی کے بجائے عقل و علم کی اجتہادی قوتوں کی حوصلہ افزائی کرتاہے۔ چنانچہ سیکو لرازم کی تبلیغ کرنے والوں کی برابر یہی کوشش رہی ہے کہ انسان کے عمل و فکر کو توہمات کے جال سے نکالا جائے۔ یہ کوئی انوکھا فلسفہ نہیں ہے۔ ہمارے صوفیائے کرام بھی یہی کہتے تھے کہ سچائی کو خود تلاش کرو، خود پہچانو اور جو رشتہ بھی قائم کرو خواہ وہ خالق سے ہو مخلوق سے معرفت حق پر مبنی ہو نہ کہ انعام کے لالچ اور سزا کے خوف پر۔ حضرت رابعہ بصری کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک روز وہ بصرے کی سڑک پر سے گزر رہی تھیں اس حال میں کہ ان کے ایک ہاتھ میں مشعل تھی اور دوسرے میں پانی کی صراحی۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو انھوں نے کہا کہ میں جنت کو آگ لگانے اور دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں تاکہ مسلمان جزا اور سزا کی فکر سے آزاد ہو کر خدا سے بے لوث محبت کرنا سیکھیں۔
جو لوگ عقل و اجتہاد کی جگہ تقلید و اطاعت پر زور دیتے ہیں وہ خود مذہب کی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ ذرا سوچیے کہ اگر حضرت ابراہیمؑ نے روایت پرستی کا شیوہ اختیار کیا ہوتا، اپنے آبائی مذہب پر قائم رہتے اور اس کو عقلی دلائل سے رد نہ کرتے تو دینِ ابراہیمی کہاں ہوتا۔ غالب نے اسی نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ
بامن میاویز اے پدر! فرزندِ آذر رانگر
ہر کس کہ شد صاحب نظر، دینِ بزرگان خوش نہ کرو
غالب تو خضر کے سے راہبر کی پیروی کو بھی لازم نہیں سمجھتا بلکہ ان کو اپنا ہم سفر خیال کرتا ہے۔
سیکولرازم کی بنیاد اس کلیے پر قائم ہے کہ ضمیر و فکر اور اظہارِ رائے کی آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے لہذا ہر فردِ بشر کو اس کی پوری پوری اجازت ہونی چاہیے کہ سچائی کا راستہ خود تلاش کرے اور زندگی کے تمام مسائل پر خواہ ان کا تعلق سیاسیات اور اقتصادیات سے ہو یا مذہب و اخلاق سے، فلسفہ و حکمت سے ہو یا ادب و فن سے ، اپنے خیالات کی بلا خوف و خطر ترویج کرے۔طاقت کے زور سے کسی کا منھ بند کرنا یا دھمکی اور دھونس سے کسی کو زبردستی اپنا ہم خیال بنانا حقوقِ انسانی کے منافی ہے اور اس بات کا اقرار بھی کہ بحث و مباحثے میں ہم اپنے حریف کی دلیلوں کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔
جبری زبان بندی کے نتائج بھی معاشرے کے حق میں بڑے مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ ملک کی فضا میں گھٹن او ر اُمس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، قوم کی کمر جھک جاتی ہے اور اس کے سجدے بقول اقبال طویل ہو جاتے ہیں، خوف اتنا بڑھ جاتا ہے شاخِ گل کا سایہ بھی سانپ بن کر ڈرانے لگتا ہے، لوگ اقتدار کی خوشنودی ہی کو زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں اور سوچنا، سوال کرنا، شک کرنا یا انکار کرنا ( جو علم و معرفت کی یہلی شرط ہے) ترک کردیتے ہیں خوف سے بزدلی، بزدلی سے تابعداری اور تابعداری سے غلامانہ ذہنیت جنم لیتی ہے۔ جرات و بے باکی کا نام و نشان باقی نہیں رہتا، تلاش و جستجو اور تحقیق و تفتیش کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے تجربے کے بازو شل اور مشاہدے کی آنکھیں کو ر ہو جاتی ہیں، ایجاد و تخلیق کےسوتے سوکھ جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ ایک ایسی نسل وجود میں آتی ہے جو ذہنی طور پر مفلوج اور عملی طورپر اپاہج ہوتی ہے۔ بھیڑوں کا یہ گلہ جو نہ خودبین ہو نہ جہاں بیں، بقا و ترقی کی جد و جہد میں ان قوموں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے جو اپنی تخلیقی قوتوں میں اضافے کی مسلسل کوشش کرتی رہتی ہیں اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں سر گرداں رہتی ہیں۔
فکرو عمل کی قوانینِ قدرت سے ہم آہنگی کا نام سیکولرازم ہے اور اگر قوانینِ قدرت کی خلاف ورزی کی جائے تو انسان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ انسانی تخلیق کا ہر عمل چوں کہ قوانینِ قدرت کے مطابق ہوتا ہے لہذا شعر کہنا ہو یا تصویر بنانا، کھڈی پر کپڑا بننا ہو یا ہوائی جہاز اڑانا ہم اپنے کاموں کے دوران سیکولر انداز اختیار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، ہم مانیں یا نہ مانیں لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ہمارے عمل کی ذمہ داری ہم پر ہے اور اس میں کسی ماورائی طاقت کا دخل نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ کر قتل کے الزام سے ہر گز بچ نہیں سکتے کہ ہم کو خواب میں قتل کرنے کاحکم دیا گیا تھا۔ بیماریوں کا علاج اور حفظانِ صحت کے طور طریقے بھی سیکولر اصولوں ہی پر وضع ہوتے ہیں مگر پرانے زمانے میں انسان قوانینِ قدرت سے بہت کم واقف تھا لہذا مظاہر قدرت سے ڈرتا تھا۔ ان کی پوجا کرتا تھا اور ان کے لطف و کرم کا طالب رہتا تھا۔ کانسی کی تہذیب کے زمانے میں وادی نیل، وادی دجلہ و فرات اور وادی سندھ میں بڑی بڑی تہذیبیں ابھریں اور انسان نے اپنے آرام و راحت کے لیے بے شمار نئی نئی چیزیں بنائیں لیکن اس کا شعور ہنوز تجرباتی تھا۔ استدلالی نہ تھا۔ وہ اپنی ایجادوں اور دریافتوں سے کوئی سائنسی کلیہ یا نظریہ اخذ نہ کرسکا۔ اس کا عمل سیکو لر تھا لیکن اس کی سوچ سیکولر نہ تھی۔
مغرب میں سیکولر خیالات کی ابتدا آئیونا (مغربی ترکی) کے نیچری فلسفیوں سے ہوئی جو یونانی الاصل تھے۔ طالیس، انکسی ماندر، ہرقلاطیس اور دیمقراطیس وغیرہ مظاہر قدرت کی تشریح خود عناصر قدرت کے حوالے سے کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ کائنات کا اصل اصول پانی ہے، کسی نے کہا نہیں آگ ہے، کسی نے کہا ہوا ہے اور کسی نے کہا ایٹم ہے۔ ان میں بیش تر یونانی خداؤں کے قائل تھے لیکن دیناوی حقیقتوں کی تشریح وہ سیکولر انداز میں کرتے تھے۔ یونان کی شہری ریاستوں بالخصوص ایتھنز کا نظام ریاست بھی سیکولر تھا البتہ لوگ دیوتاؤں کی باقاعدہ پرستش بھی کرتے تھے۔
یونان کے زوال کے بعد جب مغربی سیاست کا مرکز روم منتقل ہو گیا تو نظم و نسق کے تقاضوں کے سبب اربابِ اختیار کو وہاں بھی سیکولر طرزِ عمل اختیار کرنا پڑا۔ ابتدا میں قانونی دستاویزیں روم کے پروہتوں کے قبضے میں رہتی تھیں۔ قوانین کی تشریح اور تاویل کا حق انہیں کو حاصل تھا اور قوانین سے متعلق مذہبی مراسم کی ادائیگی بھی انہیں کی اجارہ داری تھی لہذا پروہت جن کا تعلق امرا کے طبقے سے تھا اپنے ان وسیع اختیارات سے خوب فائدے اٹھاتے تھے۔ 451 ق۔م میں جب روم میں پروہتوں کی دراز وستیوں کے خلاف بغاوت ہوئی تو رومن سینٹ نے قوانین کو ” بارہ لوحوں” میں قلم بند کر کے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اور تب ” رومن لا” کا سیکولر دور شروع ہوا۔ ملکی قوانین سینیٹ بنانے لگی۔ تیسری صدی قبلِ مسیح میں پروہتوں کے بجائے وکیل عدالتوں میں پیش ہونے لگے تو امورِ ریاست میں پروہتوں کا اثر اور کم ہوگیا۔
پہلی صدی عیسوی میں رومی معاشرے میں ایک نیا مشرقی عنصر داخل ہوا جس نے یورپ والوں کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ یہ عنصر عیسائی مذہب کا تھا۔ حضرتِ مسیحؑ کا حکم تھا کہ خدا کا حق خدا کو دو اور قیصرِ روم کا حق قیصرِ روم کو دو۔ ان کے شاگردوں نے پیغمبر خدا کی ہدایت پر عمل کیا مگر قیصر روم کو مسیحی تعلیمات کسی صورت گوارہ نہ تھیں چنانچہ پطرس اور پال نے جب روم میں تبلیغ شروع کی تو ان کو صلیب دے دی گئی۔ دوسرے کئی مبلغوں کا بھی یہی حشر ہوا اور عام عیسائیوں پر جو عموماًٍ غریب یا غلام ہوتے تھے ہولناک مظالم توڑے گئے۔ تقریباً تین سو سال تک یہی عالم رہا لیکن اس بیداد کے باوصف عیسائی مذہب کی مقبولیت بڑھتی رہی اور آخر کار شہنشاہ قسطنطین (274ء۔ 337ء) کو اعلان کرنا پڑا کہ ” عبادت کی آزادی سے کوئی شخص محروم نہیں کیا جائے گا اور ہر فردِ بشر کو اختیار ہوگا کہ الوہی امور کا تصفیہ اپنی مرضی سے کرے” مگر 313ء میں جب قسطنطین خود عیسائی ہو گیا تو غیر مسیحی آبادی پر ستم ڈھایا جانے لگا۔ 346ء میں تمام غیر مسیحی عبادت گاہیں بند کر دی گئیں۔ پرانے رومن دیوتاؤں کو قربانی پیش کرنے کی سزا موت قرار پائی اور عبادت گاہوں کی جائیدادیں ضبط کر کے کلیسا کے حوالے کردی گئیں۔ جو کل تک مظلوم و مفلس تھے دفعتاً صاحبِ جاہ و چشم بن گئے۔ روم کلیسا کا صدر مقام قرار پایا کیوں کہ پطرس اور پال کی ہڈیاں وہیں دفن تھیں۔ پاپائے روم پطرس کا جانشین اور عیسائیوں کا روحانی پیشوا تسلیم کر لیا گیا۔ کلیسا کا دور اقتدار شروع ہو گیا۔ شہنشاہ قسطنطین نے اس سے پہلے ہی شمالی یورپ کی وحشی قوموں کے حملے سے بچنے کی غرض سے اپنا دارالسلطنت روم سے قسطنطنیہ (استنبول) منتقل کردیا تھا جو یقیناً زیادہ مرکزی اور محفوظ جگہ تھی۔ اس کی موت کے بعد تاج و تخت کے لیے جھگڑے شروع ہوگئے اور سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی۔ایک قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت اور دوسری مغربی سلطنت جس کا صدر مقام روم تھا۔
مگر مغربی سلطنتِ روما کے قدم ابھی جمے نہ تھے کہ مشرقی یورپ سے گوتھ اور ہن قوموں نے بڑے پیمانے پر ترکِ وطن کر کے مغربی یورپ پر یلغار کردی۔ 410ء میں انھوں نے روم کو بھی تاخت و تاراج کردیا۔ لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا یہ سلسلہ پچاس ساٹھ سال تک جاری رہا۔ اس اثنا میں گوتھ قوم نے اسپین ، فرانس اور اٹلی کے کئی علاقوں میں اپنی ریاستیں بھی قائم کرلیں اور شہنشاہ روم گوتھ سرداروں کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بن گئے۔ 476ء میں ایک سردار نے آخری شہنشاہ آگسٹولس کو تخت سے اُتار دیا اور خود حکومت کرنے لگا۔ مغربی سلطنتِ رومہ ہمیشہ کےلیے ختم ہوگئی۔
ان وحشی قوموں نے کلاسیکی روم کا ہزار سالہ تہذیبی سرمایہ نیست و نابود کردیا اور کچھ عرصے بعد وہاں قدیم علم و ادب کے آثار بھی باقی نہ رہے۔ یورپ بربربیت کے اندھیرے میں ڈوب گیا۔
البتہ سلطنتِ روما کا زوال رومن کلیسا کے حق میں بڑی نعمت ثابت ہوا۔ قسطنطنیہ کی مانند اگر روم میں بھی کوئی مضبوط مرکزی حکومت ہوتی تو رومن کلیسا کی حیثیت وہاں وہی ہوتی جو بازنطینی سلطنت میں پادریوں کی تھی۔ وہ شہنشاہ کی اطاعت پر مجبور ہوتے اور کبھی دعوے کرنے کی جرات نہ کرتے کہ کلیسا ریاست سے ارفع و اعلیٰ ادارہ ہے۔ روم میں شہنشاہیت کے خاتمے اور وحشی قوموں کے حملوں کی وجہ سے یورپی معاشرے میں جو خلا پیدا ہوا اس سے کلیسا کو اپنی سیاسی طاقت کو بڑھانے میں بڑی مدد ملی۔ پادریوں نے اطالوی تہذیب کی بچی کچھی نشانیوں کو وحشی گوتھوں کی دست برد سے بچایا اور اس میں کئی شبہ نہیں کہ ” تاریکی اور خلفشار کے اس دور میں پطرس کے جانشین مغربی یورپ کے طوفانی سمندر میں مینارۂ نور ثابت ہوئے”5 یہ پادری لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ایسٹر اور دوسرے مذہبی تیوہاروں کے دن تاریخ کا حساب کر سکتے تھے۔ پیدائش، شادی بیاہ اور موت کی رسمیں ادا کرتے تھے اور حکام کے رُوبرو مصیبت زدوں کی داد فریاد پیش کر سکتے تھے۔ غرضیکہ عہدِ تاریک میں عوام کا واحد سہارااگر کوئی تھا تو یہی پادری تھے۔ کلیسا نے قرونِ وسطیٰ میں عقیدت مندوں کے دلوں میں اگر گھر کر لیا اور اس کا اثر و اقتدار بڑھا تو اس کے معقول اسباب تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کلیسا نے اس صورت حال سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور آگے چل کر معاشرتی ترقی کی راہ کا روڑا بن گیا۔
یورپ کے نئے حاکموں نے بھی کلیسا سے کوئی تعرض نہ کیا بلکہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی کیوں کہ پادریوں کے تعاون کے بغیر وہ حکومت نہیں کرسکتے تھے۔د وسری طرف کلیسا نے بھی وفاداری ہی میں عافیت سمجھی ( مذہبی پیشواؤں کو اقتدار سے سمجھوتہ کرنے میں عموماً زیادہ دیر نہیں لگتی خواہ اقتدار کسی کے قبضے میں ہو) رومتہ الکبریٰ کے دور میں حکام اور امرا اور رؤسا پادریوں کو بالکل خاطر میں نہ لاتے تھے۔ اس کے برعکس نئے حاکم جو اُجڈ اور توہم پرست تھے پادریوں کی باتیں بڑی عقیدت سے سنتے تھے۔
مغربی مورخین قرونِ وسطیٰ کو عہدِ تاریک سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک پانچویں صدی اور پندھویں صدی عیسوی کا درمیانی زمانہ معاشرتی اور تہذیبی سرگرمیوں کے لحاظ سے انتہائی پستی کا زمانہ تھا لیکن معاشرتی ادوار کا سن و سال متعین نہیں کیا جا سکتا، معاشرتی دور کوئی تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ارتقائی عمل ہے جس کی ابتدا یا انتہا کی نشان دہی ممکن نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرونِ وسطیٰ کی شام آہستہ آہستہ ہوئی اور نئی زندگی کی پو آہستہ آہستہ پھٹی۔ چنانچہ یورپ میں سیکولر اداروں اور فکروں کی نشو و نما تیرھویں صدی عیسوی میں شروع ہو گئی تھی۔ یہ بڑی تاریخ ساز صدی تھی۔ اسی صدی میں اٹلی میں ابھرتے ہوئے سرمایہ داری نظام نے طاقت پکڑی اور سیکولر افکار مسلم اسپین اور سسلی کی راہ سے یورپ میں داخل ہوئے مگر تاریخ کی ستم ظریفی دیکھئے کہ جس مذہب کے عظیم دانشوروں ،ا لکندی، ابوبکررازی، بو علی سینا، ابن ہیثم ، خوارزمی، البیرونی اور ابنِ رشد نے مغرب کو سیکولر خیالات اور نظریات کی تعلیم دی اسی مذہب کے نام لیوا آج سیکولرازم پر اسلام دشمنی کی تہمت لگا رہے ہیں۔
انگریز مورخ پروفیسر فشر کو اس بات پر بڑی حیرت ہے کہ سیکولر خیالات اٹلی میں شروع ہوئے جو کلیسائیت کا سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ تیرھویں صدی کی فکری تحریکوں پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ:
” یہ اُلٹی بات ہے کہ اٹلی جو کلیسا کا مرکز تھا پورے تاریخی دو ر میں مغربی ملکوں میں سب سے زیادہ سیکولر تھا”۔6
لیکن یہ ہر گز اُلٹی بات نہیں بلکہ سیدھی بات ہے اس لیے کہ جنگ صلیبیہ کے دوران صنعت و حرفت اور تجارت نے دوسرے تمام مغربی ملکوں سے پہلے اٹلی میں ترقی کی۔ صلیبی جنگوں کا بظاہر مقصد عیسائیوں کے مقدس شہروں ، یروشلم، بیتِ لحم وغیرہ کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑانا تھا لیکن اصل مقصد مشرقی بحرِ روم کی تجارت پر اور تجارتی راستوں پر قبضہ کرنا تھا۔ صلیبی سورما فلسطین و شام کو تو آزاد نہ کروا سکے البتہ مشرقی بحر روم کی تجارت پر اٹلی کی ری پبلکن ریاستوں کا غلبہ ہو گیا۔ یہ ریاستیں بالخصوص وینس، میلان، فلورنس اور جینوا شہری ریاستیں تھیں۔ ان کا دارو مدار تجارت اور صنعت و حرفت پر تھا۔ کلیسا کا اثر ان علاقوں میں برائے نام تھا بلکہ کلیسا سے اکثر ان کی ٹکر ہوتی رہتی تھی۔ کلیسا چوں کہ ملک کا سب سے بڑا زمین دار تھا لہذا اس کا مفاد فیوڈلزم سے وابستہ تھا جن کہ ری پبلکن ریاستیں سرمایہ داری نظام کی حوصلہ افزائی کرتی تھیں۔
سیکو لر درس گاہوں کی ابتدا اگر اٹلی میں ہوئی تو یہ بھی کوئی اتفاقی امر نہ تھا بلکہ صنعت و تجارت کی ترقی کاتاریخی تقاضا تھا۔ اٹلی کے بینکروں، جہاز سازوں اور ریشمی، اُونی ملوں کے مالکوں کو تربیت یافتہ اور ہنر مند کارکنوں کی ضرورت پڑتی تھی مگر تعلیمی ادارے کلیسا کے ماتحت تھے جو فنی تعلیم کے سخت خلاف تھا لہذا سرمایہ دار طبقے کو مجبوراً سیکولر درس گاہیں قائم کرنی پڑیں۔ کلیسا نے اس اقدام کی شدت سے مخالفت کی مگر اس کی ایک نہ چلی اور دیکھتے ہی دیکھتے اٹلی کے قریب قریب ہر بڑے شہر میں سیکولر یونیورسٹیاں کھل گئیں۔ ” ان یونیورسٹیوں کو سیکولر اداروں نے سیکولر تعلیمات کی غرض سے قائم کیا تھا۔” 7 لہذا ان درس گاہوں کا ماحول قدرتی طورپر کلیسا کے خلاف تھا۔ بولو نیا یونیورسٹی میں تو دینیات کا شعبہ بھی نہ تھا۔ پیڈوایونیورسٹی فکرِ جدید کا سب سےبڑا مرکز تھی۔ فلورنس میں چھ ٹیکنیکل اسکول قائم تھے جن میں طلبا کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ تھی۔ سالر مو یونیورسٹی طبی تعلیم کے لیے پورے یورپ میں مشہور تھی۔ ان یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے نوجوانوں کی معاشرتی قدریں سیکولر ہوتی تھیں اور ان کا زاویہ نظر بھی کلیسا کے زاویہ نظر سے مختلف تھا۔
دوسرا اہم رحجان جس سے سیکولر عناصر کو تقویت ملی شرعی قوانین کی جگہ سول قوانین کی بڑھتی ہوئی مقبولیت تھی۔ اس رحجان کو بھی اٹلی کی جمہوری حکومتوں ہی نے سہارا دیا۔ چوں کہ کلیسا کے وضع کردہ فرسودہ قوانین نئی زندگی کے تقاضوں کو پورا نہین کر سکتے تھے لہذا تیرھویں صدی میں روم، ملان، ویرونا اور بولونیا ہر جگہ لا کالج قائم ہو گئے ۔ ان درس گاہوں میں قدیم رومن لا کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ تعلیم کلیسا کے حق میں بڑی مہلک ثابت ہوئی۔ اس کے سبب سے عدالتوں کا کردار بدل گیا اور پادری سینٹ برنارڈ کو فریاد کرنی پڑی کہ ” یورپ کی عدالتیں جسٹسن کے قوانین سے گونج رہی ہیں، خدائی قوانین کی آواز کہیں سنائی نہیں دیتی ۔ ” اور پروفیسر فشر کو جو کلیسا کا حامی ہے اعتراف کرنا پڑا کہ ” تیرھویں صدی میں سیاست اور معاشرے پر جتنے فکری اثرات پڑے ان میں رومن قانون کا اثر سب سے قوی تھا۔ سلطنت اور کلیسا کی کشمکش میں سول قانون کی تعلیم پانے والوں نے کلیسا کے بجائے سلطنت کاساتھ دیا۔”
اسی زمانے میں فرانس، بیلجیم اور برطانیہ میں بھی تجارت اور صنعت و حرفت کو فروغ ہوا۔ مارسلز، پیرس، ایمسٹرڈیم، ہمبرگ اور لندن میں صنعتی اور تجارتی اداروں کی تعداد بڑھنے لگی۔ سیکولر درس گاہیں قائم ہوئیں اور پرانی یونیورسٹیوں میں بھی جو کلیسا کے زیر اثر تھیں سیکولر خیالات کا چرچا شروع ہوگیا۔ برطانیہ میں آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیوں پر ہنوز کلیسا کا غلبہ تھا لہذا سول قانون کی تعلیم کے لیے لندن کے کاروباری حلقوں نے اپنے شہر میں جداگانہ لا کالج قائم کیے جو آج تک INN ” سرائے” کہلاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے بیرسٹر وہیں سے سند لیتے ہیں۔
زندگی کی اس طرزِ نو میں، جس کی داغ بیل سرمایہ داری نظام نے ڈالی فکرِ کہن کا پیوند نہیں لگ سکتا تھا ۔ مگر یورپ کا معاشرہ ہنوز فکرِنو کی تخلیق کا اہل نہ تھا۔ اس خلا کو اسپین اور سسلی کے عرب مفکرین نے پر کیا ۔ یورپ میں ذہنی انقلاب لانے کا سہرا انہیں کے سر ہے۔ چنانچہ پروفیسر فشر کے سے متعصب مورخ کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ ” تیرھویں صدی میں روشنی کی جو کرنیں یورپ میں پہنچیں وہ یونان سے نہیں بلکہ اسپین کے عربوں کے ذریعے آئیں” اور پروفیسر فلپ حتی لکھتا ہے کہ:
” یورپ کے قرونِ وسطیٰ کی فکری تاریخ میں مسلم اسپین نے انتہائی درخشاں ابواب تحریر کیے۔ آٹھویں اور تیرھویں صدی کے دوران عربی بولنے والے ساری دنیا میں تہذیب و تمدن کے مشعل بردار تھے۔ مزید برآں انہیں کی کوششوں سے قدیم سائنس اور فلسفے کی بازیابی ہوئی۔ انہوں نے اس علم میں اضافہ کیا اور اس کو دوسروں تک اس طرح پہنچایا کہ مغرب نشاۃِ ثانیہ سے آشنا ہوا۔ ان کاموں میں ہسپانوی عربوں کا بڑا حصہ ہے۔انہوں نے یونانی فلسفے کو مغرب میں منتقل کیا۔ مغربی یورپ میں نئے خیالات کا یہ بہاؤ بالخصوص فلسفیانہ خیالات کا یہ زبردست بہاؤ عہدِ تاریک کے اختتام کی ابتدا کا موجب بنا” 8
حقیقت یہ ہے کہ علم و حکمت کا کارواں بڑی پر پیچ راہوں سے گزرا ہے۔ یونانی فکرو فن کا اثاثہ پہلے بطلیموس فرماں رواؤں کے عہد میں (تیسری صدی قبلِ مسیح) اسکندریہ منتقل ہوا۔ اس خزانے سے شام و عراق کے یہودی اور عیسائی علما نے فیض پایا۔ تب عباسیوں کے زمانے میں یونانی تصنیفات اور خلاصوں کے ترجمے عربی میں ہوئے۔ ان ترجموں سے مسلمان حکما اور اطبا نے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ عباسیوں کے زوال کے بعد علم و حکمت کا یہ سرمایہ ہسپانوی عربوں کو ورثے میں ملا۔ انہوں نے اس دولت کو محفوظ رکھنے پر اکتفا نہ کی بلکہ اپنی تحقیقی اور تخلیقی کاوشوں سے اس میں بیش بہا اضافے کیے۔ وہ خزانے کے سانپ بھی نہ بنے بلکہ انہوں نے اہلِ مغرب کو اس دولت سے مستفید ہونے کے مواقعے فراہم کیے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے مغرب کی درس گاہیں عربی تصنیفات کے لاطینی ترجموں کی روشنی سے منور ہوگئیں۔ سچ یہ ہے کہ یورپ میں سیکولر خیالات کو فروغ دینے میں عرب مفکرین نے بڑا تاریخی کردار ادا کیا ہے۔
جس طرح نویں صدی عیسوی یونانی، سریانی اور سنسکرت تصنیفات کے عربی ترجموں کی صدی تھی اسی طرح بارھویں اور تیرھویں صدی (1125ء۔1280ء) کو عربی سے لاطینی میں ترجمے کا زمانہ کہتے ہیں۔ اسپین میں ان دنوں یوں تو بے شمار اہل قلم موجود تھے جو عربی ، لاطینی اور فرانسیسی زبانوں پر پورا عبور رکھتے تھے لیکن ترجمہ کرنے والوں میں سر فہرست نام اطالوی عالم جرارڈ آف کری مونا (1114ء۔ 1178ء) کا ہے۔ علم کی پیاس اس کو طولید ولائی اور پھر وہ ہیں کا ہو رہا۔ جرارڈ نے اسّی کتابیں عربی سے لاطینی میں منتقل کیں۔ ان میں بطلیموس کی المجیط، خوارزمی کی حساب الجبرو المقابلہ ، بوعلی سینا کی قانون الطب (جو مغربی یونیورسٹیوں میں صدیوں تک داخل نصاب رہی) حکیم ابوبکر رازی کی کتابِ سرالاسرار (جو ڈھائی سو سال تک کیمسٹری کی سب سے مستند کتاب سمجھی جاتی رہی) اور جابرابنِ افلاح کی کتاب الحیات قابلِ ذکر ہیں۔
ان کے علاوہ الجاخط کی کتاب الحیوان ، ابوبکررازی کی کتاب الطب المنصوری (جو دس جلدون میں تھی) خوارزمی اور البطانی کی کتاب زج، ابن بیطار اورابن ماجہ کی تصنیفات اور الحادی کی کتاب جو یونانی ، ایرانی اور ہندی طب کی قاموس تھی لاطینی زبان میں ترجمہ ہوئیں۔ بعض عرب حکما براہِ راست لاطینی زبان میں لکھتے تھے مثلاً ابو جعفر احمد بن محمد غفیقی جو قرطبہ کا مشہور طبیب تھا۔ اس نے الادویہ مفردہ، عربی، بربر اور لاطینی تینوں زبانوں میں لکھی۔ اس کتاب کے سلسلے میں غفیقی نے اسپین اور افریقہ کے دورے کیے اور آٹھ سو سے زیادہ مفردات کے نام اور ان کے خواص اکٹھا کیے۔ یہ سب حکما جن کا ہم نے ذکر کیا ہے پیشے کے اعتبار سے طبیب تھے یعنی اپنی عہد کے سائنس داں جبھی تو پروفیسر لانگے مشہور جرمن مفکر ہمبولٹ کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ “عربوں کو طبیعاتی سائنسوں کا حقیقی بانی سمجھنا چاہیے۔”
قرونِ وسطیٰ کے جن مسلمان حکما نے مغربی فکر کو سب سے زیادہ متاثر کیا ان میں ابو بکر رازی (وفات 925ء) اور ابنِ رشد (1126ء۔1198ء) کے نام سر فہرست ہیں۔ رازی رے (تہران ) کا رہنے والا تھا مگر بغداد منتقل ہو گیا تھا۔ وہ نہایت آزاد خیال اور روشن فکر سائنس دان تھا۔ البیرونی اس کی 56 تصنیفات کا ذکر کرتا ہے لیکن اس کی کتابوں کی تعداد سو سے بھی زیادہ ہے (33 نیچرل سائنس پر، 22 کیمسٹری پر، 17 فلسفے پر، 14 مذہبیات پر، 10 ریاضی پر، 8 منطق پر، 6 مابعد الطبیعات پر اور 10 متفرقات ) رازی کی تصنیفات پہلے جرارڈ نے لاطینی میں ترجمہ کیں پھر بادشاہ چارلس آف انجو کے حکم سے تیرھویں صدی میں ترجمہ ہوئیں۔ یورپ میں اس کا نام Rhaze تھا۔ وہ اکثریتِ مطالعہ کی وجہ سے آخری عمر میں اندھا ہوگیا تھا۔
رازی اسلاف پرستی کے سخت خلاف ہے۔ وہ منقولات کی حاکمیت کو نہیں تسلیم کرتا بلکہ عقل اور تجربے کو علم کا واحد ذریعہ سمجھتا ہے۔ اس کی سوچ کا انداز عوامی تھا۔ وہ کہتا تھا کہ عام لوگ بھی اپنے مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سائنسی سچائیوں کے ادراک کے اہل ہیں۔ اس کا قول تھا کہ ہم کوفلسفے اور مذہب دونوں پر تنقید کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ وہ معجزوں کا منکر تھا کیوں کہ معجزے قانونِ قدرت کی نفی کرتے ہیں اور خلافِ عقل ہیں۔ وہ مذاہب کی صداقت کا بھی چنداں قائل نہیں کیوں کہ مذاہب عموماً حقیقتوں کو چھپاتے ہیں اور لوگوں میں نفرت اور عداوت پیدا کرتے ہیں۔ وہ معاشرے کے بارے میں افلاطون کی کتاب تماؤس کے ارتقائی تصور سے اتفاق کرتا ہے اور اقتصادی پہلو کو اہمیت دیتے ہوئے تقسیمِ کار کی افادیت پر زور دیتا ہے۔
رازی ارسطو کا پیرو نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو ارسطو سے بڑا مفکر سمجھتا ہے۔ وہ ارسطو کی ” طبیعات” کو رد کرتا ہے اور دیمقراطیس اور ایپی قورس کے ایٹمی فلسفے کے حق میں دلیلیں دیتا ہے۔ اس کے خیال میں تمام اجسام مادی ایٹموں پر مشتمل ہیں اور خلا میں حرکت کرتے رہتے ہیں۔ ارسطو کے برعکس وہ خلا کے وجود بالذات کو تسلیم کرتا ہے۔ اس کی رائے میں پانچ قوتیں ابدی اور لافانی ہیں، خدا، روح، مادہ، زبان و مکان۔ وہ کہتا تھا کہ سائنس میں حرف آخر کوئی نہیں بلکہ علوم نسلاً بعد نسل ترقی کرتے رہتے ہیں لہذا انسان کو لازم ہے کہ اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھلی رکھے اور منقولات کے بجائے حقیقی واقعات پر بھروسہ کرے۔9
طبیبِ توابنِ رشد بھی تھا لیکن یورپ میں اس کی شہرت کی وجہ فلسفہ تھا بالخصوص ارسطو کی شرحیں۔ ” ابن رشدیت بارھویں صدی سے سولھویں صدی تک یورپ میں سب سے غالب مدرسہ فکر تھا حالاں کہ عیسائی پادری اس کے سخت خلاف تھے۔ ” ابنِ رشد کی تعلیمات کا لب لباب یہ تھا کہ (1) کائنات اور مادہ ابدی اور لافانی ہے (2) خدا دنیاوی امور میں مداخلت نہیں کرتا (3) عقل لافانی ہے اور علم کا ذریعہ ہے۔
ارسطو کی تصانیف بالخصوص ” طبیعات” اور ” مابعد الطبیعیات” پر ابنِ رشد کی شرحیں پیرس پہنچیں تو کلیسائی عقاید کے ایوان میں ہلچل ملچل مچ گئی۔ معلم اور منعلم دونوں مسیحی عقیدۂ تخلیق، معجزات اور روح کی لافانیت پر علانیہ اعتراض کرنے لگے۔ حالات اتنے تشویشناک ہو گئے کہ 1210ء میں پیرس کی مجلسِ کلیسا نے ارسطو کی تعلیمات بالخصوص ابنِ رشد کی شرحوں کی اشاعت ممنوع قرار دے دی مگر کسی نے پرواہ کی لہذا 1215ء میں پوپ نے پوری عیسائی دنیا میں ان کتابوں پر پابندی لگا دی۔ پابندیوں کی وجہ سے ابنِ رشد کی مقبولیت اور بڑھ گئی۔ پوپ اسکندر چہارم نے رشدیت کےابطال کے لیے پادری البرٹس مغنوس سے ایک کتاب لکھوائی مگر وہ بھی قریب قریب ہر صفحے پر بو علی سینا کا اقتباس پیش کرتا ہے اور مسلمان مفکرین کے حوالے دیتا ہے۔ 1269ء میں ابنِ رشد سے منسوب تیرہ مقولوں کی تعلیم مذہب کے خلاف قرار پائی ان میں سے بعض یہ ہیں: سب انسانوں کے دماغ کی ساخت یکساں ہے، دینا لافانی ہے، آدم کی تخلیق افسانہ ہے، انسان اپنی مرضی میں آزاد ہے اور اپنی ضرورتوں سے مجبور، خدا کو روزمرہ کے واقعات کا علم نہیں ہوتا اور انسان کے اعمال میں خدا کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ مگر ابنِ رشد کی مقبولیت کم نہ ہوئی۔ تب 1277ء میں ابنِ رشد کے 219 مقولوں کے خلاف فتویٰ صادر ہوا مثلاً تخلیق محال ہے، مردے کا جسم دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، قیامت کا اعتقاد فلسفیوں کو زیب نہیں دیتا، فقہائے مذہب کی باتیں قصے کہانیاں ہیں، دینیات سے ہمارے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ دینِ مسیحی حصول علم میں حارج ہے۔ مسرت اسی دینا میں حاصل ہو سکتی ہے نہ کہ آخرت میں۔
فرانس میں رُشدیت کا سب سے بڑا علم بردار پیرس یونیورسٹی کا پروفیسر سیگر (1235ء۔1271ء) تھا۔ اس پر 1277ء میں مذہبی عدالت میں مقدمہ چلا اور عمر قید کی سزا ملی۔ اسیری کے دن اس نے روم میں گزارے اوروہیں قتل ہوا۔ ان سختیوں کے باوجود ابنِ رشد کے خیالات ذہنوں کو متاثر کرتے رہے یہاں تک کہ ول ڈیورنت کے بقول ” تیرھویں صدی کے وسط میں ابن رشدیت تعلیم یافتہ طبقے کا فیشن بن گئی 10 اور ہزاروں افراد ابن رشد کے اس خیال سے اتفاق کرنے لگے کہ قوانینِ قدرت کے عمل میں خدا بالکل مداخلت نہیں کرتا، کائنات لافانی ہے اور جنت دوزخ عوام کو بہلانے کے بہانے ہیں۔
معتزلہ کے زیر اثر فرانس میں، ایسے مفکر بھی پیدا ہونے لگے جو کہتے تھے کہ خدا نے کائنات کی تخلیق کے بعد نظامِ کائنات کو قوانینِ قدرت کے سپرد کردیا ہے لہذا معجزہ محال ہے کیوں کہ معجزوں سے قوانیںِ قدرت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ دعاؤں، تعویذوں سے عناصر قدرت کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ التجاؤں سے نہ طوفان کو روکا جا سکتا ہے نہ بارش لائی جا سکتی ہے اور نہ بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بناتات اور حیوانات کی نئی قسمیں عملِ تخلیق کا کرشمہ نہیں بلکہ قدرتی ارتقا کا نتیجہ ہیں اور یہ عقیدہ کہ قیامت کے دن مردے جی اٹھیں گے درست نہیں کوں کہ روح اور جسم دونوں فانی ہیں۔ اس کےسا تھ قدیم یونانی فلسفی ایپی قورس (341۔270 ق۔ م ) اور اس کے روحانی شاگرد لوکری شیش (99۔ 55 ق۔م)کا ایٹمی فلسفہ مقبول ہونے لگا اور یہ خیال عام ہوا کہ حقیقی دنیا یہی ہے۔ آخرت محض افسانہ ہے۔
یورپ میں سائنسی تجربوں کا دور عربی تصانیف کے لاطینی ترجموں کے بعد شروع ہوا۔ اس دور کے سائنس دانوں میں سب سے ممتاز روجر بیکن (1214ء۔ 1294ء) ہے تحصیلِ علم کے شوق میں وہ آکسفورڈ سے فرانس ، اٹلی اور غالباً اسپین بھی گیا۔ وہیں وہ مسلمان سائنس دانوں کے خیالات سےس واقف ہوا۔ وہ اسلامی سائنس اور فلسفے کے احسانات کا اعتراف اپنی کتابوں میں بار بار کرتا ہے۔ روجر بیکن کے نزدیک علم و آگہی کا واحد ذریعہ تجربہ ہے۔ ” جو شخص مظاہر قدرت کی سچائیوں تک بلا شک و شبہ پہنچنا چاہتا ہو اس کو لازم ہے کہ تجربوں پر وقت صرف کرے کیوں کہ نیچری سائنس میں تجربہ ہی واحد ثبوت فراہم کرتا ہے”۔آکسفورڈ واپس جا کر اس انے ابنِ ہیثم کی بصریات پر تجربے شروع کیے تو کلیسا کی طرف سے اس کی باقاعدہ نگرانی ہونے لگی اور پادری یوناون ترا(1221ء۔1274ء) نے دھمکی دی کہ ” علم و حکمت کا درخت بہتوں کو شجرِ حیات سے گمراہ کردیتا ہے اور جہنم کے ہولناک عذابوں کی تمہید ہوتا ہے۔” اس جرم کی پاداش میں کہ “تمھاری تحریروں میں عجیب و غریب خیالات کا اظہار ہوتا ہے” روجر بیکن کو مذہبی عدالت کے حکم سے قید کردیا گیا اور وہ پندرہ سال بعد رہا ہوا ۔
چودھویں صدی میں قومی ریاستوں کے قائم ہونے سے سیکولر خیالات خوب پھلے پھولے۔ قومی ریاستوں کو کلیسا کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے جن دلیلوں کی ضرورت تھی وہ سیکولر مفکر ہی فراہم کر سکتے تھے۔ مثلاً پیڈو وا یونیورسٹی کے استاد مارسی لیو نے اٹلی کی شہری ریاستوں کو نمونہ بنا کر 1334ء میں سیکو لر ریاستوں کا ایک مبسوط نظریہ پیش کیا۔ اس نے شرعی قوانین اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کا موازنہ کرتے ہوئے لکھا کہ ” شہریوں کے حقوق ان کے عقاید سے متعین نہیں ہوتے لہذا کسی شخص کو اس کےمذہب کی بنا پر سزا نہیں ملنی چاہیے۔ ” کلیسا کی قائم کردہ مذہبی عدالتوں پر یہ کھلا حملہ تھا۔
کلیسا کا زوال اب دورنہیں تھا۔ چنانچہ جلد ہی ایسی تحریکیں اٹھیں اور پے درپے ایسے اہم واقعات پیش آئے جو سیکولر خیالات کے حق میں بے حد سازگار ثابت ہوئے: یورپ میں نشاۃ ثانیہ کا ظہور، مارٹن لوتھر، کالون اور زونیگلی وغیرہ کی پوپ کے خلاف بغاوتیں، برطانیہ میں ہنری ہشتم کا رومن کلیسا سے تصادم، سائنسی ایجادوں میں اضافہ، صنعت حرفت کا بڑے پیمانے پر فروغ ، امریکہ اورہندوستان کی دریافت اور اس کی وجہ سے بین الاقوامی تجارت و صنعت میں اضافہ، برطانیہ میں خانہ جنگی اور جمہوریت پسندوں کے ہاتھوں بادشاہ چارلس اول کا قتل، اُلوہی استحقاقِ ملوکیت کے نظریے سے عام بیزاری اور پارلیمانی نظام سے وابستگی غرضیکہ معاشرتی اور سیاسی شعبوں میں سیکولر میلان عام ہوگیا۔ سترھویں صدی میں جو عقلیت کا عہد کہلاتا ہے سیکولر رحجانات کو مزید تقویت ملی۔ اسی بنا پر پروفیسر آرنلڈ ٹوائن بی نے لکھا ہے کہ ” سترھویں صدی مغربی زندگی پر سیکولر ازم کی بالادستی کی صدی ہے۔ سیکولر ازم ہی کے طفیل مغربی معاشرے میں معاشی مفاد نے اور تحقیق و تفتیش کے دائرے میں سائنس نے مذہب کی جگہ لے لی۔”11
اٹھارویں صدی یورپ میں صنعتی انقلاب ، سیاسی انقلاب اور روشن خیالی کے عروج کی صدی تھی۔ والتیر، روسو، مان تس کیو، اولباخ، ایلواتیس، دیدرو، کانٹ بے شمار ایسے مفکر پیدا ہوئے جنھوں نے معاشرتی اقدارو افکار کا رخ ہی بدل دیا اور جب عوام کی انقلابی جدو جہد (امریکہ اور فرانس میں ) شروع ہوئی تو سیکولر خیالات نے عملی پیراہن پہن لیا۔
امریکی جنگِ آزادی کی قیادت وہاں کے صنعت کارون اور تاجروں نے کی تھی۔ ان طبقوں پر اور ان کے فکری نمائندوں پر جیمس میڈیسن، تھامس جیفر سن، ٹام پین اور بنجامن فرینکلین کے علاوہ برطانوی سیاسی مفکر جان لاک اور فرانسیسی خرد افروزوں کا گہرا اثر تھا۔ انہوں نے امریکی ری پبلک کی بنیاد سیکولر اصولوں پر رکھی۔ چنانچہ امریکہ کا نیا آئین جو 1789ء میں منظور ہوا خالص سیکولر آئین تھا۔ یہ آئین ہنوز رائج ہے۔ اس کے مطابق اقتدارِ اعلیٰ کا سرچشمہ ملک کے باشندے ہیں۔ آئین کی دفعہ چھ کے مطابق ریاست کے کسی عہدے کے لیے مذہب کی کوئی شرط نہیں۔ آئین کی سیکولر نوعیت کی مزید تشریح کی غرض سے صدر میڈیسن کی تحریک پر کانگریس نے 1793ء میں آئین میں پہلی ترمیم منظور کی جس میں طے پایا کہ ” کانگریس مذہب کے قیام یا مذہب کی آزادی پر پابندی کے سلسلے میں کوئی قانون پاس نہیں کرے گی۔” صدر جیفرسن نے اس ترمیم کی وضاحتت کرتے ہوئے کہا کہ ” امریکی قوم کے اس فیصلے کو میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جس میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ مقنّنہ مذہب کے قیام یا مذہبی رسوم کی ادائیگی کی ممانعت کے بارے میں کوئی قانون وضع نہیں کرے گی۔ اس طرح انہوں نے ریاست اور کلیسا کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔”
تاریخی اعتبار سے امریکہ عہدِ جدید کی پہلی سیکولر ریاست ہے مگر جس سماجی انقلاب کی وجہ سے سیکولر اداروں اور فکروں کے اثرات یورپ اور ایشیا میں نمایاں ہوئے وہ فرانس کا عظیم انقلاب تھا۔ اس کے باعث یورپ میں ملوکیت ، فیوڈل ازم اور کلیسا کی بالا دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور دنیا سرمایہ داری نظام کے عہد میں داخل ہو گئی۔
سرمایہ داری نظام ہر اعتبار سے جاگیری نظام کی ضد ہوتا ہے۔ یہ تضاد یورپ میں اس وقت کھل کر سامنے آیا جب بین الاقوامی تجارت کے بحری راستے دریافت ہوئے۔ جاگیری دور میں آلاتِ پیداوار، ہل بیل، ہنسیا، ہتھوڑا، چرخہ کھڈی، سبھی ذرائع پیداوار (زمین) کی مانند افراد کی ذاتی ملکیت ہوتے ہیں لہذا زرعی او ر صنعتی پیداوار بہت محدود ہوتی ہے۔ چنانچہ انگریز، ولندیزی اور پرتگالی بیوپاریوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ پیداوار کس طرح بڑھائی جائے۔ ان کو ہندوستان ، لنکا، جاوا اور ملایا وغیر ہ میں مصالحہ جات و مصنوعات سونے چاندی کے عوض نقد خریدنی پڑتی تھی۔ کیوں کہ مغربی مصنوعات کی مقدار بہت کم تھی اور کوالٹی کے لحاظ سے بھی وہ مشرقی بازاروں میں فروخت کے قابل نہیں ہوتی تھی۔ وہاں تو فیکٹریوں اور کارخانوں کے مزدور بھی نہیں ملتے تھے کیوں کہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ فیوڈل نوابوں کی زمینوں سے بندھے تھے۔ ان شہروں میں جا کر کام کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اس کے علاوہ جاگیرداروں اور نوابوں نے تجارتی مال کی نقل و حرکت پر طرح طرح کی پابندیاں لگا رکھی تھیں جن کی موجودگی میں تجارت ترقی کر ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ تھے وہ اقتصای تضادات جو جاگیری نظام کو نیست و نابود کیے بغیر حل نہیں ہو سکتے تھے۔
مگر جاگیریت فقط پسماندہ طریقہ پیداوار ہی کی علامت نہیں ہوتی بلکہ ایک فرسودہ ضابطہ حیات کی نشان دہی بھی کرتی ہے۔ لوگوں کا رہن سہن ، سوچنے اور محسوس کرنے کا انداز، ان کی سماجی اور اخلاقی قدریں، رسم و رواج اور تعصبات و میلانات سب جاگیری ضابطوں کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ان ضابطوں کی گرفت معاشرے پر اتنی سخت ہوتی ہے کہ ان کو توڑے بغیر جاگیری دور کے طریقہ پیداوار کو بدلا نہیں جا سکتا ۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب کے سرمایہ دار طبقوں کو مطلق العنان ملوکیت کے علاوہ، جو جاگیری نظام کا مرکز تھی جاگیری عہد کے ضابطہ حیات سے بھی لڑنا پڑا۔ سیکولر ازم یعنی جمہوریت اور مساوات، آئینی اور نمائندہ حکومت، فکر و ضمیر کی آزادی، سائنسی سوچ اور شہری حقوق کی جد و جہد جاگیریت اور سرمایہ داری کے درمیان نظریاتی جنگ ہی کی مختلف شکلیں تھیں۔ اس جنگ میں ملوکیت کے علم برداروں کی طرح کلیسا نے بھی ظلم و استبداد کا ساتھ دیا اور ہر روشن خیال، خرد افروز اور ترقی پسند تحریک کی شدت سے مخالفت کی مگر تاریخ کے دھارے کو نہ ملوکیت روک سکی نہ کلیسائیت۔ فرانس میں زبردست انقلاب آیا جس نے ملوکیت ، نوابیت اور کلیسا یعنی جاگیری نظام کے تینوں ستون گرادیے۔ اس کے بعد یورپ کے قریب قریب ہر ملک میں معاشرے اور ریاست کی تشکیل سیکولر خطوط پر ہونے لگی لیکن سیکولرازم کو پوری طرح رواج پانے میں ایک صدی لگی اور مغربی قوموں نے بڑی جد وجہد کے بعد پہلی بار وہ حقوق حاصل کیے جو سیکولرازم کی جان ہیں۔ مثلاً تحریرو تقریر کی آزادی، ضمیر و فکر کی آزادی، پریس کی آزادی، تنظیمیں بنانے کی آزادی اور اختلافِ رائے کی آزادی ورنہ جاگیری دور میں تو کسی نے ان حقوق کا نام بھی نہ سنا تھا۔
یورپ اور امریکہ میں سیکولر ریاستوں کے قیام سے لوگ لامذہب نہیں ہو گئے۔ نہ گرجا گھر ٹوٹے اور نہ پادریوں کی تبلیغی سرگرمیوں میں چنداں فرق آیا البتہ ہر شخص کو پہلی بار اس بات کا موقع ملا کہ دو دوسرے مسائل کی مانند مذہبی مسائل پر بھی بلا خوف و خطر غور کرے اور جو عقاید و رسوم خلافِ عقل نظر آئیں ان کو رد کردے۔ سیکولر ازم کے رواج پانے سے کلیسا کی قائم کی ہوئی خوف و دہشت کی فضا بھی ختم ہو گئی۔ کلیسائی دور میں لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی بھیانک قسم کی جسمانی ایذائیں دی جاتی تھیں اور ان کو توبہ کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ سیکولرازم کے دور میں یہ وحشانہ مظالم بند کر دیے گئے اور پادری حضرات کو بھی اپنا طرزِ عمل بدلنا پڑا۔ اب وہ لوگوں سے اخلاق و محبت سے پیش آنے پر مجبور ہوئے اور ڈارانے دھمکانے کے بجائے ان کو عقلی دلیلوں سے اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کرنے لگے۔
(2)
مشرقی ملکوں میں سیکولر خیالات کے نشو ونما اٹھارویں صدی میں ہوئی۔ روشن خیالی کی یہ لہر ترکی اور ایران میں براہِ راست مغربی روابط سے آئی۔ مصر میں نپولین کے حملے کے دوران اور ہندوستان میں بنگال، بہار اور آگرہ دہلی پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلط کے بعد۔ اس مضمون میں ہم فقط ترکی اور برصغیر کی سیکولر تحریکوں سے بحث کریں گے۔
سلطان سلیمان اعظم (1520ء۔1560ء) کا عہد سلطنتِ عثمانیہ کا نقطہ عروج تھا۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا فرماں روا تھا جو ہنگری سے یمن اور بغداد سے مراکش تک پھیلی ہوئی تھی، اس کی رعایا میں مختلف قوموں اور مذاہب کے لوگ شامل تھے۔ ترک، عرب، کرد، سلاف، میجیار، بربر، یہودی، عیسائی اور مسلمان۔ عروج کا یہ دور تقریباً دو سو سال تک جاری رہا۔ 1683ء میں وینا (آسٹریا) پر ترکوں کے دوسرے حملے کی ناکامی زوالِ سلطنت کی تمہید ثابت ہوئی۔ پہلے ہنگری ہاتھ سے نکلا (1699ء) پھر کریمیا اور گرجستان، اس کے بعد بلغاریہ، یوگو سلاویہ، یونان، البانیہ، قبرص، الجزائر، لیبیا، کریٹ اور مصر۔ پہلی جنگِ عظیم کے بعد مغرب کی سامراجی طاقتوں نے عراق، عرب ، شام اور فلسطین پر بھی قبضہ کرلیا۔ اب ترکی کے پاس اناطولیہ کے علاوہ سالونیکا کا تھوڑا سا ساحلی علاقہ پرانی تسخیرات کی واحد نشانی رہ گیا ہے۔
عثمانی سلطنت میں اقتدارِ اعلیٰ کی مالک سلطان کی ذات تھی۔ وہ تمام اختیارات کا سر چشمہ ہوتا تھا۔ اس کا ” ارادہ” شریعت کے تابع نہ تھا مگر شریعت سے متصادم بھی نہ تھا۔ اس کو ” تقدیر و تعزیر” کا پورا استحقاق حاصل تھا۔ ارکانِ سلطنت تین طبقوں پر مشتمل تھے۔ 1۔ اصحابِ قلم جن کے تین مدارج تھے۔ اول رجال جن سے وزرا اور اعیانِ سلطنت مراد تھے۔دوئم خوجہ جو سرکاری دفتروں میں کام کرتے تھے۔ سوئم آغا یعنی شاہی محلات کے ملازم و محافظ۔ 2۔ اصحابِ سیف یعنی صوبوں کے فوجی گورنر اور “سپاہی” جن کو افواج شاہی کے لیے لشکری فراہم کرنے کے عوض جاگیریں (تیمار ) دی جاتی تھیں اور ” جاں نثار” یہ وہ شاہی فوج تھی جس میں اقلیتی علاقوں کے عیسائی لڑکے کمسنی میں بھرتی کیے جاتے تھے۔ ان کو مسلمان بنایا جاتا تھا۔ ان کو شادی کرنے کی اجازت نہ تھی اور نہ ان کا اپنا گھر بار ہوتا تھا۔ 3۔ اصحابِ مذہب، کلیسائی نظام دنیائے اسلام میں اگر کہیں تھا تو وہ ترکی تھا جہاں شیخ الاسلام کو صدر اعظم کے مساوی اختیارات حاصل تھے۔ وہ سلطنت کا سب سے بڑا قاضی اور مفتی ہوتا تھا۔ قاضی العسکر رومالیہ، قاضی العسکر اناطولیہ، قاضیِ استنبول، ملاء مکہ و مدینہ اور ملاء بروسا، ایدریانوپل، قاہرہ دمشق سب اس کے ماتحت ہوتے تھے۔ سلطنت کی تمام مساجد او ر اوقاف تمام عدالتیں اور درس گاہیں شیخ الاسلام کے تابع تھیں مگر وہ بیک وقت وزیرِ تعلیم، وزیرِ قانون اوروزیرِ مذہبی تھا۔ اور عدالتِ عدلیہ کا چیف جسٹس بھی ۔ ” اصناف ” اور “رعایا” دو طبقے اور بھی تھے مگر ان کو امورِ سلطنت میں کوئی حق و اختیار نہ تھا۔ اصناف سے مراد تجارت پیشہ لوگ، دکاندار، دست کار اور اہلِ حرفہ تھے اور رعایا سے مراد کاشت کار۔ ارکانِ سلطنت کا فرض سلطنت یعنی سلطان کی طاقت کو مستحکم اور محفوظ کرنا تھا نہ کہ رعایا کی فلاح و بہبود کی تدبیریں اختیار کرنا۔
سلطنت کی اس طرزِ تعمیر ہی میں اس کی خرابی کی صورت مضمر تھی۔ سترھویں صدی میں جب یورپ میں جدید صنعت و تجارت نے بڑے پیمانے پر ترقی کی اور فیوڈل نظامِ فکر و عمل کی جگہ نیشنلسٹ جمہوری اور سیکولر اداروں نے قوت پکڑی تو عثمانی سلطنت جس کی بنیاد فیوڈل ازم اور عسکری طاقت پر قائم تھی یورپ کی ابھرتی ہوئی سرمایہ دار طاقتوں کا مقابلہ نہ کرسکی۔ نہ معاشرتی طورپر نہ فکری طورپر۔ خالدہ ادیب خانم ترکی کی ذہنی پسماندگی اور قدامت پرستی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ:
جس وقت مغرب نے روایت پرستی کی زنجیروں کو توڑنے اورنئے علم اور سائنس کی طرح ڈالی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ دنیا کی شکل بدل گئی مگر اسلام کا مذہبی جسد اپنے تعلیمی فرائض کی ادائیگی میں سراسر ناکام رہا۔ علما اس خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ انسانی علم و حکمت تیرھویں صدی سے آگے نہیں بڑھی ہے۔ ان کا یہ اندازِ فکر انیسویں صدی تک بدستور قائم رہا۔ عثمانی علما نے ترکی میں نئی فکر کو ابھرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ جب تک مسلم قوم کی تعلیم کے نگراں رہے انہوں نے اس کا پورا پورا بندوبست کیا کہ تعلیم کے نصاب میں کوئی نئی فکر داخل نہ ہونے پائے لہذا علم پر جمود طاری ہو گیا۔ مزید برآں یہ حضرات ملکی سیاست میں اس درجہ الجھے ہوئے تھے کہ ان کو اصلاحات پر غور کرنے کا وقت ہی نہ ملا۔ مدرسے وہیں رہے جہاں وہ تیرھویں صدی میں تھے۔12
اٹھارویں صدی کی ابتدا میں مغربی طاقتوں کے ہاتھوں پے درپے شکست کے بعد جب ترکی یورپی اقوام کو تجارتی، قانونی اور مذہبی مراعات دینے پر مجبور ہوا، ترکی میں ا ن کے دفاتر اور تجارتی مرکرز قائم ہوے، مغربی حکومتوں سے ترکی کی روہ رسم بڑی تو اس بدی سے نیکی کی صورتیں بھی پیدا ہونے لگیں۔ مغربی سیاست کو سمجھنے کے لیے مغربی زبانوں بالخصوص فرانسیسی زبان اور تہذیب سے واقفیت ضروری ہو گئی۔ اس طرح اصحابِ سیف اور اصحابِ مذہب کے مقابل ” اصحابِ قلم” کا ایک نیا گروہ آہستہ آہستہ پیدا ہوا جو مغربی افکار و علوم سے قدرے آگاہ تھا اور مغربی تمدن کو قبول کرنے ہی میں ترکی کی نجات دیکھتا تھا۔ یہ گروہ صدقِ دل سے محسوس کرتا تھا کہ مشرقی اور اسلامی ورثہ نئے حالات اور نئے خطرات کا مقابلہ کرنے میں عثمانیوں کی مدد نہیں کرسکتا لہذا ہم کو مغربی تمدن و تہذیب اختیار کرلینا چاہیے۔ یہ رحجان سلطان احمد (1707ء۔ 1730ء) کے دور میں جس کو ” عہد لالہ” کہتے ہیں سلطان کے داماد اور صدرِ اعظم ابراہیم پاشا کی کوششوں سے ابھرا۔ اس نے 1717ء میں سائنسی کتابوں بالخصوص جغرافیہ، طب اور طبیعات کی کتابوں کا ترکی میں ترجمہ کرنے کی غرض سے 25 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی مقرر کی۔ 1720ء میں سلطان نے محمد فیضی چیلپی کو پیرس سفیر بنا کر بھیجا اور ہدایت کی کہ فرانس کے قلعوں اور فیکٹریوں کا معائنہ کرے، وہاں کے تہذیبی اداروں کی سرگرمیوں کو غور سے دیکھے اور جو جو چیزیں ترکی میں رائج کی جا سکتی ہوں ان کے بارے میں اپنی رپورٹ پیش کرے۔ چیلپی نے واپس آکر ایک کتاب بھی لکھی جس میں وہ فرانس کے ٹیکنیکل فنون، فوجی اداروں اور ہسپتالوں ،ا سکولوں کی تعریف کرتا ہے اور عورتوں کی آزادی کو خوب سراہتا ہے۔
چیلپی کا بیٹا سعید محمد پہلا ترک ہے جس نے فرانسیسی زبان سیکھی۔ وہ فرانس کی آزادی فکر کا بڑا مداح تھا ۔ پیرس سے دوسری بار واپس آنے پر اس نے ہنگری کے ایک نو مسلم ابراہیم متفرقہ (1670ء۔ 1754ء) کے ساتھ مل کر 1727ء میں پہلا ترکی چھاپہ خانہ قائم کیا (ترکی میں پریس کا رواج 1587ء میں شروع ہو گیا تھا لیکن شیخ الاسلام کے فتوے کے مطابق صرف عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنی مذہبی کتابیں چھاپنے کی اجازت تھی) ابراہیم متفرقہ بڑا روشن خیال شخص تھا۔ وہ فرانسیسی، اطالوی، جرمن، لاطینی اور ترکی زبانیں جانتا تھا۔ نیازی برکس کے بقول ” ابراہیم وہ شخص ہے جس نے ترکی کو جدید سائنسی فکر سے روشناس کیا اور تبدیلی اور ترقی کی راہ دکھائی” 13 اس نے 1726ء میں ایک دستاویز ” وسیلتہ الطباعت” لکھی اور صدرِ اعظم داماد کو پیش کی۔ دوسرے سال اس کو پریس لگانے کی اجازت مل گئی لیکن کاتبوں نے سخت شور مچایا کہ اسلام خطرے میں ہے حالاں کہ اسلام نہیں بلکہ ان کی روزی خطرے میں تھی۔ کاتبوں کے احتجاج پر شیخ الاسلام نے فتویٰ صادر کیا کہ قرآن، حدیث، تفسیر اور فقہ کی کتابیں مطبع میں نہیں چھپ سکتیں۔ پہلی کتاب جو دنیائے اسلام کی پہلی مطبوعہ کتاب تھی 31 جنوری 1769ء کو چھپ کر شائع ہوئی۔ ابراہیم متفرقہ نے مغرب کی ترقی اور ترکی کی پسماندگی کے اسباب پر بھی ایک کتاب ” اصول الحکم فی نظام الااُمم” لکھی اور سلطان کو بھی پیش کی۔ اس کتاب میں وہ جمہوریت کے حق میں فیصلہ دیتا ہے ۔ اس کتاب کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ اس موضوع پر کسی اسلامی ملک میں پہلی بار اظہارِ خیال کیا گیا تھا۔وہ بار بار برطانیہ اور ہالینڈ کے حوالے دیتا ہے۔ وہ امورِ مملکت میں فوجی مداخلت کے سخت خلاف ہے اور فوج کی دقیانوسی تنظیم پر کڑی تنقید کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ” مسیحی قوموں میں حکومت اب احکام اِلہٰیہ کے تابع نہیں رہی نہ اوامرو نواہی خدا کی طرف سے آتے ہیں۔ وہاں اختلافات کا فیصلہ شریعت نہیں کرتی بلکہ حکومت کے فیصلے عقل سے بنائے ہوئے قوانین و ضوابط کرتے ہیں۔ ” ابراہیم متفرقہ نے جغرافیہ، طبیعات اور فوجی حکمتِ عملی پر بھی کتابیں لکھیں۔ اسی نے پہلی بار کوپرنیکس اور دیکارٹ کے نظریات کا ذکر کیا اور ارسطا طالیسی طبیعات کی رد میں گلیلو کی دلیلوں کی حمایت میں لکھا۔ اس کی کتابیں ” فیوضاتِ مقناطیسیہ” اور ” مجموعہ حیاتِ قدیم و جدید” بہت پسند کی گئیں۔
مگر سیکولر خیالات کی نشرو اشاعت روایت پرست ملاؤں کو سخت ناگوار گزری۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ عوام میں اپنے اچھے برے کا شعور پیدا ہو او ر وہ عقل سے کام لیں۔ انھوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ جدید علوم کی تعلیم کا مقصد لوگوں کو دراصل عیسائی بنانا ہے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا ہے۔ اسی اثنا میں سلطان احمد نے فوج میں بھی اصلاحات شروع کردیں۔ یہ اصلاحات ” جاں نثاروں” کے مفاد کے خلاف تھیں لہذا انھوں نے ملاؤں کی شہ پا کر بغاوت کردی، سلطان احمد برطرف ہوا۔ صدرِ اعظم ابراہیم داماد اور امیر البحر مصطفیٰ پاشا کو گلا گھونٹ کر ہلاک کردیا گیا۔ محمد فیضی چیلپی اور سعید محمد قبرص میں جلا وطن کردیے گئے، ابراہیم متفرقہ کا چھاپہ خانہ بند ہو گیا۔
خالدہ ادیب خانم کے بقول ترکی نشاۃِ ثانیہ کا آغاز سلطان سلیم سوئم (1787ء 1807ء) کے عہد میں ہوا ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انقلابِ فرانس کے نعروں سے سارا یورپ اور امریکا گونج رہا تھا۔ معاشرتی اور فکری ہیجان انتہا کو پہنچ چکا تھا اور فرانسیسی روشن خیالوں کے نظریات کا ہر طرف ڈنکا بج رہا تھا۔ سلطان سلیم انقلابِ فرانس سے بے حد متاثر تھا مگر اصلاحات ہی اس کا مقصد نہ تھیں بلکہ وہ جدید اصولوں پر نئی ریاست قائم کرنے کا خواہش مند تھا۔” 14
سلطان سلیم نے تخت نشین ہوتے ہی یہ محسوس کر لیا کہ پرانی فوج کی موجودگی میں کسی قسم کی اصلاح ممکن نہیں لہذا اس نے ” نظامِ جدید” کے نام سے ایک متوازی نئی فوج کھڑی کی۔ مدرسے چوں کہ اصحابِ مذہب کی نگرانی میں تھے لہذا اس نے فوج، بحریہ اور انجینئرنگ کے اسکول ان مدرسوں سے الگ قائم کیے۔ انجینئرنگ اسکول میں تو وہ خود لیکچر دیتا تھا۔ اس نے ملک کے نظم و نسق میں رعایا کو شریک کرنے اور سول افسروں کی مطلق العنانی میں تخفیف کی غرض سے یہ حکم دیا کہ مقامی معاملات کا تصفیہ لوگ آپس میں مل کر خود کیا کریں۔ اس نے تیماری نظام اور کرنسی کی اصلاح کی بھی کوشش کی۔ پہلی بار مغربی ملکوں میں مستقل سفارت خانےکھولے اور فرانسیسی زبان، فرانسیسی لباس اور فرانسیسی طرزِ زندگی کی حوصلہ افزائی کی مگر سلطان سلیم نے ان اصلاحی تدبیروں سے پرانی فوج، افسر شاہی اور علما تینوں کو اپنا دشمن بنا لیا۔ 1807ء میں جن دنوں سلطان کی نئی فوج بلقان مین بغاوت فرو کرنے میں مصروف تھی پرانی فوج نے علما اور اعیان کی مدد سے قسطنطنیہ میں بغاوت کردی اور سلطان کو قتل کردیا۔
سلطان محمود دوئم (1808ء۔1839ء) سلطان شہید کا چچا زاد بھائی تھا اور اس کے خیالات سے پورا پورا اتفاق کرتا تھا البتہ وہ سلطان سلیم سے زیادہ دور اندیش ثابت ہوا۔ وہ سترہ برس تک ” جاں نثاروں” سے نباہ کرتا رہا۔ اس اثنا میں اس نے عام لوگوں سے ربط ضبط بڑھانے کی کوشش کی ۔ وہ ان میں گھل مل کر ان کی فریاد سنتا اور ان کی دل جوئی کرتا چنانچہ لوگ اس کو پیار سے محمود عدلی کہنے لگے۔ تب اس نے موقع پا کر 1862ء میں جاں نثاروں کا قلع قمع کردیا اور حکومت کا نیا ڈھانچہ بنایا جس کی رُو سے صدرِ اعظم کا عہدہ منسوخ ہو گیا، نظم و نسق کے مختلف شعبوں کے لیے الگ الگ وزرا (وکیل) مقرر ہوئے اور ان کے مجموعے کو ” باب عالی ” کا لقب دیا گیا۔ شیخ الاسلام کو اس نئی وزراتی تنظیم میں شامل نہیں کیا گیا بلکہ فرمان صادر ہوا کہ علما آئندہ سیاست میں حصہ نہ لیں۔ 1838ء میں سلطان نے مدرسوں کے متوازی نئے اسکول مغربی طرز پر قائم کیے جن میں ذریعہ تعلیم فرانسیسی زبان تھی اور سائنسی علوم کی تعلیم پر خاص توجہ دی جاتی تھی۔ اس نے جدید طرز کی ملٹری اکیڈمی اور میڈیکل کالج بھی قائم کیے اور ان کے لیے استاد وینیا (آسٹریا) سے بلوائے مگر علما نے سرجری کی تعلیم کی سخت مخالفت کی اور مردہ جسموں کی چیر پھاڑ کو ناجائز قرار دے دیا۔ لہذا سرجری سکھانے کے لیے موم کے مجسمے استعمال کرنے پڑے۔ ملاؤں نے اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ یہ بحث چھڑ دی کہ زمین گول ہے یا نہیں۔ وباؤں سے بچنا چاہیے یا تقدیر پر بھروسہ کرنا چاہیے اور یہ کہ چیچک کا ٹیکہ جائز ہے یا ناجائزلیکن سلطان نے ان اڑنگوں کی پروا نہ کی۔ اس نے پہلی بار ڈیڑھ سو نوجوانون ترکوں کو یورپ بغرض تعلیم بھیجا۔ ایک دارالترجمہ قائم کیا جس میں سید عثمان صائب اور مصطفیٰ بہجت کی نگرانی میں سائنسی علوم کی مغربی کتابیں ترکی میں ترجمہ ہونے لگیں۔ سلطان نے دُخانی کشتیوں کو رواج دیا اور لوگوں کی ہیبت دور کرنے کی خاطر خود ان میں بیتھ کر سیروتفریح کرنے لگا۔ کوٹ پتلون اور قمیض کا استعمال بھی اسی کے زمانے میں عام ہوا اور ہیٹ اوڑھنے پر جب قدامت پرستوں نے بہت شور مچایا تو 1820ء لال ترکی ٹوپی وضع کی گئی۔ ترکی زبان میں پہلا اخبار جس کا نام ” تقویم وقائع” تھا سلطان محمود ہی کے حکم سے 1831ء میں جاری ہوا۔ اس کا ایڈیٹر اسد بے تھا اور چیف ایڈیٹر مصطفیٰ سمیع (وفات 1855ء)۔
اس عہد کے بدلتے ہوئے مزاج کا اندازہ مصطفیٰ سمیع کے ” سفر نامہ اَرد پارسالسی” (1838ء) سے ہوتا ہے۔ یہ سفر نامہ روم، فلورنس، وینیا، پراگ، برلن، پیرس اور لندن کے مشاہدات و تاثرات پر مشتمل ہے۔ مصطفیٰ سمیع مغرب میں سائنس کے فروغ کا، مذہبی آزادی کا اور جدید و قدیم تخلیقات کو عجائب گھروں میں محفوظ کرنے کے شوق کا خاص طورپر ذکر کرتا ہے۔ مصنف لکھتا ہے کہ مغرب میں وہ صنعتیں ترقی پر ہیں جن کی مسلمانوں کوسخت ضرورت ہے۔ مثلاً کاغذ، سوتی کپڑے، شیشہ اور گھڑی بنانے کی صنعتیں۔ ملاؤں نے مصطفیٰ کو کافر اور ملحد کا لقب عطا کیا۔
س دور کا دوسرا روشن فکر مصنف صادق رفعت (1807ء۔ 1856ء) ہے جس نے بعد میں ” تنظیمات” کے اصول مرتب کیے۔ 1837ء میں وہ آسٹریا میں سفیر مقرر ہوا۔ وہاں قیام کے دوران اس نے یورپ کے حالات کا ترکی سےے موازنہ کرتے ہوئے دو کتابیں تصنیف کیں۔ وہ لکھتا ہے کہ ” یورپ میں حکومتیں شہریوں کی بہبودی کےلیے ہیں نہ کہ شہری حکومت کی بہبودی کے لیے۔ لہذا حکومتیں ملت کے حقوق اور مروجہ قوانین کے مطابق چلتی ہیں”۔ صادق رفعت پہلا شخص ہے جس نے ترکوں کو مغربی تہذیب و تمدن، آزادی، ملت اور انسانی حقوق کے تصورات سے متعارف کیا اور لکھا کہ مغربی تمدن جدید سائنس کی پیداوار ہے اور اس کی ٹیکنالوجی بہت اعلیٰ ہے۔
ترک مورخ سلطان محمود کو ترکی کا پیٹرا اعظم کہتے ہیں جس نے مغربی تہذیب و تمدن کو ترکی میں رائج کیا مگر نیازی برکس کے بقول ” یہ مغربی اصلاحات سلطان کے من کی موج کا نتیجہ نہ تھے بلکہ روایتی اداروں کی شکست و ریخت اور لبرل اور سیکولر خیالات کا فروغ مغربی طرز کی اصلاحات کا سبب بنے۔”
سلطان عبدالمجید (1839ء۔1861ء) نے باپ کی اصلاحی سرگرمیوں میں اور اضافہ کیا۔ ” تنظیمات” کا تاریخی دو اسی کے عہد میں شروع ہوا۔ اس نے تخت نشین ہوتے ہی 3 نومبر 1839ء کو ایک فرمان جو ” گلشنِ خطِ ہمایوں” کے نام سے مشہور ہے خود اپنے قلم سے لکھا اور شیخ الاسلام کی منظوری کے بغیر براہِ راست جاری کردیا۔ فرمان میں سلطان نے اعلان کیا تھا کہ آئندہ ہر شخص کو جان و مال اور عزت و آبرو کا قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ مسلم اور غیر مسلم رعایا قانون کی نظر میں مساوی ہوں گے۔ ” قوانینِ جدید” کے خلاف بابِ عالی سے کوئی احکام صادر نہیں ہوں گے اور ایک مجلسِ شوریٰ قائم ہوگی (سلطان کی نامزد کردہ) جو قوانین وضع کرے گی البتہ قوانین کا نفاذ سلطان کی صوابدید پر منحصر ہوگا۔ خطِ ہمایوں میں یہ تو تسلیم نہیں کیا گیا کہ اقتدارِ اعلیٰ کی مالک قوم ہے البتہ یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ سلطان کی ذات اقتدارِاعلیٰ کی مالک نہیں ہے۔
تنظیمات کے دور میں (1839ء۔ 1876ء) بظاہر بہت سی اصلاحیں ہوئیں: کابینہ کے اصول پر نئی طرز کی وزارتیں قائم کی گئیں۔ انتظامیہ، مقنّنہ اور عدلیہ کے شعبے کسی حد تک الگ ہوئے۔ شیخ الاسلام کے ماتحت عدالتوں کے پہلو بہ پہلو سیکولر عدالتیں اور روایتی مدرسوں کے پہلو بہ پہلو سیکولر اسکول کھلے جن میں گلا تاسرائے کا ایک اسکول سب سے بڑا تھا۔ وہاں تعلیم فرانسیسی زبان میں ہوتی تھی۔ ٹیجرز ٹریننگ کالج اور استنبول یونیورسٹی (1870ء) بھی اسی زمانے کی یادگاریں ہیں۔ اس کے علاوہ غیر مسلموں کو بہت سی مراعات دی گئیں اور جزیہ منسوخ ہوا۔ یہ سب کچھ ہوا مگر سلطنت کا اقتصادی ڈھانچہ نہ صرف بدستور فیوڈل رہا بلکہ اس پر مغربی سامراج مسلط ہو گیا۔ نہ جدید طرز کی فیکٹریاں قائم کی گئیں اور نہ معدنیات سے فائدہ اٹھانے کا کوئی منصوبہ بنا۔ بازاروں میں مغرب کی سستی مصنوعات کی بھرمارسے ترکی کی رہی سہی گھریلو صنعتیں بھی برباد ہو گئیں۔تجارت اور جہاز رانی کو فروغ ہوا مگر ان شعبون پر غیر ترک قوموں۔۔۔۔ یونانیوں اور ارمینوں۔۔۔ کا قبضہ تھا اور وہ برطانیہ اور فرانس کے اشاروں پر چلتی تھیں۔ ان سامراجی طاقتوں کے دباؤ کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ درآمدی مال پر ڈیوٹی کم اور برآمدی پر ڈیوٹی برائے نام لگتی تھی۔
“عثمانی سلطنت ایک طرح کی یورپی کالونی بن گئی جس کا کام مغربی ملکوں کو سستا خام مال اور وہاں کی مصنوعات کے لیے ایک وسیع بازار فراہم کرنا تھا۔ اسی دوران میں مغربی سرمائے کی کھپت بھی بڑھ گئی اور اس کو نہایت نفع بخش مراعات دے دی گئیں۔ جو کمی رہ گئی تھی اس 1854ء میں شاہی قرضوں نے پورا کر دیا۔ یہ قرضے بے حد تباہ کن شرطوں پر برطانیہ اور فرانس سے حاصل کیے گئے تھے۔ سرکاری آمدنی کے کئی اہم زرائع سود کی ادائیگی کے لیے ان طاقتوں کے ہاتھ رہن رکھ دیے گئے۔” 15
اِدھر مغربی قوتیں ترکی کی معیشت کا آخری قطرہ خون کشید کرنے میں مصروف تھیں اُدھر یورپ میں آزادیِ وطن، آئینی حکومت اور جمہوریت کی جنگ دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ ہنگری، چیکو سلوواکیہ، اٹلی، فرانس اور جرمنی میں لوگوں نے اسلحہ سنبھال لیا تھا اور دشمن کی فوجوں سے جم کر لڑ رہے تھے۔فرانسیسی روشن فکروں کی تعلیمات رنگ لا رہی تھیں۔ تنظیمات کی بدولت ترکی میں جو نیا ترقی پسند درمیانہ طبقہ نمودار ہوا اس نے یورپ کی انقلابی سرگرمیوں سے بھرپور اثر قبول کیا اور قوم میں فکرو عمل کی نئی روح پھونکی۔ وطن پرستوں کی ایک تحریک میں کچھ سرکاری ملازم تھے ، کچھ فوجی افسر اور چند کاروباری لیکن تحریک کے روحِ رواں ترکی کے روشن خیال ادیب اور دانشور تھے۔ جدید ترکی ادب اور “نوجوان ترک تحریک” دونوں کے بانی وہی تھے۔ جس طرح ہندوستان میں سرسید اور ان کے رفقا، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابو الکلام آزاد، علامہ اقبال، مولانا حسرت موہانی اور دوسرے محب وطن ادیبوں کے نزدیک ادب اور سیاست ایک ہی حقیقت کے دورُخ تھے اور وہ بیک وقت دونوں کی خدمت کرتے تھے اسی طرح ترکی میں بھی جدید ادب اور جدید سیاست کے دھارے مل کر بہتے تھے۔ ادیب ملکی سیاست سے نہ صرف وابستہ تھے بلکہ اس کی قیادت بھی انھوں ہی نے کی ۔ ان میں ابراہیم شناسی ، نامق کمال ، ضیا پاشا اور مصطفیٰ فاضل پاشا خاص طورپر قابلِ ذکر ہیں۔
” نوجوان ترکوں” کا مطالبہ تھا کہ سلطنت کا آئین رعایا کی مرضی سے وضع ہو۔ ملک میں آئینی حکومت قائم کی جائے اور عوام کے نمائندوں کو بھی نظم و نسق میں شرکت کا موقع ملے۔ مدرسے کے فرسودہ نظامِ تعلیم کی جگہ مغربی طرزِ تعلیم کو اپنایا جائے، امورِ سلطنت میں علما کی مداخلت بند کی جائے اور مغربی طاقتوں کے اثرو اقتدار کو ختم کرنے کی غرض سے مغربی تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیا جائے۔ عثمانی تہذیب درحقیقت ترک تہذیب نہ تھی بلکہ ایرانی تہذیب کا چربہ تھی۔ سلطنت کی دفتری زبان فارسی تھی اور عثمانی خواص کی زبان میں فارسی اور عربی الفاظ اور محاورے اس کثرت سے داخل ہو گئے تھے کہ عام ترک جن کی مادریج زبان کو سرکار دربار میں بڑی حقارت سے دیکھا جاتا تھا عثمانیوں کی گفتگو سمجھنے سے قاصر تھے۔ ایرانی اور عربی میں ایسی کوئی تازہ فکر بھی موجود نہ تھی جو جدید ترکی کو ذہنی خوراک مہیا کرتی یا ان کو مستقبل کی راہ دکھاتی لہذا انھوں نے ” شرقی” تہذیب پر ” غربی تہذیب” کو ترجیح دی۔ ان دنوں چوں کہ ہر طرف فرانسیسی فکر و فن کا غلبہ تھا لہذا ترک ادیبوں نے بھی فرانس سے ربط و ضبط بڑھایا اور فرانسیسی فلسفیوں ، ڈرامہ نویسوں، ناول نگاروں اورشاعروں کی تحریروں سے استفادہ کیا۔
اگر کسی فردِ واحد کو ” نوجوان ترک تحریک” اور جدید ترکی فکر و ادب کا بانی کہا جا سکتا ہے تو وہ ابراہیم شناسی آفندی (1824ء۔ 1871ء) تھا۔ ابراہیم شناسی استنبول میں پیدا ہوا۔ ایک سال کا تھا کہ باپ فوج میں لڑتا ہوا مارا گیا لہذا پرورش نانہیال میں ہوئی۔ لکھنے پڑھنے کا شوق بچپن سے تھا۔ اٹھارہ سال کی عمر میں شاہی اسلحہ خانہ میں کلرک بھرتی ہوا۔ وہاں اس نے راشد بے نامی ایک نو مسلم فرانسیسی افسر سے، جس کی بیوی ترک تھی فرانسیسی زبان سیکھی۔ ابراہیم کی ذہانت سے متاثر ہو رکر راشدے بے نے اس کو فرانس جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ اتفاق سے انھیں دنوں صدرِ اعظم معائنے پر آئے تو ابراہیم نے سرکاری وظیفے پر فرانس جانے کی درخواست پیش کردی۔ درخواست منظور ہو گئی اور وہ پیرس روانہ ہوگیا۔ پیرس میں وہ چار سال رہا اور فرانسیسی فلسفے، سائنس اور ادب کا مطالعہ کرتا رہا۔
ابراہیم شناسی 1852ء میں استنبول واپس آیا۔ اس نے تھوڑے دنوں سرکاری ملازمت کی اور سلطان عبدالمجید کی قائم کردہ سائنس و ادب کی اکیڈمی “انجمنِ دانش” کا رکن منتخب ہوگیا لیکن اس کے مزاج میں لچک بالکل نہ تھی اور نہ اس کی مضطرب روح سرکاری ملازمت کی پابندیاں برداشت کر سکتی تھی۔ اس نے نئے صدرِ اعظم کے خلاف جو آئینی اصلاحات کا جانی دشمن تھا کئی طنزیہ تحریریں شائع کیں لہذا ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ اب اس نے اخبار نویسی شروع کی۔ پہلے اخبار ” ترجمان” شائع کیا اور پھر ” تصویرِ افکار” خالدہ ادیب خانم کے بقول جدید ترکی صحافت کا بانی ابراہیم شناسی ہی ہے۔ تصویرِ افکار، کا پہلا شمارہ شائع ہوا تو سلطان عبدالعزیز (1861ء۔1874ء) نے پانچ سو پونڈ بطور تحفہ بھجوائے لیکن شناسی نے رقم یہ کہہ کر واپش کر دی کہ ” میں ایسی کوئی چیز خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتا جس کی قیمت پانچ سو پونڈ ہو۔”
ابراہیم شناسی نے خالدہ ادیب خانم کے بقول ” جدید ترکی کی زندگی اورفکر میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔” 16 اس نے حقوقِ شہریت، حقوقِ انسانی، حریت، قومی شعور، آئینی حکومت، جمہوریت اور اس قبیل کی دوسری اصطلاحوں کو نہ صرف رائج کیا بلکہ ان کے معنی و مفہوم اخبار میں بڑی شرح و بسط سے لکھے۔ وہ پہلا ادیب ہے جس نے ملت کا لفظ قوم یعنی ” نیشن” کے معنی میں استعمال کیا۔ اس نے لوک کہانیوں اور جانوروں کی کہانیوں کے مجموعے اور فرانسیسی ادیبوں کے ترجمے شائع کیے۔سماجی ڈرامے لکھے جن میں “شاعر کی شادی” میں روایتی معاشرے پر کڑی تنقید کی۔ وہ توہم پرستی کا شدت سے مخالف اور جمہوریت کا شدت سے حامی تھا۔ لہذا ملاؤں نے اس کو دہریہ اور لامذہب کہنا شروع کردیا۔
عثمانیوں نے ترکی زبان کی طرف سے جو غفلت برتی تھی ابراہیم شناسی کو اس کا بڑا تلخ تجربہ صحافتی سرگرمیوں کے دوران ہوا کیوں کہ مروجہ تحریری زبان جدید مغربی خیالات کو ادا کرنے سے قاصر تھی لہذا اس نے چودہ جلدون میں ایک جامع ترکی لغت مرتب کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن وہ فقط حرف “ط” تک مکمل کرپایا تھا کہ تشدد دوبارہ شروع ہو گیا۔ اس کے رفقا گرفتار کر لیے گئے اور اس کو مجبوراً ترکِ وطن کر کے پیرس میں پناہ لینی پری ( 1864ء) چھ سال بعد وہ استنبول واپس آیا اور اپنے چھاپے خانے کے ایک گوشے میں رہنے لگا اوروہیں نہایت عسرت کی حالت میں انتقال کرگیا۔
نامق کمال (1840ء۔1888ء) اس دور کی دوسری نہایت اہم شخصیت ہے۔ وہ جوانی میں ابراہیم شناسی سے وابستہ ہو گیا اور اس کا سچا جانشین ثابت ہوا۔ وہ سیاست داں تھا، مورخ تھا، شاعر تھا، ناول نویس تھا اور ڈرامے لکھتا تھا۔ اس نے بیکن ، مان تس کیو، روسو اور دوسرے کئی روشن خیال مصنفوں کے ترجمے شائع کیے۔ ” اورفکرِ جدید کی جو مشعل ابراہیم شناسی نے جلائی تھی اس کو ادب اور سیاست کے میدان میں لے کر آگے بڑھا۔” وطن سے والہانہ محبت اور حب الوطنی کا مخلصانہ جوش اس کی تحریروں کا امتیازی نشان ہے۔ اس کا ڈرامہ “وطن” جس رات پہلی بار استنبول میں اسٹیج پر کھیلا گیا تو تماشائی وفورِ جذبات سے بے قرار ہو کر سڑکوں پر نکل آئے اور تمام رات مظاہرے کرتے رہے۔ دوسرے دن نامق کمال گرفتار ہوگیا۔
نامق کمال فرد کے انسانی حقوق کو بہت عزیز رکھتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ جو حکومتیں عوام کی مرضی و منشا سے نہیں قائم ہوتیں وہ جبرو استبداد کی مظہر ہوتی ہیں لہذا ہر شخص کا فرض ہے کہ اپنے شہری حق کے لیے آخر وقت تک لڑتا اور قربانیاں پیش کرتا رہے۔ اس ضمن میں اس کے شاہ کار ” قصیدہ حریت” کا یہ ٹکڑا قابل غور ہے۔
” حالات کی رونے اگرچہ دیانت او ر صداقت سے مُنھ موڑ لیا ہے لیکن انسان اگر انسان ہے تو وہ خدمتِ خلق سے کبھی نہیں تھکے گا۔ افتاد گانِ خاک اور ستم رسیدِ گانِ استبداد کو سہارا دے کر اٹھانا اس کا فرض ہے۔ جو رو جبر کے حامیوں کے دل و دماغ میں فساد پرورش پاتا ہے۔ کتے خوں خوار شکاری کے حکم کی تعمیل میں خوش ہوتے ہیں۔ جلاد کی رسی موت کا اژدہا سہی مگر غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی زندگی سے یہ موت ہزار بار، صدہزار بار زیادہ گوارہ ہے۔ حُریت کا میدان آگ اور خون کا میدان سہی لیکن انسان اس سے فقط جینے کی خاطر گریز نہیں کرے گا۔مقدر اپنے تمام استبدادی حربے استعمال کرلے مگر تف ہے مجھ پر اگر میں خدمت خلق اور جدوجہد کی راہ سے ہٹ جاؤں۔ اور حریت! تجھ میں کیا جادو ہے کہ ہم نے تمام زنجیریں توڑ ڈالیں لیکن تیرے غلام ہیں۔”
نامق کمال 1870ء میں یورپ سے وطن واپس آیا۔ وہاں کی معاشرتی زندگی کے مطالعے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یورپ کی ترقی اور کامیابی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ لوگوں نے توکل اور تقدیر پرستی کے زہریلے عقاید کو ذہنوں سے خارج کردیا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ ترکی کا اصل مسئلہ اقتصادی ہے لہذا ہم کو جدید صنعت و حرفت کو ترقی دینا چاہیے اور جدید ٹیکنالوجی کو اپنا لینا چاہیے۔ آزاد پریس قائم کرنا چاہیے اور تعلیم کی از سرِ نو تنظیم کرنی چاہیے۔ نامق کمال اور اس کے ہم خیال نوجوان ترکوں کا مطالبہ تھا کہ ملک میں ” قانونِ اساسی” کی حکومت قائم ہو (یہ آئینی دستاویز خود نامق کمال نے پیرس میں تیار کی تھی)۔ نظم و نسق کی ذمہ داریاں ” مجلسِ مبعوثوں اور مجلسِ شوریٰ اُمت” کے حوالے کی جائیں اور سلطان کی حیثیت آئینی سربراہ مملکت کی ہو۔یہ وہ زمانہ تھا جب فرانس میں شہنشاہ نپولین سوئم کی مہم جوئیوں سے عوام عاجز آچکے تھے۔ جرمنی نے فرانس کو میدانِ جنگ میں شکست دے دی تھی اور نپولین کو قید کر کے فرانس کو نہایت ذلت آمیز شرائط پر صلح کرنے پر مجبور کردیا تھا مگر پیرس کے انقلابی مزدوروں نے ان شرطوں کو قبول نہیں کیا تھا بلکہ احتجاجاً اپنی پنچایتی حکومت قائم کر لی تھی ( پیرس کمیون 1870ء۔ 1871ء) ان حالات نے سلطان عبدالعزیز کو بے حد خوف زدہ کردیا۔ اس کو اندیشہ تھا کہ کہیں حُریت پسند عناصر ترکی میں بھی اس قسم کی شورش برپا نہ کردیں لہذا بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ شروع ہو ئی۔ نامق کمال اور کئی دوسرے ممتاز افراد قید کردیے گئے اور بے شمار ادیبوں اور محبِ وطن ترکوں نے یورپ میں پناہ لی۔ جب تشدد بہت بڑھ گیا تو مدحت پاشا نے جو صوبہ ڈینوب اور عراق کا گورنر رہ چکا تھا اور نوجوان ترکوں کےنصب العین سے ہمدردی رکھتا تھا سلطان عبدالعزیز کو تخت سے اتار کر اس کے بھتیجے سلطان عبدالمجید دوئم (1876ء۔ 1909ء) کو تخت پر بٹھا دیا۔ مدحت پاشا صدرِ اعظم مقرر ہوا اور ترکی میں پہلی بار 23 دسمبر 1864ء کو قانونِ اساسی سلطان کے دستخط سے ناٖفذ کیا گیا۔ سلطان نے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر حلفِ وفاداری اٹھایا اور عہد کیا کہ میں آئین سے کبھی انحراف نہیں کروں گا۔ تب آئین کے مطابق دو ایونوں پر مشتمل مجلسِ شوریٰ ملی منتخب ہوئی اور پورے ملک میں مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔
لیکن یہ خوشیاں چند روزہ تھیں۔ کیوں کہ ایک سال بھی نہ گزرا تھا کہ سلطان اپنے اصلی رنگ میں ظاہر ہوگیا۔ مدحت پاشا کو طائف میں قید کردیا گیا اور بعد میں قتل ۔ نامق کمال جزیرے میں نظر بند ہوا اور سلیمان پاشا کو بغداد جیل میں بند کردیا گیا جہاں کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہوگیا۔ آئین معطل ہوگیا، پارلیمنٹ توڑ دی گئی اور ترقی پسندوں کے خلاف داروگیر کی ملک گیر مہم شروع ہوئی۔ اس کارِ خیر میں علمائے کرام نے سلطان کے ساتھ پوراپورا تعاون کیا۔ شیخ الاسلام نے فتویٰ صادر کیا کہ آئین پسند “سرخے” ہیں یعنی پیرس کمیون کے ایجنٹ ہیں۔ سُرخ روئی کی خاطر شہاب الدین احمد ربیعی کی کتاب “سلوک الممالک فی تدبیر الممالک” سلطان کی خدمت میں بطور سند پیش کی گئی۔ لُب لُباب یہ تھا کہ ” آئین پسند مفسدہیں۔ وہ آزادی تقریر اور جمہوریت کے پردے میں سیکولرازم اور الحاد کا پروپیگنڈا کرتے ہین اور یہ کہ آزادی تقریر مہمل اصطلاح ہے۔ اسلامی ریاست کی اساس نہ اشرافیہ ہے نہ جمہوریت بلکہ خلافتِ عثمانیہ ہے لہذا اقتدارِ اعلیٰ کا مالک خدا ہے اور خدا کا نائب سلطان خلفیہ۔”
سلطان عبدالمجید کے عہدِ ظُلمت پرست میں مُلائیت اور مخبری کا کاروبار خوب چمکا۔ سلطان نے محل کے اندر ایک مخصوص مہمان خانہ مُلاؤں کی خاطر تواضع کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ زیادہ مقتدر علما کے قیام کے لیے عالی شان کوٹھیاں مخصوص تھیں۔ احمد فریس الشریاق، سید جمال الدین افغانی، شیخ محمد ظفر مکی، شیخ جواد، شیخ فضل حضرموتی،امیر مسقط، عبدالہدیٰ سیدی جلی جو روحانی طاقت کے شعبدے دکھاتا تھا سلطان کے مشیرو مصاحب بنے۔ نقش بندی شاذلی، رفاعی اور تجانی سلسوں کے دامے درمے سرپرستی ہونے لگی اور احکامِ شریعت پر لوگوں سے زبردستی عمل کروانے کی خاطر پولیس کو وسیع اختیارات دے دیے گئے تھے۔ ان ظاہر پرستیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے نیازی برکس لکھتا ہے کہ “ترکی میں غالباً کسی عہد میں دین کا تذکرہ اور شریعت کی باتیں اس کثرت سے کبھی نہیں ہوئیں لیکن بیش تر علمائے دین منافقت کا بے مثال نمونہ تھے۔” اپنے اس بیان کی تائید میں وہ موسی کاظم کا قول نقل کرتا ہے جو سلطان عبدالمجید کی برطرفی کے بعد شیخ الاسلام مقرر ہوا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ:
“مشاہیرِ سلطنت اپنی بد عنوانیوں اور سیہ کارویوں پر پردہ ڈالنے کی خاطر عبادت کو خاص طورپر استعمال کرتے تھے۔ وہ جہاں جاتے ملازم ان کی جاء نماز بغل میں دبائے پیچھے پیچھے چلتا تھا حتیٰ کہ وہ دفتروں میں بھی اپنی ان نمائشی حرکتوں سے باز نہ آتے تھے۔ محل کی خوشنودی کے لیے مذہبی بھیڑیوں کی صف میں شامل ہونا ضروری تھا ۔ خلیفہ کو خدا کا درجہ دیا گیا تھا۔” 17
سلطان کے حکم سے اخباروں، رسالوں اور کتابوں پر کڑی سنسرشپ عائد کر دی گئی ۔ بعض سیاسی اصطلاحوں مثلاً حُریت ، وطن ، آئین،جمہوریت کا استعمال ممنوع قرار پایا، حتیٰ کہ ان الفاظ کو لغت سے بھی خارج کردیا گیا۔18 تنظیماتی دور کا تمام لٹریچر جس میں نامق کمال کی تصنیفات بھی شامل تھیں ضبط ہوگیا۔ تنظیماتی لٹریچر کا اگر ایک صفحہ بھی کسی کے پاس مِل جاتا یا کسی شخص کی زبان سے ممنوعہ الفاظ نکل جاتے تو اس کو سخت سزا ملتی یا جلا وطن کردیا جاتا تھا۔۔۔۔ چنانچہ ہزاروں نوجوانوں نے نامق کمال کی تصنیفات کے خفیہ مطالعے اور تشہیر کی پاداش میں جان سے ہاتھ دھویا۔ استنبول سے جہاز کے بعد جہاز نوجوانوں کو لادے جن میں اکثر اسکول کے کمسن لڑکے ہوتے تھے، یمن اور فزان کے ریگستانوں کو جو جلاوطنی کے کاسیکی مرکزتھے روانہ ہوتے رہتے تھے۔19
تشدد، جسمانی اذیت کے خوف اور سنسرشپ کی پابندیوں سے عاجز آکر بعض ادیبوں نے فرار کی راہ اختیار کرلی اور قنوطیت کا شکار ہو گئے۔ بعضوں نے مایوس ہو کر خودکشی کر لی لیکن بیش تر ادیبوں نے سیاسی امور پر لکھنے کے بجائے تہذیبی اور معاشرتی مسائل پر طبع آزمائی شروع کردی۔ بالزک، زولا، فلابیر اور ستاندال کے ترجمے شائع کیے۔ اور عثمانی زبان کے بجائے کلاسیکی ترکی کی ترقی اور ترویج پر زور دینے لگے۔ ضیا پاشا نے روسو کی ایمیل کا ترجمہ کیا اور لکھا کہ ہماری حقیقی زبان اور شاعری وہ ہے جو ترک عوام میں زندہ ہے۔ ہماری قدرتی شاعری لوک شاعری ہے۔ مدحت آفندی نے عثمانی زبان پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ:
” ہماری قوم اپنی مادری زبان سے محروم ہو گئی ہے۔ اس کے بجائے ہم کو عثمانی زبان سیکھنی پڑتی ہے۔ یہ زبان نہ عربی ہے نہ فارسی اور نہ ترکی بلکہ ایک مخصوص اقلیت کی زبان ہے جو اکثریت پر حکومت کرتی ہے اور اس کو بے زبان بنا رہی ہے۔”20
ترکی زبان کے حامیوں میں ایک حلقہ ان ادیبوں کا بھی تھا جو عربی زبان اور رسم الخط کے سخت خلاف تھے۔ مثلاً طاہر منیف، حسین ثابت، توفیق فکرت اور حسین رحمی وغیرہ۔ طاہر منیف نے ایک تنظیم ” جماعتِ علمیہ، عثمانیہ” کے نام سے قائم کی تھی اور ایک رسالہ ” مجموعہ فنون” شائع کرتے تھے جس میں سائنسی معلومات پر تبصرہ ہوتا تھا۔ اُن کے نزدیک ترکوں کی ناخواندگی اور پسماندگی کا ذمہ دار عربی رسم الخط تھا لہذا وہ لاطینی اپنانے کے خواہاں تھے۔
سلطان کے جبرواستبداد کا مقابلہ کرنے کی غرض سے استنبول کے فوجی کالج کے طلبا نے 1889ء میں ایک خفیہ جماعت ” عثمانی لی اتحادو ترقی” کے نام سے بنائی۔ یہی گر وہ بعد میں ” نوجوان ترک” کہلایا۔ اتحاد سے اُن کی مراد سلطنت کی مختلف قوموں میں اتحاد اور ترقی سے مراد مغربی تمدن کو فروغ دینا تھا۔ 1896ء میں حکومت کو اس تنظیم کا سراغ مل گیا لہذا جو بھاگ سکے اُنھوں نے فرانس میں پناہ لی۔ بقیہ گرفتار ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد انجمن نے اپنے ٹوٹے ہوئے تار پھر جوڑے مگر اب کے اتحاد و ترقی کا مرکز سالونیکا(یورپی ترکی) میں قائم ہوا۔ کمال اتاترک سالونیکا کے اسی فوجی گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔
حمیدی دور میں سرکاری طورپر تین رحجانات کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ 1۔ روایتی اندازِ فکر۔2۔ مغربی خیالات کی شدت سے مخالفت۔3۔ اتحادِ اسلام۔ روایت پرست حلقوں کاکام یہ تھا کہ ماضی کے کارناموں کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کریں، اسلاف پرستی کو ہوا دیں، مناظرے کا لٹریچر شائع کریں اور قرآن و حدیث سے یہ ثابت کریں کہ سلطان کی اطاعت مسلمانوں کا مذہبی فریضہ ہے۔ خالدہ ادیب خانم لکھتی ہیں کہ اس گروہ نے سرکاری خرچ پر بے شمار کتابیں اور رسالے شائع کیے اور کتب فروشی کی دکانیں ان کے لٹریچر سے بھر گئیں مگر پڑھنے والوں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا البتہ مانگ اگر تھی تو اس خفیہ لٹریچر کی جو چوری چھپے یورپ سے آتا رہتا تھا۔ مغربی علوم و افکار کے خلاف مہم دو متوازی خطوط پر چلائی گئی۔ اول یہ ثابت کرنا کہ مغربی علوم اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں لہذا مسلمانوں کو ان سے دور رہنا چاہیے۔ مغربی خیالات کی روک تھام کے لیے اخباروں کو ہدایت کردی گئی کہ مغربی پارلیمنٹوں کی رُوداد ہر گز نہ چھاپیں، وہاں کی سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں کا بھُولے سے بھی ذکر نہ کریں اور وہاں حکومت میں جو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں ان کی خبریں یا جلسوں، جلوسوں اور دہشت پسندوں کی خبریں بالکل شائع نہ کریں۔ اس کے علاوہ ” ماویئین اور طبیعون” کے ابطال کی طرف بھی خاص توجہ دی گئی اور ہرشخص کو دہریہ اور ملحد کہہ کر مطعون کرنے کی کوشش کی گئی جو اصلاح یا تبدلی کا خواہاں تھا۔ اس “فکری” مہم میں سید جمال الدین افغانی کی تحریریں بہت کام آئیں۔ اُنھوں نے ہندوستان کے قیام کے دوران 1878ء میں سر سید کے خلاف فارسی میں ایک کتاب ” ردِ نیچریہ” لکھی تھی۔ 1885ء میں محمد عبدہ نے اس کا عربی ترجمہ “الردالاالدہریون” کے نام سے بیروت سے شائع کیا (جو عثمانی سلطنت میں شامل تھا)” اس کتاب میں یونان کے ایٹمی فلسفیوں سے ڈارون تک، مزدک سے روسو تک، یہودیوں سے فری میسن تک، اسماعیلیوں سے مور منوں تک اور لبرل سیاست سے سوشلزم اور کمیونزم تک ہر فکر، ہر تحریک کو نیچری قرار دیا گیا تھا اور فتویٰ صادر کیا گیا تھا کہ “اس ملعون گروہ نے ہمیشہ مذہب اور معاشرے سے غداری کی ہے، خدا سے انکار کیا ہے اور قانون و اخلاق کو برباد کیا ہے۔”21 اس کتاب کا ترکی میں ترجمہ ہوا تو اس میں مدحت پاشا ، سلیمان پاشااور دوسرے ترقی پسندوں کے ناموں کا بھی (جو سزاپاچکےتھے)اضافہ کردیا گیا اور لکھا گیا کہ “ان غداروں کو انصاف پسند ہاتھوں نے وہ سزائیں دیں جن کے وہ مستحق تھے۔”
مغرب کی طرف دوسرا رویہ فاخرانہ اور سرپرستانہ تھا جو ان دنوں ہمارے ملک میں بھی بہت عام ہے یعنی اس بات پر بغلیں بجانا کہ ہزار برس پہلے مغرب کو تہذیب و تمدن کا درس ہم نے دیاتھا اور یہ دعویٰ کرنا کہ نظامِ شمسی ہو یا نظریہ ارتقا، برقی قوت ہو یا ایٹم بم، خلا میں پرواز ہو یا چاند کا سفر تمام سائنسی ایجادوں اور دریافتوں کا ذکر ہماری مقدس کتابوں اور علماء و حکماء کی تصنیفات میں پہلے سے موجود ہے لہذا ہم کو مغرب سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہاسبھائی ہندو بھی وید اور پُران کے حوالے سے اسی قسم کے بے بنیاد دعوے کرتے رہتے ہیں۔
رہا اتحادِ اسلام کا خوش آئند نعرہ سو اس کھلونے سے مسلمانوں کو بہلانے کی کوشش تقریباً دو سو سال سے ہو رہی ہے۔ بپولین 22 سلطان عبدالحمید، انگریز سیاست داں، مسولینی، فرانکو اور ہٹلر سب نے اسلام بے چارے کو باری باری تختہ مشق بنایا اور یہ مشغلہ ہنوز جاری ہے۔ جس صاحبِ اقتدار کو مسلمانوں کے جمہوری حقوق غضب کرنے ہوتے ہیں اس کی نگاہِ لطف و کرم کا پہلا شکار اسلام ہوتا ہے۔
اتحادِ اسلام اور احیائے اسلام کے تذکرے اگرچہ سلطان عبدالعزیز ہی کے عہد میں (1872ء) شروع ہو گئے تھے لیکن اس کو سیاسی حربے کے طور پر سلطان عبدالحمید نے استعمال کیا۔ اس کا خیال تھا کہ شام ، لبنان، فلسطین، البانیہ، نجد، عراق اور یمن میں خود مختاری کی جو تحریکیں چل رہی ہیں اور خود ترکوں میں حکومت سے جو نفرت پھیل رہی ہے اس پر اتحادِ اسلامی کے نعروں کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے اور خارجی سیاست میں بھی اس حربے سے کام لیا جا سکتا ہے کیوں کہ ہندوستان، مصر، سوڈان، ترکستان، الجزائر، لیبیا اور تونس وغیرہ میں جو کروڑوں مسلمان برطانیہ، فرانس اور زار روس کے زیرِ نگیں تھے اُن کی نظر میں سلطنتِ عثمانیہ دنیا میں لے دے کر ایک ہی آزاد اسلامی مملکت باقی بچی تھی لہذا مسلمانوں کو اس مملکت سے بڑا جذباتی لگاؤ تھا۔ ہندوستان میں تو نمازِ جمعہ کا خطبہ سلطان کے نام سے پڑھا جاتا تھا۔ ایسی صورت میں سلطان اگر اتحاد اسلام کا علم بردار بن کر سامنے آئے تو مسلمان سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں سلطان کا ضرور ساتھ دیں گے ۔
سلطان عبدالحمید ایک طرف اتحادِ اسلام کا نعرہ لگا کر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں سامراجی طاقتوں کا دشمن ہوں اور دوسری طرف اس نے ملک کی ساری معیشت سامراجی طاقتوں ہی کے پاس رہن رکھ دی تھی۔ چنانچہ 1882ء میں ریلوے لائن، ٹیلی گراف لائن اور بندرگاہوں اورپُلوں کے تمام ٹھیکے انگریزوں ، فرانسیسوں اور جرمنوں کو دے دیے گئے۔ معدنیات اور بینکوں پر یورپی ساہو کاروں کا قبضہ ہو گیا اور ریاست کی مالیات کا ساراانتظام ان کے حوالے کردیا گیا۔ سامراجی تسلط کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ قرضوں پر جو سُود واجب الادا تھے فقط ان کی وصولی پر نو ہزار افراد ملازم تھے جو سب کے سب عیسائی اور یہودی تھے۔ اس کے علاوہ سلطان نے مغربی طاقتوں کا یہ مطالبہ بھی تسلیم کرلیا تھا کہ کسی ملکی یا غیر ملکی عیسائی یا یہودی پر ترکی عدالتوں میں مقدمہ نہیں چل سکے گا۔ مغربی طاقتوں نے ترکی کے اندر اپنی آزاد ریاست قائم کی لی تھی۔
آخرکار حالات اتنے ناقابلِ برداشت ہو گئے کہ جولائی 1907ء میں فوج کی تیسری کور نے جس میں کمال اتاترک بھی شامل تھے بغاوت کردی۔ سلطان عبدالحمید کو برطرف کردیاگیا۔ 1874ء کا آئین بحال ہوا۔ حکومت کی باگ ” نوجوان ترکوں” نے سنبھال لی اور نیا سلطان محمد شاد پنجم برائے نام سلطان رہ گیا۔
نوجوان ترکوں کے عہد میں (1908ء۔1919ء) ترکی کی فکر اور ترکی کی سیاست میں تین رحجان نمایاں ہوئے۔ 1۔ روایتی رُحجان جس کے بااثر ترجمان پرنس سعید حلیم پاشا تھے۔ ان کی رائے تھی کہ “اسلام کو جمہوریت کی ضرورت نہیں اور آئین لغوبات ہے۔” یہ حضرت 1913ء سے 1916ء تک ترکی کے صدرِاعظم رہے۔ ان کا دستِ راست مصطفیٰ صابری تھا جو 1918ء سے 1923ء تک شیخ الاسلام کے عہدے پر فائز رہا۔ اسی نے کمال اتاترک اور ان کے رفقا پر کفر کا فتویٰ صادر کیا تھا اور بالآخر انگریزوں سے مل گیا تھا۔ دوسرا گروہ توران پسندوں کا تھا جو عثمانی سلطنت کو نسلی بنیادوں پر استوار کرنا چاہتے تھے۔ وہ ان تمام علاقوں کو جہاں ترک آبا د تھے (وسطی ایشیا اور مغربی ایران) ترکی کا حصہ سمجھتے تھے۔ اس گروہ کے سرغنہ انور جمال پاشا تھے۔ تیسرا حلقہ نیشنلسٹوں کاتھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکی کی بقا کی بس یہی صورت ہے کہ عربوں کے حق خود اختیاری کو تسلیم کرلیا جائے اور ترکی کی نئی ریاست کو خالص ترک وطنیت کی بنیادوں پر منظم کیا جائے۔ نیشنلسٹوں کا سیاسی مفکر اور نظریاتی ترجمان ضیا گو کلپ (1875ء۔1924ء) تھا۔ کمال اتاترک، عصمت انونو، خالدہ ادیب خانم، رؤف بے اور ڈاکٹر عدنان وغیرہ پر، جنھوں نے بعد میں انقلابِ ترکی کی رہنمائی کی ضیاءگوکلپ کے خیالات کا گہرا اثر تھا۔
ضیاءگوکلپ جنوب مشرقی اناطولیہ کے تاریخی شہر دیار بکر میں پیدا ہوا۔ ابتدا میں نامق کمال اور توفیق فکرت کی تقلید میں شعر لکھتا رہا، پھر استنبول جا کر انجمنِ اتحاد و ترقی میں شامل ہوگیا اور صحافت کا پیشہ اختیار کرلیا۔ وہ جلد ہی اس نتیجے پر پہنچا کہ فقط سیاسی تبدیلیاں کافی نہیں بلکہ ترکی کو سماجی اور تمدنی انقلاب کی بھی ضرورت ہے۔ وہ مغربی تمدن کو اختیار کرنے کے حق میں تھا بشرطیکہ استمدن کو ترکی کی دو تاریخی روایات ترکی تہذیب اور اسلام سے ہم آہنگ کرلیا جائے۔ یعنی ترکی کا تمدن مغربی ہو، مذہب اسلام اور تہذیب خالص ترکی اور تینوں کو آپس میں گڈ مڈ کیا جائے۔
ضیاگوکلپ کا خیال تھا کہ روایت پرست حلقے تہذیب اور تمدن میں فرق نہیں کرتے حالاں کہ دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ تہذیب کسی قوم یا ملت کی سماجی قدروں کی نمائندگی کرتی ہے۔ وہ قومی یا ملی ہوتی ہے جب کہ تمدن نام ہے معاشرتی تنظیم اور سماجی اداروں کے مجموعے کا مثلاً نظم و نسق کے اصول، ضروریاتِ زندگی کے حصول کے طریقے، صنعت و حرفت، شہری حقوق، جمہوریت اور ملوکیت وغیرہ۔ تمدن معاشرے کا شعوری عمل ہے۔ اس کے برعکس تہذیب افراد کے شعوری عمل کا نتیجہ نہیں ہوتی نہ مصنوعی طورپر پیدا کی جا سکتی ہے۔ گوکلپ کے نزدیک کسی قوم کی تہذیب کی روح اس کی زبان ہوتی ہے جس سے وہ پہچانی جاتی ہے۔ زبان کے حوالے سے تہذیب اورتمدن کے فرق کی تشریح کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ ” فقروں کی بناوٹ کے اصول اور افعال (کھانا ، پینا، سونا، جاگنا) تہذیب کی علامتیں ہیں جو افراد کی مرضی کے تابع نہیں البتہ اصطلاحیں مصنوعی ہوتی ہیں جو تمدن کی پیداوار ہوتی ہیں۔”
ضیاگوکلپ روایت پرستوں کے اس دعوے کو بھی تسلیم نہیں کرتا کہ اسلام ایک تمدن ہے اور یہ کہ مغربی تمدن اور عیسائیت ایک ہیں کیوں کہ مذہب کا کوئی تعلق تمدن سے ہے ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تمدن اخلاقی قدروں کا پابند نہیں ہوتا بلکہ واقعاتی حقیقت ہوتا ہے لہذا مغربی تمدن کا کوئی واسطہ مذہب سے نہیں ہے۔ مغربی تمدن ایک بین الاقوامی حقیقت ہے جو برطانیہ، فرانس ، جرمنی، امریکا ہر ملک میں برتا جاتا ہے البتہ فرانس، برطانیہ، اٹلی اور جرمنی کی تہذیبیں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔
ضیاگوکلپ کہتا ہے کہ اسلام نے ہم کو پوری آزادی دے رکھی ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کے پیشِ نظر جو تمدن چاہیں اختیار کریں۔ علمائے دین پر تنقید کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ یہ حضرات جو شریعت کی بحالی پر اصرار کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اسلامی فقہ تمدنی معروضے کے سوا کچھ نہیں۔ وہ قرونِ وسطیٰ کے تھیو کریٹک تمدن کی ضرورتوں کو پورا کرتی تھی۔ یہ حضرات اسلام کی آفاقی سچائیوں اور ان حقیقتوں کے درمیان فرق کرنے میں ناکام رہے ہیں جن کا تعلق اُمت کی وقتی ضرورتوں سے تھا۔ جدید تمدن صنعتی انقلاب کا آوردہ پروردہ ہے لہذا فقہ جو پرانے تمدن کی نمائندہ ہے جدید تمدن سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتا ہے کہ ہم کو اُمت کے تصور کو بھی ملت کے ساتھ گڈ مڈ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں کہ اُمت بین الاقوامی مذہبی جمعیت ہے جب کہ ملت کی بنیاد وطن ہے (ترک اور ایرانی دانش ور ملت کی اصطلاح کو قوم اور وطن کے معنی میں استعمال کرتے ہیں) وہ ترکوں کو ایک ملت قرار دیتا ہے اور اس ملت میں عربوں کو شامل نہیں کرتا اور نہ اُن ترکوں کو جو ترکی کی حدود سے باہر ترکستان یا ایران میں آباد ہیں کیوں کہ ضیاگو کلپ کے نزدیک ملت کی بنیاد نسل نہیں ہے بلکہ وطنی تہذیب ہے۔
ضیاگو کلپ آخر میں اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ترکوں کو عربی اور ایرانی تہذیبوں سے کنارہ کش ہو کر ترکی کی نئی تہذیب کو ترکی زبان اور ترکی لوک ادب کی بنیادوں پر فروغ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ترکوں کا مذہب اسلام ہو گا اور تمدن مغربی۔
” ہم کو مغربی تمدن کو اپنا لینا چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو مغربی طاقتیں ہم کو اپنا غلام بنا لیں گی۔ ہم کو دو میں ایک کو چُننا ہے: مغربی تمدن پر پورا عبور یا مغربی طاقتوں کا مکمل غلبہ، مغربی تمدن عبارت ہے سائنسی علوم سے، جدید صنعتی تکنیک سے اور سماجی تنظیمات سے (جمہوریت، شہری حقوق، پارلیمانی انتخابات، ذمہ دار حکومت) یورپ اپنی تمدنی فوقیت ہی کہ وجہ سے مسلمان قوموں کو شکست دینے میں کامیاب ہوا اور دنیا کا آقا ہوگیا۔”23
“نوجوان ترکوں” نے 1908ء میں جس وقت سلطان عبدالحمید کو برطرف کر کے ملک میں آئینی حکومت قائم کی تو انجمنِ اتحاد و ترقی میں اتحادِ اسلام کے داعی، توران پسند اور نیشنلسٹ تینوں عناصر شامل تھے مگر جنوری 1913ء میں انور پاشا ، طلعت پاشا اور جمال پاشا نے جوا تحادِ اسلام اور تورانیت کے سرغنہ تھے تمام اختیارات خود سنبھال لیے، قومی اسمبلی توڑ دی جس میں نیشنلسٹوں کی اکثریت تھی ( وہ یورپ کی سامرجی سیاست میں کسی فریق کا ساتھ دینے کے خلاف تھے) جرمنی کے ساتھ خفیہ معاہدہ کر لیااور جنگ چھِڑی تو جرمنی کی طرف سے جنگ میں شریک ہو گئے۔
جنگ میں شریک ہو کر ترکی کی قیادت نے بڑی عاقبیت نا اندیشی کا ثبوت دیا۔ انور پاشا اور اس کے رفیقوں کو امید تھی کہ فتح کے بعد جرمن حکومت روسی ترکستان، مصر، لیبیا، تونس اور الجزائر کو اِتحادی طاقتوں سے چھین کر ترکی کے حوالے کردے گا۔ وہ اس غلط فہمی میں بھی تھے کہ مغربی مقبوضات کے مسلمان ترکی کے حق میں بغاوت کردیں گے اور سلطنت کے عرب مسلمان ترکوں سے پورا پورا تعاون کریں گے لیکن ترکی حکومت کی یہ خواہشیں پوری نہ ہوئیں اور جب شکست ہو گئی تو انورپاشا اور اس کے رفقا ترکی حکومت کی یہ خواہشیں پوری نہ ہوئیں اور جب شکست ہو گئی تو انورپاشا اور اس کے رفقا ترکی کو اس کے حال پر چھوڑ کر ملک سے فرار ہو گئے اور حکومت پر سلطان کا قبضہ ہوگیا۔ برطانوی فوجوں نے استنبول پر قبضہ کرلیا اور سلطان انگریزوں کا تابع ہوگیا۔ مشرقی اناطولیہ کے ارمنی علاقے کو آزاد ریاست کا درجہ دے دیا گیا اور یونانی فوجوں نے اسمرنا کے مقام پر اتر کر قتل عام شروع کردیا۔ ستم بالائے ستم یہ کہ سلطان نے ترکی فوجوں کو جو اناطولیہ میں بکھری ہوئی تھیں ہتھیار ڈال دینے کا حکم دے دیا۔ تب حُریت پسند ترکوں کی غیرت و حمیت نے نے جوش مارا۔ ان کی آزادی، ان کا قومی وجود، ان کی زندگی سب خطرے میں تھی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ عورتیں مرد، جوان بوڑھے، شہری ، دیہاتی، ہتھیار بند اور نہتے۔ حُب الوطنی کے اس جوش ، اس ولولے کی قیادت کمال اتاترک نے کی۔ وطن فروش سلطان نے جو سامراجی طاقتوں کے ہاتھ میں کٹھ پُتلی تھا، کمال اتاترک، علی فواد پاشا، ڈاکٹر عدنان بے اور ان کی مجاہد بیگم خالدہ ادیب خانم سمیت سات رہنماؤں کو ان کی غیر حاضری پر موت کی سزا دے دی مگر موت کے فرشتے ان کا بال بیکانہ کرسکے۔ شیخ الاسلام نے فتویٰ صادر کیا کہ جو شخص ان ساتوں کو قتل کرے گا اس کو جنت میں انعام ملے گا لیکن کوئی ترک شیخ الاسلام کی جنت میں جانے پر راضی نہ ہوا۔ آزادی کی جنگ دو سال تک جاری رہی۔ یونانی فوجوں نے شکست کھائی۔ اتحادی فوجیں اطاطولیہ، استنبول اور سالونیکا سے واپس جانے پر مجبور ہوئیں۔ سلطان نے برطانوی جنگی جہاز میں پناہ لی اور مالٹا بھاگ گیا۔ انقلابِ ترکی کا سرخ پرچم سُرخ رُو ہوا۔ کمال اتاترک جمہوریہ ترکی کے صدر منتخب ہوئے اور تب قومی اسمبلی نے نومبر 1922ء میں اتفاقِ رائے سے بادشاہت کے خاتمے کا اعلان کردیا۔ 2 اگست 1923ء کو نئی مجلسِ آئین ساز منتخب ہوئی۔ اکتوبر 1923ء میں نیا آئین منظور ہوا۔ مارچ 1924ء میں اسمبلی نے خلافت کا عہدہ منسوخ کردیا اور مذہب کو ریاست سے الگ کرنے کی غرض سے متعدد قانون منظور کیے۔ شیخ الاسلام کا عہدہ توڑ دیا گیا اور امورِ مذہبی کا شعبہ وزیرِاعظم کی تحویل میں دے دیا گیا۔ اوقاف کی زمینوں کو قومی ملکیت قرار دے دیاگیا۔ ترکی کی نئی ریاست سیکولر ہو گئی چنانچہ ترکی کے نئے آئین میں وضاحت کردی گئی کہ:
“ترکی ری پبلک ایک نیشنلسٹ، جمہوری، سیکولر اور سوشل ریاست ہے جس پر انسانی حقوق پر مبنی قانون کی حاکمیت ہے۔” (دفعہ2)
آج کل تو خیر سے ہم نے ہیرو سازی کی فیکٹریاں کھول رکھی ہیں لیکن بیسوی صدی کی دوسری اور تیسری دہائی میں دنیائے اسلام کی سب سے ہر دل عزیز شخصیت کمال اتاترک کی تھی۔ وہ انقلابِ ترکی کے قائد اور جدید جمہوریہ ترکی کے بانی ہی نہ تھے بلکہ پورے مشرق کی آبرو سمجھے جاتے تھے۔ اُنھوں نے مغربی طاقتوں کو شکست دی تھی۔ لہذا محکوم ملکوں کے لوگ ان کے کارناموں میں اپنی خواہشوں کا عکس دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ ہندوستان کے گوشے گوشے میں ان کی اصلی اور فرضی تصویریں پنواڑیوں، درزیوں، حجاموں اور خوردہ فروشوں کی دکانوں میں لٹکی رہتی تھیں۔ اخباریین طبقہ ترکی کے حالات بڑے شوق سے پڑھتا تھا۔ مقررین جلسوں میں بہادر ترکوں کی سرفرشیوں کا ذکر کر کے حاضرین کو جوش دلاتے تھے۔ ترکی ادیبوں کی تحریریں ہمارے رسالوں کی زینت بنتی تھیں اور برصغیر کا شاید ہی کوئی ممتاز اہلِ قلم تھا جس نے جدید ترکی کا خیر مقدم نہ کیا ہو۔ کمال اتاترک کے انقلابی اقدامات سے علامہ اقبال بھی بہت متاثر تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ترکی میں ایک نیا انسان پیدا ہو رہا ہے اور ترکوں کی بیداری تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے حیاتِ نو کا مژدہ ثابت ہوگی۔ ان کی آخری دنوں کی ایک نظم ” غلاموں کی نماز” ہے جس میں اُنھوں نے ترکوں کی روشن خیالی کو خوب سراہا
کہا مجاہدِ ترکی نے مجھ سے بعدِ نماز
طویل سجدہ ہیں کیوں اس قدر تمھارے امام
وہ سادہ مردِ مجاہد، وہ مومنِ آزاد!
خبرنہ تھی اسے کیا چیز ہے نمازِ غلام
ہزار کام ہیں مردانِ حُر کو دنیا میں
انھیں کے ذوقِ عمل سے ہیں اُمتوں کے نظام
بدن غلام کا سوزِ عمل سے ہے محروم
کہ ہے مرورغلاموں کے روز و شب پہ حرام
طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے
دُرائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام
خطباتِ مدراس میں جدید ترکی کے تاریخی کردارپر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:
“سچ تو یہ ہے کہ دورِ حاضرکی مسلم قوموں میں فقط ترکی نے اعتقاد کی نیند کو جھٹک دیا ہے اور شعورِ ذات حاصل کرلیا ہے۔ ترکی واحد ملک ہے جس نے ذہنی آزادی کے حق کا دعویٰ کیا ہے۔ ترکی جانتا ہے کہ حرکت کرتی اور پھیلتی ہوئی زندگی کی بڑھتی ہوئی پیچیدگیاں یقیناً نئے حالات پیدا کریں گی اور نئے نقطہ ہائے نظر کی دعوت دیں گی اور ان اصولوں کی ازسرِ نو تفسیر کی متقاضی ہوں گی جو روحانی کُشادگی کی مسرت سے ناآشنا حضرات کے لیے فقط مجلسی دل چسپی کا باعث ہوتے ہیں۔ میراخیال ہے کہ وہ انگریز مفکر ہابس تھا جس نے یہ بلیع بات کہی تھی کہ ہو بہو یا یکساں خیالات و جذبات کی متواتر تکرار کے معنی تو یہی ہوئے کہ خیالات ہیں نہ جذبات۔ فی زمانہ مسلمان ملکوں کا یہی حال ہے۔ وہ میکانکی طورپر پرانی قدروں کو دہرائے جارہے ہیں جب کہ ترکی نئی قدروں کی تخلیق پر آمادہ ہے۔ اس کی زندگی حرکت کرنے، بدلنےاور پھیلنے لگی ہے۔اس میں نئی خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں جو اپنے ہمراہ نئی دشواریاں لاتی ہیں اور نئی تشریحوں کی دعوت دیتی ہیں۔”24
کیا سیکولرازم کی اس سے بہتر تشریح ممکن ہے۔ مگر ہماری قوم اتنی طویل سجدہ ہوتی جا رہی ہے کہ اس کو سامنے کی چیزیں نظر نہیں آتیں۔ نہ مرحلہ شوق کی جستجو باقی رہی ہے نہ ہر لحظہ نئے طُور اور نئی برقِِ تجلی کی آرزو۔ نہ موجِ تحقیق سے دریا میں تلاطم پیدا کرنے کا حوصلہ ہے اور نہ اپنے اعجارِ ہنر سے فطرت کو شرمندہ کرنے کا ولولہ۔
کمال اتاترک نے ترکی کو ایک ترقی پسند اور ترقی پذیر مملکت بنانے کی پوری کوشش کی۔ اس نے وہ تمام مراعات منسوخ کردیں جو سامراجی طاقتوں کو ترکی میں حاصل تھیں۔ ترکی میں سوئزر لینڈ کے نمونے پر سِول ضابطہ قوانین، اطالوی نمونے پر فوجداری ضابطہ قوانین اور جرمن نمونے پر تجارتی ضابطہ قوانین رائج کیے گئے۔ ترکی زبان کا رسم الخط عربی کے بجائے لاطینی ہوگیا۔ عورتوں کو مردوں کے برابر شہری حقوق ملے اور پردے کا رواج ختم ہوگیا۔ یورپ کے ” مردِ بیمار” نے بالآخر شفا پائی اور اس کا شمار دنیا کی معزز اور باوقار قوتوں میں ہونے لگا۔
مگر کمال اتاترک کی آنکھ بند ہوتے ہی ان کے جانشینوں نے انقلابِ ترکی کے نصب العین کو بالائے طاق رکھ دیا۔ وہ ملک کو صنعتی اعتبار سے خود کفیل نہ بنا سکے۔ وہ یہ بھول گئے کہ مغربی تمدن کوٹ پتلون پہننے اور کانٹے چھری استعمال کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ مغربی تمدن کا انحصار جیسا کہ نامق کمال اور ضیاگوکلپ نے بار بار تنبیہہ کی تھی جدید صنعت و حرفت اور سائنسی ٹیکنالوجی کو فروغ دینے پر ہے، شہری حقوق کو عام کرنے پر ہے، جمہوری اداروں کو مستحکم کرنے پر ہے۔ ترکی کے نئے حکمرانوں نے ان فرائض کی بجا آوری کے بجائے یورپ کی فاشسٹ قوتوں سے ناتا جوڑا اور ترقی پسند عناصر پر تشدد کرنے لگے۔ ترکی ہٹلر کے گماشتوں کا اڈا اور سازشوں کا مرکز بن گیا۔ دوسری جنگِ عظیم میں فاشسٹوں کو شکست ہوئی تو ترکی سیاست نے امریکہ کی حلقہ بگوشی اختیار کرلی اور ترکی معیشت امریکہ کی فوجی اور مالی امداد کی دست نگر ہو گئی۔ اب ہر جگہ امریکہ کے فوجی اور ہوائی اڈے قائم ہیں اور ترکی کی خارجی اور داخلی پالیسی کا دامن امریکہ سے بندھا ہوا ہے۔ اسی عاقبت نا اندیشی کا نتیجہ ہے کہ ترکی گزشتہ چوتھائی صدی سے مسلسل سیاسی اور اقتصادی بحران میں مبتلا ہے۔ اقتدار پر فوج کا قبضہ ہے، شہری آزادی مفقود ہے، جمہوریت کا نام و نشان باقی نہیں اور سیکولرازم کے مخالفین کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔
(4)
برصغیر پاک و ہند کی تاریخ 27 مئی 1498ء کی وہ ساعت کبھی نہ بھولے گی جس وقت پرتگالی جہاز رانوں نے واسکوڈی گاما کی قیادت میں ساحل ملا بار پر لنگر ڈالے اور کالی کٹ کے راجہ زمورن سے تجارتی تعلقات قائم کیے۔ پرتگالیوں نے جلد ہی گواپر قبضہ کرلیا جو سلطنتِ بیجاپور کی اہم بندرگاہ تھی اور رفتہ رفتہ دمن، سایست، بسین، چول، بمبئی اور بنگال میں ہگلی کے بھی مالک ہو گئے۔ اُنھوں نے گوا میں اپنا پریس لگایا جس میں مذہبی کتابیں چھپتی تھیں اور لوگوں کو زبردستی عیسائی بنانے لگے۔ مقامی باشندوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ ان کا سلوک نہایت ظالمانہ تھا کیوں کہ ان کی آمد سے پیش تر بحرِ ہند کی تجارت صدیوں سے عربوں کے ہاتھ میں تھی۔ بالآخر وہ اپنے تجارتی حریفوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے اور بحرِ ہند میں ان کا عمل دخل اتنا بڑھا کہ سولھویں سترھویں صدی میں مغل شہزادوں، شہزادیوں اور عمائدینِ سلطنت کو بھی حج و زیارت کے لیے پرتگالی جہازوں ہی میں سفر کرنا پڑتا تھا۔ اس کے باوجود مغلوں کو اپنی بحری طاقت بڑھانے کا خیال نہ آیا نہ اُنھوں نے پرتگالیوں کی سیاسی ریشہ دوانیوں کو در خورِ اعتنا سمجھا۔ پرتگیز پادریوں نے چھاپے خانے کا نمونہ شہنشاہ اکبر کو دکھایا تھا مگر اُس دوراندیش فرماں روا نے بھی اس انقلابی ایجاد کی اہمیت و افادیت کو محسوس نہ کیا اور یہ کہہ کر ٹال دیا کہ پریس لگا تو ہمارے خوش نویسوں کی روزی ماری جائے گی۔
انگریزوں نے پُرتگالیوں کے سو سال بعد ہندوستان کا رخ کیا۔ اُنھوں نے 31دسمبر 1600ء کو لندن میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی۔ ان کا تجارتی نمائندہ، کپتان ہاکنس 1608ء میں یہاں آیا اور جہانگیر کے دربار میں حاضر ہوا۔ مگر انگریزوں کو پانچ سال کی دوڑ دھوپ کے بعد 1613ء میں سُورت میں فیکٹری (تجارتی کوٹھی) کھولنے کی اجازت ملی۔ آہستہ آہستہ اُنھوں نے مغل بادشاہوں سے مختلف مراعات حاصل کرلیں اور احمد آباد، بھڑوچ، آگرہ، لکھنو، مسولی پٹم، ہگلی، قاسم بازار، پٹنہ اور مدراس میں بھی ان کی فیکٹریاں کُھل گئیں۔ رفتہ رفتہ اُنھوں نے شاہی دربار میں بھی رسوخ پیدا کرلیا۔ ڈاکٹر برنیئر اورنگ زیب کے عہد میں بارہ سال دہلی میں رہا۔ وہ نواب دانش مند خان کا طبیب تھا ۔ برنیئر کی سرگزشت سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے نواب کو فرانس کے روشن خیال مفکروں بالخصوص ڈیکارٹ اورگے سندی کا فلسفہ بھی پڑھایا تھا مگر نئی روشنی کی یہ ٹِمٹماتی لَو برنیئر کے جاتے ہی بجھ گئی اور اس چراغ سے دوسرا کوئی چراغ نہ جلا۔
ایسٹ انڈیا کمپنی نے بمبئی اور مدراس میں قدم جمانے کے بعد جلد ہی محسوس کرلیا تھا کہ مرکزی حکومت کی کمزوری اور صوبوں کی خود مختار حکومتوں کی بد نظمیوں کی وجہ سے ملک میں جو ابتری پھیلی ہوئی ہے اس کے پیشِ نظر تجارت کے تحفظ و فروغ کے لیے سیاسی اقتدار حاصل کرنا نہایت ضروری ہے چنانچہ سرجارج آک زندن گورنر سورت نے 1669ء میں کمپنی کے ڈائریکٹروں کو مشورہ دیا تھا کہ ” حالات کا اب یہی تقاضا ہے کہ آپ اپنی تجارت کا انتظام بزورِ شمشیر کریں” اور کمپنی نے اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے 1687ء میں مدراس کے گورنر کو لکھا تھا کہ ” ایسی سِول اور فوجی حکومت قائم کی جائے اور دونوں شعبوں کی کفالت کے لیے اتنی آمدنی کا بندوبست کیا جائے جو ہندوستان میں ایک وسیع اور پائیدار برطانوی مقبوضے کی بنیاد بن سکے۔” واضح رہے کہ یہ یادداشت اس زمانے کی ہے جب شہنشاہ اورنگ زیب مدراس سے چند سو میل کے فاصلے پر دکن فتح کرنے میں مصروف تھا اور مغلیہ سلطنت بہ ظاہر متحدو مستحکم تھی۔
اورنگ زیب کی وفات کے بعد سلطنت کا شیرازہ جس طرح بکھرا اس کی عبرت ناک داستان سے ہر شخص واقف ہے۔ چنانچہ انگریزوں نے پہلے حیدرآباد دکن کا رخ کیا اور وہاں درباری سازشوں کے ذریعے آصف جاہی خاندان کو ہمیشہ کے لیے اپنا تابعدار بنالیا۔ پلاسی اور بکسر کی لڑائیوں کے بعد کمپنی بنگال، بہار اور اڑیسہ کی بھی مالک ہو گئی اور 1765ء میں شاہ عالم ثانی (1759ء۔1804ء) نے فرمان کے ذریعے ان صوبوں کے دیوانی کے اختیارات کمپنی کو سونپ کر کمپنی کے قبضہ مخالفانہ کی توثیق بھی کردی۔ تسخیر ہند کا عمل شروع ہوگیا۔
اس بیرونی اقتدار نے یوں تو مقبوضہ علاقوں کی معاشرتی زندگی کے سب ہی شعبوں پر اثر ڈالا لیکن روایتی تہذیب و تمدن کے تین عناصر خاص طورپر متاثر ہوئے۔ 1۔ عدالتی نظام ۔2۔ تعلیمی نظام۔3۔ فکری اور اعتقادی نظام۔
مغلوں کے عہد میں حکومت کا نظم و نسق دیوانی اور نظامت دو حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ محکمہ دیوانی کے سپرد مال گزاری اور محصولات کی وصولی تھی اوران مقدموں کا فیصلہ جن کا تعلق وراثت، زمینوں کے جھگڑے، لین دین کے معاہدوں اور شادی بیاہ سے ہوتا تھا۔ دیوانی کے مالیاتی شعبوں میں اکثریت ہندو کائستھوں کی تھی جن کو فارسی آتی تھی اور جو حساب کتاب میں بھی ماہر تھے۔ مسلمان عموماً ان پیشوں کو حقارت سے دیکھتے تھے۔ اس طرزِ عمل کا خمیازہ ان کو انگریزوں کے عہد میں بُھگتنا پڑا۔ دیوانی عدالتوں میں ہندوؤں کے مقدموں کے فیصلے دھرم شاستر کی رُو سے پنڈت کرتے تھے اور مسلمانوں کے فیصلے شریعت کے مطابق قاضی۔ ناظم دراصل صوبے کا گورنر ہوتا تھا۔ شاہی فوج اس کے ماتحت تھی۔ صوبے میں امن و امان قائم رکھنا، شاہی قوانین کو نافذ کرنا اور نظم و نسق کی نگرانی کرنا اسی کی ذمہ داری تھی۔ فوجداری کے قوانین (قتل، ڈاکہ، چوری، بلوہ فساد وغیرہ) جو حنفی فقہ پر مبنی تھے ہندو مسلمانوں دونوں کے لیے یکساں تھے۔ لہذا فوجداری عدالتوں کے حاکم مسلمان ہوتے تھے اور فوجداری کے دوسرے محکموں میں بھی اکثریت مسلمانوں کی ہوتی تھی۔
جہاں تک تعلیمی نظام کا تعلق ہے اٹھارویں صدی میں ہندوستان کیا دنیا کے کسی حصے میں بھی رعایا کی تعلیم ریاست کی ذمہ داری نہیں سمجھی جاتی تھی۔ ہندوؤں کے راج میں راجے، مہاراجے اور دھن دولت والے پاٹھ شالوں کو جو عموماً مندروں سے ملحق ہوتے تھے زمینیں دان پن کردیتے تھے تاکہ پاٹھ شالوں کا خرچ چلتا رہے۔ ان کے علاوہ کاشی، متھرا، ہر دوار اور دوسری تیرتھ گاہوں میں بڑے بڑے ودوان پنڈٹ اور سادھو سنت بھی تھے جو اپنے چیلوں کو وید، پُران، بھگوت گیتا اور دھرم شاستر کی شِکسا دیتے تھے۔ مسلمان بادشاہوں کی پرانی روایت بھی یہی تھی۔ وہ ممتاز علما اور معلمین کو مکتبوں، مدرسوں کے مصارف کی خاطر ” مددِمعاش” کے طورپر زمینیں دے دیتے تھے۔ (ایک اندازے کے مطابق صوبہ ٹھٹھہ کی تقریباً ایک تہائی زمینیں علما کو مفت ملی ہوئی تھیں) علم دوست شہزادے اور امرا بھی اپنے خرچ سے مدرسے قائم کرتے رہتے تھے۔ صوفیائے کرام کے اپنے حلقے اور دائرے تھے جن میں مُریدوں کی تعلیم و تربیت اور کھانے رہنے کا انتظام مفت تھا۔ پہلا سرکاری مدرسہ سلطان شہاب الدین غوری نے 1191ء میں اجمیر میں قائم کیا تھا۔ پھر بختیار خلجی نے بنگال میں بہت سے مدرسے کھولے۔ سلطان التمش نے 1227ء میں اُچھ میں اور 1237ء میں دہلی میں مدرسے قائم کیے 25؎ مغلوں کے دور میں ملتان، ٹھٹھہ، سیالکوٹ، جون پُور، پٹنہ اور دہلی تعلیم کے بڑے مرکزتھے لیکن شاید ہی کوئی شہر یا بستی ایسی تھی جہاں مدرسے اور مکتب موجود نہ ہوں۔
مسلمانوں کے عہد میں ذریعہ تعلیم فارسی تھا۔ مکتبوں میں حروف ہجا کی پہچان سکھائی جاتی تھی۔ لکھنے کی مشق لکڑی کی تختیوں پر سرکنڈے کے قلم اور چاول گیہوں کو جلا کر گھر کی بنی ہوئی سیاہی سے ہوتی تھی لہذا تعلیم کے مصارف برائے نام تھے۔ حروف شناسی کے بعد بچوں کو بغدادی قاعدے کی گردانیں اور پارہ عم کی چند سورتیں یاد کرا دی جاتی تھیں اور فارسی کے کچھ مصاد رو الفاظ بھی پڑھا دیے جاتے تھے۔ شاید گلزارِ دبستان قسم کی کوئی آسان کتا ب تھی۔ مدرسوں کے نصاب میں جہاں اعلیٰ تعلیم کا انتظام تھا فقہ، اصولِ فقہ، بلاغتِ نحو، علم کلام، تصوف اور تفسیر کی کتا بیں داخل تھیں جو صدیوں پہلے ایران اور عراق میں لکھی گئی تھیں۔ زیادہ زور فقہ پر دیا جاتا تھا کیوں کہ عدالتوں میں ملازمت کے لیے فقہ سے واقفیت ضروری تھی۔ اکبر کے عہد میں جہاں اور بہت سی اصلاحیں ہوئیں وہاں پرانے تعلیمی نظام کے پہلو بہ پہلو سیکولر تعلیم رواج دینے کی کوشش بھی کی گئی۔ چنانچہ مفتی انتظام اللہ شہابی آئینِ اکبری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اکبر کے عہد میں ایسی درس گاہیں بھی تھیں جن میں ” طالب علموں کو ریاضی، اخلاقیات، زراعت، مساحت، جیومیٹری، نجومیات، اصولِ حکومت، طب، منطق، کیمسٹری، طبیعات اور تاریخ کی تعلیم دی جاتی تھی۔”26
ڈاکٹر عابد حسین لکھتے ہیں کہ
” اکبر نے بہت سے سرکاری اسکول کھولے جن میں ہندو اور مسلمان لڑکوں کو ایک ساتھ فارسی میں تعلیم دی جاتی تھی۔ مضامین خالص سیکولر ہوتے تھے مثلاً منطق، اخلاقیات، جیومیٹری، طبیعات، طب، سیاسیات، تاریخ اور فارسی ادب۔”27
مگر سیکولر تعلیم کی پالیسی کو اکبر کے جانشینوں نے ترک کردیا اور روایتی تعلیم پھر سے رائج ہو گئی۔ البتہ اورنگ زیب کو مروجہ نصابِ تعلیم کی فرسودگی کا احساس تھا۔ اس کا اندازہ اورنگ زیب کی ایک تقریر سے ہوتا ہے جو اس نے اپنے سابق استاد کے رُو برو کی تھی۔ موصوف اورنگ زیب سے جب وہ بادشاہ ہوا تو اپنے حق استادی کا انعام مانگنے گئے تھے ۔ا ورنگ زیب نے ان کی جغرافیہ دانی اور کمالِ علمِ تاریخ کو پول کھولنے کے بعد کہا کہ:
” کیا استاد کو لازم نہ تھا کہ دنیا کی ہر ایک قوم کے حالات سے مجھے مطلع کرتا مثلاً ان کی حربی قوت سے، ان کے وسائلِ آمدنی اور طرزِ جنگ سے، ان کے روسم و رواج اور مذاہب اور طرزِ حکمرانی سے اوران خاص خاص امور سے جن کو وہ لوگ اپنے حق میں زیادہ مفید سمجھتے ہیں بہ تفصیل مجھ کو آگاہ کرتا اور علمِ تاریخ مجھے ایسا سلسلے وار پڑھاتا کہ میں ہر ایک سلطنت کی جڑ، بنیاد اور اسبابِ ترقی و تنزل اور ان حادثات و واقعات اور غلطیوں سے واقف ہو جاتا جن کے باعث ان میں ایسے بڑے بڑے انقلاب آتے رہے ہیں۔۔۔۔ اور باوجود یکہ بادشاہ کو اپنی ہمسایہ قوموں کی زبانوں سے واقف ہونا ضروری ہے بجائے ان کے آپ نے مجھ کو عربی لکھنا پڑھنا سکھایا اگرچہ اس زبان کے سیکھنے میں میری عمر کا ایک بڑا حصہ ضائع ہوا۔۔۔۔۔ آپ نے بغیر یہ سوچے کہ ایک شہزادے کو زیادہ ترکن کن علوم کی ضرورت ہے فقط صرف و نحو اور ایسے فنون کی تعلیم کو جو ایک قاضی کے لیے ضروری ہیں مقدم جانا اور ہماری جوانی کے ایام کو بے فائدہ اور لفظی بحثوں کے پڑھنے پڑھانے میں ضائع کیا۔”28
مگر افسوس ہے کہ مُلا نظام الدین سیوہالوی نے جو نصابِ تعلیم سلطان ذی فہم کے حکم سے مرتب کیا (درسِ نظامی) اس میں اُن علوم کا ذکر تک نہیں جن کی افادیت پر سلطان نے اپنی تقریر میں زور دیا تھا بلکہ اُنھیں علوم پر اصرار کیا گیا جن پر سلطان معترض تھا۔ مثلاً منقولات میں تجوید اور قرات، تفسیر، حدیث، فقہ اور اصولِ فقہ، فرائض (وراثت ) کلام اور تصوف، معقولات میں صرف و نحو، بلاغت، عروض، منطق، حساب، ہیئت، حکمت اور مناظرہ۔ مفتی انتظامِ اللہ شہابی اس نظام تعلیم کے بڑے ثنا خواں ہیں مگر ان کو بھی دبی زبان سے یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ” ہر چند کہ اسلام نے قرونِ وسطیٰ میں عظیم مفکر اور سائنس داں پیدا کیے مگر (درسِ نظامی) ان علوم کی عدم موجودگی حیرت انگیز ہے۔ اسلام کے ممتاز مفکر۔۔۔۔ الکندی، الفارابی، ابنِ سینا، البیرونی اور ابنِ رشد وغیرہ سرے سے غائب ہیں۔” لطف یہ ہے کہ ہمارے دینی مدارس میں ابھی تک اسی قسم کا فرسودہ نصاب رائج ہے۔
اسلامی مفکر میں جمود کا بنیادی سبب تو یہ تھا کہ خود مسلم معاشرہ جمود کا شکار ہوگیا تھا۔ تلاش و تحقیق، تجربہ اور مشاہدہ، اجتہادی تفکر اور نامعلوم کرنے کے شوق کی پرانی روایت کو علمائے دین اور صوفیائے کرام نے نہ صرف ترک کردیا تھا بلکہ قرونِ وسطیٰ کے روشن خیال مسلمان مفکروں کو کافر، ملحد اور زندیق کے لقب سے نوازتے تھے اور ان کی تصنیفات کا مطالعہ ممنوع کردیا گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے اربابِ علم منقولات کی دلدل میں ایسے پھنسے کہ پھر کبھی نکل نہ سکے۔ بس مکھی پر مکھی مارتے رہے۔ پرانی کتابوں کی شرحیں اور حاشیے لکھتے رہے بلکہ حاشیوں پر حاشیے۔ نہ اپنی بصیرت و آگہی میں اضافہ کیا نہ بد نصیب قوم کی اور بقول اقبال یہ اُمت خرافات میں کھو گئی۔ چنانچہ گزشتہ سات سو سال کے طویل عرصے میں مسلمان حکومتوں کی سر پرستی کے با وصف کسی بزرگ کے قلم سے ایسی ایک طبعِ زاد تصنیف بھی نہ نکلی جس کو ہم آج دنیا کے سامنے فخر سے پیش کرسکیں۔ اس “لوچہ زُہاد” سے اگر کوئی ثابت نکلا ہے تو وہی “رندانِ قدح خوار” جن کا شعری کلام ہنوز زندہ ہے۔ تاریخ کی کتابیں بے شمار لکھی گئیں لیکن ان کو لکھنے والے بھی فلسفہ تاریخ سے بابلد تھے۔ وہ وقائع نویس ہیں نہ کہ مورخ۔ ان کو ابنِ خلدون کی ہوا تک نہیں لگی ہے۔ کیا عجیب کہ اُنھوں نے ابنِ خلدون کا نام بھی نہ سنا ہو۔
شاہ عالم نے دیوانی اختیارات کمپنی کو سونپتے وقت چوں کہ یہ شرط رکھ دی تھی کہ صوبوں کے نظم و نسق میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ یعنی دفتری زبان فارسی ہوگی اور عدالتوں کا پرانا نظام بھی بدستور قائم رہے گا لہذا گورنر جنرل وارن ہسٹینگز(1774ء۔1785ء) کو ایسے تعلیم یافتہ مسلمانوں کی فوراً ضرورت پڑی جو ملکی قوانین سے بخوبی واقف ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنی یادداشت میں لکھا کہ:
” ہماری پالیسی ہے کہ دیوانی اور فوجداری کی اہم اسامیوں پر اور پولیس کے عہدوں پر مسلمانوں کو مقرر کیا جائے۔ یہ فرائض عربی اور فارسی زبانوں او ر اسلامی قوانین کی ٹھوس اور جامع لیاقت ہی سے ادا ہو سکتے ہیں۔ مگر یہ علوم اور علما آہستہ آہستہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔۔۔۔۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسلم اقتدار کے زوال کے بعد مسلمان خاندان تباہ و برباد ہو گئے ہیں اور وہ اپنی اولاد کو تعلیم دینے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے۔” 29
وارن ہسٹینگز نے ” ان اسباب کی بنا پر 1781ء میں مدرسہ عالیہ (کلکتہ مدرسہ) قائم کیا تاکہ مسلمانوں کو نظم و نسق میں شرکت کا پورا پورا موقع ملے۔” اس نے ضلع 24 پرگنے کی کچھ آراضی بھی مدرسے کے مصارف کے لیے مخصوص کردی۔
وارن ہسٹینگز ہندوستان میں عرصے سے مقیم تھا۔ وہ فارسی زبان پر پورا عبور رکھتا تھا اور مشرقی علوم والسنہ کا بڑا دل دادہ تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ برطانوی طرزِ حکومت اور ہندوستانی تہذیب میں کسی نہ کسی طرح مفاہمت اور ہم آہنگی پیدا کی جائے تاکہ کمپنی کو اپنے مقاصد کے حصول میں دشواری نہ ہو۔ اُن دنوں اتفاق سے کمپنی کے اعلیٰ عہدے داروں میں بھی ایک حلقہ ایسا تھا جو وارن ہسٹینگز کے خیالات سے اتفاق کرتا تھا اور مشرقی علوم اور زبانوں سے گہری دل چسپی رکھتا تھا۔ مثلاً سرولیم جونس جج سپریم کورٹ، سرچارلس وِل کِنس، نَے تَھے نیل ہال ہیڈ، سرجان شور جو بعد میں گورنر جنرل ہوا، فران سِس گلیڈون، جان کارناک، جان گِل کرسٹ، جوناتھن ڈن کن اور ولیم چَیم برس وغیرہ۔
سرولیم جونس 1783ء میں سپریم کورٹ کا جج ہو کر کلکتہ آیا اور دس سال بعد 47 سال کی عمر میں وہیں وفات پاگیا۔ اس نے ہندوستان آنے سے پہلے ہی عبرانی، یونانی، لاطینی، عربی، فارسی، فرانسیسی، ہسپانوی، اطالوی، جرمن، ترکی اور چینی زبانوں میں مہارت حاصل کرلی تھی۔ یہاں آکر اس نے سنسکرت بھی سیکھ لی اور اپنے لسانی نظریوں کی بدولت دنیا میں بڑا نام پیدا کیا (اس نے زبانوں کے تقابلی مطالعے سے یہ ثابت کیا کہ سنسکرت فارسی اور یورپین زبانیں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں) اس نے فقہ کی کتاب “السر آجیہ” اور دھرم شاستر کا انگریزی میں ترجمہ شائع کیا اور 1784ء میں ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال قائم کی جو اب تک موجود ہے۔ سوسائٹی کا مقصد اس کے بقول “انسان اور نیچر اور نیچر جو کچھ ایشیا میں پیدا کرتا ہے اور انسان جو کچھ محنت سے تخلیق کرتا ہے اس کا مطالعہ اور تحقیق تھا۔” 30
سر چارلس وِل کنس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے بنگالی، اردو اور ناگری کے ٹائپ بڑی محنت و کاوش سے خود تیار کیے۔ فورٹ ولیم کالج کی اردو کتابیں اسی کے بنائے ہوئے نستعلیق ٹائپوں پر چھپتی تھیں۔ سرچارلس اور دوسرے مستشرقین نے جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا، ادب، گرامر، لغت، قانون، تاریخ، فقہ اور مذہب کی بہ کثرت کتابیں فارسی، عربی اور سنسکرت سے انگریزی میں ترجمہ کیں اور یہاں کے معاشرتی حالات کے بارے میں انگریزی میں طبع زاد کتابیں بھی لکھیں۔
وارن ہسٹینگز اور سر ولیم جونس وغیرہ کی مشرقی علوم اور زبانوں سے دل چسپی فقط کمپنی کی انتظامی ضرورتوں کا تقاضا نہ تھی بلکہ یہ دل چسپی اٹھارویں صدی کے انقلابی عہد میں اہلِ مغرب کا مزاج بن گئی تھی۔ پرنگالی، برطانوی، فرانسیسی کمپنیوں کی تجارتی سرگرمیوں کے تذکروں نے مشرقی منڈیوں کی تلاش میں ان کمپنیوں کے گماشتوں کی دوڑ دھوپ کی داستانوں نے، سیاحوں اور طالع آزماؤں کے سفر ناموں، مشرق کی دولت مندی کے چرچوں نے اور یہاں کی پُر اسرار تہذیب کی جھوٹی سچی حکایتوں نے مغرب کے دلوں اور دماغوں کو مسحور کردیا تھا۔ فارسی کی تقلید میں گوئٹے کا ” دیوان” شیلی کی ” اسلام کی بغاوت” بائرن کی نظمیں، سوئفٹ کا ” گلی ورکاسفر” (1726ء) رابن سن کروسو کے تجربات، رمبراں اور گویا کی تصویریں، والٹیئر کے افسانے اور فرانسیسی روشن خیالوں کی تصنیفات میں اسلامی مفکرین کی تحسین و تعریف غرضیکہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا یورپ والوں کو ایک نئی دنیا ایک نئی حقیقت کا انکشاف ہوگیا ہے۔ وارن ہسٹینگز، سرولیم جونس اور کمپنی کے بیش تر حکام اسی مشرق زدہ ذہنیت کے پروردہ تھے۔ اٹھارویں صدی میں کمپنی کی انتظامی پالیسی پر انھیں عناصر کا غلبہ رہا۔
لیکن ان ” اورینٹلسٹوں” کے مقابل کمپنی کے ملازمین میں ایک حلقہ ان افراد کا بھی تھا جو ہندوستانیوں کو انگریزی زبان اور ولایتی تہذیب کے ذریعے ” مہذب” بنانے پر مُصر تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہاں برطانوی قوانین نافذ ہوں، یہاں کی سرکاری زبان انگریزی کردی جائے اور اسکولوں میں انگریزی پڑھائی جائے۔ ان خیالات کا اظہار سب سے پہلے کمپنی کے ایک افسر چارلس گرانٹ نے کیا۔ اس کی رائے میں ” سماجی برائیاں اور اخلاقی خرابیاں نتیجہ میں گہری جہالت او ر وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی لا علمی کا اور یہ نقص انگریزی تعلیم ہی سے دور ہو سکتا ہے۔” اس کی بات جب یہاں کسی نے نہ سنی تو اس نے انگلستان جا کر اپنی تجویزیں کمپنی کے ڈائریکٹوں کے رُو برو پیش کیں مگر کمپنی ڈائریکٹر بھی ہندوستانیوں کو انگریزی تعلیم دلوانے کے سخت خلاف تھے چنانچہ 1792ء جب انگریزی کے ٹیچروں کو ہندوستان بھیجنے کی تجویز رکھی گئی تو ایک ڈائریکٹر نے کہا کہ ” ہم اپنی حماقت سے امریکا میں اسکول اور کالج کھول کر ملک کھو چکے ہیں اور اب ہم اس حماقت کو ہندوستان میں دہرانا نہیں چاہتے۔”31
البتہ انگریزی پادری اور انگریزی زبان کے اخبار، جو وارن ہسٹینگز کے سخت مخالف تھے انگریزی زبان کی ترویح و اشاعت کے حق میں تھے۔ پادریوں کا انگریزی زبان میں تعلیم دینے کا تجربہ بمبئی اور مدراس میں کامیاب ہو گیا تھا لہذا اُنھوں نے بنگال میں بھی جگہ جگہ اپنے اسکول کھولے، چھاپے خانے قائم کیے اورتبلیغی کتابیں شائع کرنےلگے۔ اُنھوں نے سی رام پور میں کاغذ سازی کا کارخانہ بھی قائم کیا۔ یہ کاغذ سستا اور اچھا ہوتا تھا اس لیے اخباری ضروریات کے موزوں تھا۔ پادری انگریزی زبان کے ساتھ مغربی علوم کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ مسلمانوں نے جو بجا طور پر انگریزوں سے ناراض تھے اوران کے ہر اقدام کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے مشن اسکولوں میں پڑھنا یا انگریزی سیکھنا گوارا نہیں کیا مگر ہندو لڑکے انگریزی اسکولوں میں پڑھنے لگے۔ یہ تعلیم آگے چل کر ان کے بہت کام آئی اور وہ مسلمانوں پر سبقت لے گئے۔
اخبار کو معاشرے کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے کیوں کہ لوگوں کے سیاسی اور سماجی شعور کی تشکیل میں اخبار بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جابر حکمراں پریس سے ہمیشہ خائف رہتے ہیں اور سب سے پہلے پریس کی آزادی سلب کرتے ہیں۔ ہندوستان میں پہلا اخبار جو انگریزی میں تھا 1780ء ہکی نامی ایک انگریز نے کلکتہ سے شائع کیا تھا۔ اس ہفتہ وار اخبار کا نام “بنگال گزٹ” تھا (اس سے پہلے ایسٹ اندیا کمپنی نے سرکاری طورپر ایک انگریزی اخبار” انڈیا گزٹ” کے نام سے 1774ء میں جاری کیا تھا مگر اس میں فقط کمپنی کی خبریں چھپتی تھیں) ہِکی ایسٹ انڈیا کمپنی اور اُس کے ملازمین کا جانی دشمن تھا اور ان کی سیہ کاریوں اور زراندوزیوں کے قصے خوب نمک مرچ لگا کر بیان کرتا تھا۔ اسی کی پاداش میں وہ دو بار قید ہوا اور بالآخر ملک بدر کردیا گیا۔ بنگال گزٹ کے بعد جلد ہی کلکتہ، بمبئی اور مدراس سے تقریباً ایک درجن ہفت روزہ انگریزی اخبارات شائع ہونے لگے۔ ان اخباروں میں ہندوستان کے علاوہ سمندر پار کی خبریں بھی چھپتی تھیں جو لندن سے آنے والے اخباروں سے نقل کی جاتی تھیں۔ ” انگریزی اخباروں کے اجرا سے ہندوستانیوں میں اخبار بینی کا شوق اور اخبار نویسی کا مذاق پیدا ہوا۔” اور وہ بین الاقوامی حالات سے بھی واقف ہونے لگے ( یادرہے کہ یہ زمانہ انقلابِ فرانس کا تھا)۔
وارن ہسٹینگز اور لارڈ کارنوالس کے زمانے میں اگرچہ اِکا دُکا آزاد خیال انگریز ایڈیٹروں پر سختیاں ہوئیں اور وہ ملک بدر کیے گئے لیکن پریس آزاد رہا مگر لارڈویلزلی نے انقلابِ فرانس کے حالات سے خوف زدہ ہوکر خود اپنے ہم وطنوں کے پریس کی آزادی چھین لی اور 1799ء میں سخت سنسر شپ نافذ کردی۔ انگریز ایڈیٹروں نے بہتیرا احتجاج کیا اور پارلیمنٹ میں سنسر شپ کے خلاف تقریریں بھی ہوئیں مگر سنسر شپ قائم رہی البتہ لارڈ ہسٹینگز (1813ء۔1833ء) نے 1817ء میں سنسر شپ ختم کردی۔ تب ہندوستانیوں کو بھی دیسی زبانوں میں اخبار جاری کرنے کا حوصلہ ہوا۔ سب سے پہلے دیسی اخبار بنگلہ زبان میں نکلے اوران کی تعداد میں بہت جلد اضافہ ہوگیا۔ چنانچہ 1830ء میں کلکتہ سے بنگلہ کے تین روزنامے، ایک دو روزہ، دو تین روزہ، سات ہفت روزہ، دو پندرہ روزہ، ایک ماہانہ پرچے شائع ہوتے تھے۔32
فارسی میں پہلا اخبار 1822ء میں شائع ہوا اور اردو میں ایک سال بعد۔ دل چسپ بات یہ ہے کہ فارسی کے پہلے اخبار ” مراۃ الاخبار” کے مالک و ایڈیٹرراجہ رام موہن رائے اور اردو کے پہلے اخبار ” جامِ جہاں نُما” کے ایڈیٹر و مالک منشی سدا سُکھ دونوں غیر مسلم تھے۔ راجہ رام موہن رائے نے ” مراۃ الاخبار” کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے لکھا تھا کہ انگریزوں کے اخبار تو موجود ہیں مگر
“ان سےوہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو انگریزی سے واقف ہیں لیکن ہندوستان کے سب حصوں کے لوگ انگریزی نہیں جانتے۔ جو انگریزی نے نابلد ہیں وہ یا تو انگریزی دانوں سے اخبار پڑھوا کر سنتے ہیں یا خبروں سے بالکل بے خبر رہتے ہیں۔ اس خیال سے مجھ حقیر کو فارسی میں ایک ہفتہ وار اخبار جاری کرنے کی خواہش ہوئی ہے۔ دیسی برادری کے سب معززین اس زبان سے واقف ہیں۔ اس اخبار کی ذمہ داری لینے سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ عامتہ الناس کے سامنے ایسی چیزیں پیش کی جائیں جن سے ان کے تجربوں میں اضافہ اور ان کی معاشرتی ترقی ہو سکے۔ اربابِ حکومت کو رعایا کا صحیح حال بتلایا جائے اور رعایا کو ان کے حاکموں کے قانون اور رسم و رواج سے آگاہ کیا جائے تاکہ حکمرانوں کو اپنی رعایا کی تکلیفیں دور کرنے کا موقع ملے اور رعایا کی داد رسی ہو سکے۔”33
راجہ رام موہن رائے کمپنی کے عہد میں برصغیر کے سب سے بڑے مصلحِ قوم، عربی فارسی کے عالم اور مغربی تمدن کے پاسدار تھے۔ وہ 24 مئی 1774ء کو رادھا نگر بنگال میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان پانچ پشتوں سے صوبے کے مغل حاکموں سے وابستہ تھا۔ رواج کے مطابق ان کی ابتدائی تعلیم بھی عربی فارسی میں ہوئی۔اعلیٰ تعلیم کے لئے ان کو پٹنہ بھیج دیا گیا جو ان دنوں اسلامی تعلیمات کا بڑا مرکز تھا۔ وہاں اُنھوں نے قرآن شریف، فقہ، اسلامی دینیات اور علمِ مناظرہ پر عبور حاصل کیا نیز ان کو ارسطو کے عربی تراجم اور معتزلہ کی تصانیف کے مطالعے کا بھی موقع ملا ۔ اُنھوں نے صوفیوں کی کتابیں بھی پڑھیں اور وحدت الوجود کے فلسفہ سے اتنے متاثر ہوئے کہ بُت پرستی کی مخالفت ان کی زندگی کا مشن بن گئی۔ اُنھوں نے سولہ برس کے سِن میں ایک کتاب ” تحفتہ الموحدّین” فارسی میں لکھی (دیباچہ عربی میں تھا) اور ہندو بت پرستی پر سخت اعتراضات کیے۔ اتفاق سے کتاب کے مسودے پر ان کے باپ کی نظر پڑی تو وہ آگ بگولہ ہو گئے اور کشیدگی اتنی بڑھی کہ رام موہن رائے کو گھر چھوڑنا پڑا۔ اس کے باوجود رام موہن رائے کو باپ کے جذبات کا اتنا احترام تھا کہ رسالے کو ان کی زندگی میں شائع نہیں کیا۔
رام موہن رائے کو برطانوی اقتدار سے سخت نفرت تھی لیکن کلکتہ میں قیام کے دوران جب ان کو انگریزی قوانین اور طریقِ حکومت کے مطالعہ کا موقع ملا تو اُنھوں نے محسوس کر لیا کہ ” غیر ملکی غلامی کا طوق” انگریزی تعلیم اور مغربی علوم کی تحصیل کے بغیر گلے سے اتار نہیں جا سکتا لہذا اُنھوں نے انگریزی زبان سیکھی جس سے واقفیت کے باعث مغربی علم و حکمت کے دروازے ان پر کُھل گئے۔ وہ پندرہ برس تک کمپنی سے وابستہ رہے مگر 1815ء میں پنشن لے لی اور سارا وقت سماجی کاموں میں صرف کرنے لگے۔ وہ ذات پات کی تفریق، بُت پرستی اور ستی کے بے حد خلاف تھے چنانچہ ہندو مذہب میں اصلاح کی غرض سے اُنھوں نے برہمو سماج کی تنظیم قائم کی اور ہندو معاشرے میں جو برائیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کے خلاف سخت مہم شروع کردی۔
1813ء میں جب پارلیمنٹ نے کمپنی کے چارٹر کی تجدید کی تو ” ادب کی بحالی اور ترقی اور صاحبِ علم ہندوستانیوں کی حوصلہ افزائی اور برطانوی مقبوضاتِ ہند کے باشندوں کو سائنسی علوم سے روشناس کرنے اور ان کو فروغ دینے کی خاطر ایک لاکھ روپے سالانہ کی رقم مخصوص کردی گئی۔ ” مگر کمپنی کے حکام نے دس سال تک اس ہدایت کی جانب کوئی توجہ نہ دی۔ البتہ 1823ء میں جب پہلی بار تعلیمی کمیٹی بنی تو اس نے اٹھارویں صدی کی روایت کے مطابق یہ رقم مشرقی علوم والسنہ پر خرچ کرنا چاہی اور کلکتہ مدرسے کی طرز پر ایک سنسکرت کالج قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ راجہ رام موہن رائے نے اس تجویز کی شدت سے مخالفت کی۔ اُنھوں نے گورنر جنرل لارڈ ایمبرسٹ کے رُو برو جو محضر پیش کیا وہ ترقی پسند ہندوستانی حلقوں کی نئی ذہنیت کی پوری ترجمانی کرتا ہے۔ راجہ رام موہن رائے ُ( راجہ کا خطاب ان کو اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا مگر انگریزوں نے اس خطاب کو کبھی تسلیم نہیں کیا) نے اس تاریخی دستاویز میں لکھا تھا کہ “سنسکرت کالج کے طالب علم وہی دو ہزار برس پرانی دقیانوسی باتیں سیکھیں گے جن میں رعونت آمیز اور کھوکھلی موشگافیوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اگر برطانوی پارلیمنٹ کی منشا ہے کہ یہ ملک اندھیرے میں رہے تو سنسکرت نظامِ تعلیم سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا لیکن حکومت کا مقصد چوں کہ دیسی آبادی کی اصلاح و ترقی ہے لہذا ایسے کسی روشن خیال اور آزاد نظامِ تعلیم کو فروغ دینا زیادہ مناسب ہو گا جس میں ریاضی، نیچرل فلسفہ، کیمسٹری، علم الابدان اور دوسری مفید سائنسیں پڑھائی جائیں۔ مجوزہ رقم سے یورپ کے تعلیم یافتہ لائق اور فاضل استاد ملازم رکھے جائیں اور کالج کو ضروری کتابیں، آلات اور دوسری چیزیں فراہم کی جائیں۔
لارڈ ایمبرسٹ نے راجہ موہن رائے کی یہ تجویزیں مسترد کردیں اور سنسکرت کالج قائم ہو گیا لیکن بعض روشن خیال افراد نے مشنریوں کی مدد سے مغربی طرز کے کئی اسکول اور کالج کھولے اور انگریزی کتابوں کی اشاعت و فروخت کی غرض سے ایک ” اسکول بُک سوسائٹی” بھی قائم کی۔ بُک سو سائٹی نے دو سال کے عرصے میں 31ہزار سے زائد انگریزی کتابیں فروخت کیں جب کہ سرکاری کمیٹی تین برس میں عربی اور سنسکرت کی اتنی جلدیں بھی فروخت نہ کرسکی کہ طباعت کے اخراجات تو الگ رہے گودام کا دو مہینے کا خرچ ہی ادا ہو جاتا۔ برصغیر میں افکارِ تازہ کی نموداگر سب سے پہلے بنگالیوں میں ہوئی تو یہ ان کی صحافتی اور تعلیمی سرگرمیوں ہی کا فیض تھا۔ صرف ظاہر تھا کہ لوگ اندھیرے سے نکلنے کے لیے بے تاب ہیں اور پرانے علوم والسنہ ان کے ذوق کی تسکین کرنے سے قاصر ہیں۔
اسی اثنا میں انگریزوں نے 1803ء میں آگرہ اور دہلی کو بھی فتح کرلیا۔ اکبر شاہ ثانی کو کمپنی سے آٹھ لاکھ سالانہ پنشن ملنے لگی اور دہلی میں برطانوی عمل داری شروع ہو گئی۔ لہذا وہاں بھی انگریزی زبان اور مغربی علوم کا چرچا ہونا قدرتی بات تھی۔ یہ خدمت دہلی کالج نے سرانجام دی۔ دہلی کالج ابتدا میں روایتی طرز کا ایک مدرسہ تھا جس کو نظام الملک آصف جاہ کے بیٹے نواب غازی الدین نے 1792ء میں قائم کیا تھا۔ 1825ء میں کمپنی کی تعلیمی کمیٹی کی ہدایت پر مدرسے کو کالج میں تبدیل کردیا گیا۔ پانچ سو روپیہ ماہانہ امداد مقرر ہوئی اور ایک انگریز مسٹر ٹیلرپو نے دو سَو روپے ماہانہ تنخواہ پر اس کے پرنسپل بنائے گئے۔تین سال بعد دہلی کے ریذیڈنٹ کمشنر سر چارلس مٹکاف کی سفارش پر انگریزی جماعت کا بھی اضافہ ہوگیا۔ مولوی عبدالحق کے بقول کالج میں انگریزی کے اضافے سے ” لوگوں میں بڑی بے چینی پھیلی اور ہندو مسلمان دونوں نے اس کی مخالفت کی۔ دیں دار بزرگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ ہمارے نوجوانوں کے مذہب بگاڑنے اور اندر ہی اندر عیسائی مذہب کے پھیلانے کی ترکیب ہے۔ یہی مشکل بنگال میں بھی آئی تھی لیکن وہاں یہ آندھی اٹھی تو سہی مگر چند ہی روز میں بیٹھ گئی۔ وہاں مخالفت برہمنوں سے شروع ہوئی تھی تو یہاں مسلمان پیش پیش تھے۔۔۔۔ مسلمان طلبا کی تعداد انگریزی شعبے میں اکثر کم رہی34۔ سچ ہے اجداد کے فکری جمود کی سزا اولاد کو کئی نسلوں تک ملتی رہتی ہے۔ مولوی عبدالحق مرحوم دہلی کالج کی روز افزوں مقبولیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ” اگرچہ ابتدا میں انگریزی پڑھنے والوں کی تعداد تین سو تک پہنچ گئی۔ یہ زمانے کی ہوا تھی۔ ” اسی اثنا میں دہلی میں کئی مشن اسکول اور آگرہ اور بریلی میں مشن کالج بھی قائم ہو گئے جن میں مغربی علوم انگریزی زبان میں پڑھائے جانے لگے۔
دہلی کالج خالص سیکولر درس گاہ تھی۔ وہاں ہندو، مسلمان، عیسائی سب کے لیے نصاب ایک ہی تھا۔ کالج کو معلّم متعلّم کسی کے دینی عقائد سے کوئی سروکار نہ تھا۔ نہ کسی مذہب کی طرف داری کی جاتی تھی اور نہ کسی کی دل آزاری۔ انگریزی شعبے میں تو ظاہر ہے کہ انگریزی زبان و ادب اور مغربی علوم ہی پڑھائے جاتے تھے مگر مشرقی شعبے میں بھی روایتی نصاب کے علاوہ اصولِ حکومت و وضعِ قوانین، ضابطہ دیوانی، الجبرا، ہیئت، ریاضیات، پیمائش، حرکیات، میلنکس، سکونیات، کیمسٹری، طبیعات، مساوات، اقلیدس، علم المناظر، اخلاقی سائنس، تاریخ، جغرافیہ اور نیچرل فلسفے کی تعلیم دی جاتی تھی۔
مشرقی شعبے میں یہ مضامین اردو میں پڑھائے جاتے تھے لیکن ان موضوعات پر اردو میں کتابیں موجود نہ تھیں۔ اس کمی کو پورا کرنے کی غرض سے کالج کے پرنسپل مسٹر تبروس کی تحریک پر (وہ اردو میں شعر بھی کہتے تھے) 1843ء میں وہلی میں “ا نجمن اشاعتِ علوم بذریعہ السنئہ ملکی” کا قیام عمل میں آیا۔ اس انجمن کا مقصد مغربی علوم کی کتابوں کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ یا خلاصہ تیار کرنا تھا۔ مولوی عبدالحق مرحوم نے انجمن کے شائع کردہ تراجم و تالیات کی جو فہرست دی ہے اس میں متذکرہ بالا تمام موضوعات پر کتابیں شامل ہیں۔ ان کتابوں سے یہ فائدہ ہوا کہ مشرقی شعبے کےطلبا کے علاوہ دوسروں کو بھی جو انگریزی نہیں جانتے تھے مغربی افکار سے واقفیت کا موقع ہاتھ آگیا۔
دہلی کالج کے ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ اسی درس گاہ کی بدولت شمالی ہند کے مسلمان پہلی بار جدید مغربی علوم سے باقاعدہ طور پر روشناس ہوئے اور کالج کے اساتذہ اور طلبا نے مغربی علوم کی کتابیں اردو میں ترجمہ کر کے ثابت کردیا کہ اردو میں اجنبی خیالات کے اظہار کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ کالج کی ان خدمات کو سراہتے ہوئے مولوی عبدالحق مرحوم لکھتے ہیں کہ ” یہی وہ پہلی درس گاہ تھی جہاں مغرب و مشرق کا سنگم قائم ہوا۔ اس ملاپ نے خیالات کے بدلنے، معلومات میں اضافہ کرنے اور ذوق کی اصلاح میں جادو کا کام کیا اور ایک نئی تہذیب اور نئے دور کی بنیاد رکھی اور ایک نئی جماعت ایسی پیدا کی جس میں ایسے پختہ، روشن خیال اور بالغ نظر انسان اور مصنف نکلے جن کا احسان ہماری زبان اور ہماری سوسائٹی پر ہمیشہ رہے گا۔” کالج کے اساتذہ میں مولوی امام بخش صہبائی، مولوی سبحان بخش، شمس العلما ڈاکٹر ضیاء الدین سائنس کی کتابوں کے مولف ماسٹر رام چندر ، ماسٹر پیارے لال (جو غالب کے دوست اور قصصِ ہند، تاریخِ انگلستان، دربارِ قیصری وغیرہ کے مصنف اور رسالہ اتالیفِ پنجاب لاہور کے ایڈیٹر تھے) اور شمس العلما مولوی ذکااللہ اور طلبا میں جنھوں نے اردو ادب میں شہرت پائی ڈپٹی نذیر احمد، مولوی محمد حسین آزاد، مولوی کریم الدین مصنف تعلیم النسا، گلستان ہند، تذکرہ شعرائے ہند، تذکرۃ النسا اور میرناصر علی ایڈیٹر صلائے عام قابلِ ذکر ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کا تو قول تھا کہ
” معلومات کی وسعت، رائے کی آزادی، ٹالریشن (درگزر) گورنمنٹ کی سچی خیر خواہی، اجتہاد، اعلیٰ بصیرۃ یہ چیزیں جو تعلیم کے عمدہ نتائج ہیں اور جو حقیقت میں شرطِ زندگی ہیں ان کو میں نے کالج ہی میں سیکھا اور حاصل کیا اور میں اگر کالج میں نہ پڑھتا تو بتاؤں کیا ہوتا؟ مولوی ہوتا، تنگ خیال، متعصب، اکھل کھرا، اپنے نفس کے احتساب سے فارغ، دوسروں کے عیوب کا متجسس، برخود غلط؎
ترکِ دنیا بہ مردُم آموزند
خویشتن سیم و غلہ اندوزند
(دوسروں کو ترکِ دنیا کی تعلیم دیتے ہیں اور خود دولت اور غلہ جمع کرتے رہتے ہیں) مسلمانوں کا نادان دوست، تقاضائے وقت کی طرف سے اندھا بہرا۔
صم بکم عمی فھم لا یرجعون، مااصابتی من حسنۃ فی الدنیا فمن الکالج (دین اور دنیا کی جو اچھائیاں میں نے حاصل کی ہیں وہ کالج ہی کا فیض ہیں)
یہ کہنا تو غلط ہوگا کہ انگریزی زبان اور مغربی علوم کی تعلیم سے عام مسلمانوں کی ذہنیت بدل گئی یا وہ مغربی تہذیب و تمدن کے گرویدہ ہو گئے البتہ ایک حلقہ ضرور پیدا ہوا جو صدقِ دل سے محسوس کرتا تھا کہ اسلام کو مغرب کے سیکولر علوم اور سیکولر اداروں سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور یہ کہ عزت و آبرو سے جینا ہے تو پرانی ڈگر کو ترک کر کے اپنی طرزِ زندگی اور طرزِ فکر میں اصلاح کرنی ہوگی۔
اسی دوران میں کمپنی کے کردار اور اس کی حکمتِ عملی میں بھی انقلاب انگیز تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اب وہ ایک سامراجی طاقت تھی جو دو تہائی ہندوستان پر قبضہ کر چکی تھی اور بقیہ علاقوں پر تسلط جمانے کی فکر میں تھی لہٰذا کمپنی کو اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کی خاطر یہ طے کرنا تھا کہ اس وسیع و عریض سلطنت کا نظم و نسق کن اصولوں پر استوار کیا جائے۔ قوانین کی نوعیت اور عدالتوں کا نظام کیا ہو، حکومت کی سرکاری زبان کون سی ہو، اسکولوں میں ذریعہ، تعلیم فارسی ہو انگریزی اور نصابِ تعلیم مشرقی ہو یا مغربی۔ کمپنی کے اعلیٰ حکام ان دنوں دو صفوں مین بٹ گئے تھے۔ بالآخر بڑی جرح و بحث کے بعد لارڈ میکالے کی تجویز منظور ہوئی جو کٹّر مغرب نواز تھا اور گورنر جنرل لارڈ ولیم بنٹنک نے 1835ء میں فیصلہ صادر کیا کہ حکومت کی سرکاری زبان آئندہ فارسی کے بجائے انگریزی ہو گی البتہ دفتروں اور عدالتوں میں دیسی زبانوں میں بھی لکھا پڑھی کی اجازت ہوگی۔ ملازمتوں پر ترجیح انگریزی دانوں کو دی جائے گی، اسکولوں اور کالجوں میں ذریعہ تعلیم انگریزی ہوگی اور طلبا کو انگریزی ادب اور مغربی علوم پڑھائے جائیں گے۔ مغلیہ عہد کا قانونِ ضابطہ فوجداری تین سال قبل ہی منسوخ کردیا گیا تھا اور اس کی جگہ برطانوی قانون نافذ ہو گیا تھا۔ لارڈ میکالے پادریوں کی تبلیغی سرگرمیوں کے بھی خلاف تھا۔ اس کی رائے تھی کہ جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے حکومت کو کسی مذہب کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے بلکہ بالکل غیر جانب دار رہنا چاہیے لہٰذا طے پایا کہ سرکاری اور امدادی درس گاہوں میں تعلیم سیکولر ہوگی۔
سرکاری درس گاہوں میں تعلیم کو سیکولر کردینے کی پالیسی کو ہندو مسلمان دونوں فرقوں کے روشن خیال حلقوں نے سراہا چنانچہ سر سید احمد خان نے ” مذہب اور عام تعلیم” کے عنوان سے جو مضمون 1871ء میں شائع کیا اس میں وہ حکومت کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ۔
” ہندوستان میں گورنمنٹ کی رعایا مختلف مذہب کی ہے اور وہ خود ان سے مختلف مذہب رکھتی ہے اور اس سبب سے وہ کسی قسم کی مذہبی تعلیم کو شامل نہیں کرسکتی تھی۔ ہم نہایت سچے دل سے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جس قدر نا طرف دار طریقہ تعلیم کا اور مذہبی خیالات سے بچا ہوا اور اچھوتا اختیار کیا ہے اور جس قدر سعی اور کوشش ہندوستان کی تعلیم میں گورنمنٹ نے کی ہے وہ دونوں بے مثل اور بے نظیر ہیں اور غالباً اس وقت دنیا کے پردے پر اس کی نظیر موجود نہیں ہے مگر اس پر بھی جو امرا عام تعلیم کی ترقی کا مانع ہے اس کا رفع کرنا گورنمنٹ کی قدرت سے باہر ہے۔ وہ یہ کرسکتی تھی کہ اپنے تئیں مذہبی تعلیم سے بالکل علیحدہ رکھے مگر یہ نہیں کرسکتی تی کہ تمام مذاہبِ ہندوستان یا کسی خاص مذہب یا مذہبوں کی تعلیم اختیار کرے” ۔35
مگر کمپنی کی سیکولر پالیسی مخلصانہ نہ تھی بلکہ سیاسی مصلحتوں پر مبنی تھی۔ چنانچہ لارڈ میکالے کی تنبیہ کے باوجود کمپنی پادریوں کی تبلیغی سرگرمیوں کی برابر حوصلہ افزائی کرتی رہی۔ انگریز حکام مشن والوں کی مالی امداد کرتے، ان کو اپنی کوٹھیوں میں وعظ کے لیے بلاتے اور اپنے ملازموں کو پادریوں کی تقریریں سننے پر مجبور کرتے تھے۔ سرسید نے اپنی مشہور تصنیف “اسبابِ بغاوتِ ہند” (1859ء) میں کمپنی کے غیر سیکولر طرزِ عمل پر تفصیل سے لکھا ہے اور واقعات کےحوالے دے کر بتایا ہے کہ کس طرح قحط زدہ یتیم بچوں کو عیسائی بنایا جاتا تھا، کس طرح گورنمنٹ کے تنخواہ یافتہ پادری ہندوؤں اور مسلمانوں کی مقدس شخصیتوں کا ذکر اپنی تقریروں اور تحریروں میں نہایت ہتک اور نفرت سے کرتے تھے اور کس طرح مشن اسکولوں میں بچوں سے امتحان عیسائی مذہب کی کتابوں میں لیا جاتا تھا۔ سرسید نے کلکتہ کے لاٹ پادری ایڈمنڈ کی ایک گشتی چٹھی کا حوالہ بھی دیا ہے جس میں سرکاری ملازمین کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ عیسائی مذہب اختیار کرلیں۔ ” میں سچ کہتا ہوں کہ ان چٹھیات کے آنے کے بعد خوف کے مارے سب کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا۔ پاؤں تلے کی زمین نکل گئی، سب کو یقین ہو گیا کہ ہندوستانی جس وقت کے منتظر تھے وہ وقت اب آگیا۔ اب جتنے سرکاری نوکر ہیں اوّل ان کو کرسٹان ہونا پڑے گا اور پھر تمام رعیت کو۔”36
1857ء کے بعد ہندوستان اگر چہ براہِ راست تاجِ برطانیہ کے زیرِ نگیں ہو گیا مگر حکومتِ ہند کی مشن نواز پالیسیوں میں فرق نہ آیا البتہ ملک کے قوانین اور ضابطوں کو سیکولر بنانے پر زیادہ توجہ دی جانے لگی۔ 1859ء میں ضابطہ دیوانی وضع ہوا۔ دوسرے برس قانون تعزیراتِ ہند اور قانون ضابطہ فوجداری نافذ کیا گیا۔ 1864ء میں دیوانی عدالتوں سے مسلمان قاضی اور ہندو پنڈتوں کو چُھٹی مل گئی اور ہندو مسلم سِول قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے کے فرائض سرکاری مجسٹریٹوں کے سپرد کردیے گئے۔ 1872ء میں قانونِ شہادت نافذ ہوگیا۔صوبوں میں ہائی کورٹ اس سے پہلے قائم ہو چکے تھے۔ یہ تمام قوانین مغرب میں رائج سیکولر اصولوں کی روشنی میں تیار کیے گئے تھے۔
مگر انگریزوں نے ہندوستانی سیاست کو سیکولر خطوط پر ترقی کرنے کا کبھی موقع نہ دیا بلکہ پہلے دن سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین نفاق اور بدگمانیوں کے بیج بونا شروع کردیے۔ ” پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو” ان کی پالیسی کا سنگِ بنیاد بن گیا۔ یہ نئی پالیسی مغلوں کی حکمتِ عملی کی عین ضد تھی۔ مغل حکمرانوں نے اپنی سیاست کی بنیاد ہندو مسلم اتحاد پر رکھی تھی۔ اُنھوں نے دونوں فرقوں کو آپس میں لڑانے کی کبھی کوشش نہیں کی بلکہ ایسے معروضی حالات پیدا کیے جن میں دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کے عقاید و جذبات کا احترام کریں، جو اقدارِ زیست مشترک ہوں ان کو فروغ دیں اور جن اقدار سے آپس میں عداوت یا دشمنی بڑھنے کا اندیشہ ہو ان سے حتی الوسع پرہیز کریں۔ مغلوں نے ان فسادی عناصر کو بھی سختی سے دبایا جو ہندو مسلمانوں کے درمیان ایک خلیج کو بڑھاتے تھے۔ اس کے برعکس انگریزوں نے ایسے معروضی حالات پیدا کیے جن میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مذہبی اختلاف کی خلیج وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ برصغیر میں سیکولرازم کی نشوونما میں رکاوٹ ڈالنے والی دراصل خود حکومتِ برطانیہ کی سیکولر دشمن سیاسی پالیسی تھی۔
(5)
برصغیر میں سیکولر خیالات اپنی نئی شکل می ہرچند کہ جدید طرز کی صنعت و حرفت، مغربی انداز کے نظم و نسق اور مغربی علوم کی انگریزی زبان میں تعلیم کی وجہ سے پھیلے لیکن سیکولر خیالات یہاں پہلے بھی موجود تھے البتہ ان کی نوعیت مختلف تھی کیوں کہ معاشرتی حالات اور فکری تقاضے مختلف تھے۔ مثلاً اردو، فارسی کے کلاسیکی ادب میں بالخصوص شاعری میں جو ہمارے جذبات و احساسات کا آئینہ ہے سیکولر فکرکی روایت بہت پرانی ہے۔ اس طرزِ فکر کے ہدف معاشرے کے وہ عناصر تھے جو جبرو استبداد کی علامت بن گئے تھے اور انسان دشمنی، تعصب اور تنگ نظری کےاظہار میں وہی کردار ادا کرتے تھے جو قرونِ وسطیٰ میں مغربی کلیسا کا تھا۔ ہمارا شاید ہی کوئی شاعر ہو جس نے اسلامی تعلیمات کی پیروی کرنے کے باوصف کو نہ آستین مُلاؤّں کی دراز دستیوں پر، زہادِ زشت خو کی ہوس ناکیوں پر، پیرانِ سالوس کی شعبدہ بازیوں پر، مفتیانِ شرع کی اقتدار پرستیوں پر، محتسبوں کی تردامیوں پر، واعظوں کی لن ترانیوں پر اور فقیہانِ شہر کی ریاکاریوں پر لعن طعن نہ کی ہو کیوں کہ اس دور میں سیکولر خیالات و جذبات کے ابلاغ کی یہی صورت ممکن تھی۔
مگر جس تہذیب و تمدن کا عمل دخل انیسویں صدی میں ہو رہا تھا اس کے مطالبے کچھ اور تھے۔ ان مطالبوں پر مرزا غالب نے دہلی کالج سے بھی پہلے لبیک کہی۔ مرزا غالب (1797ء۔ 1869ء) اُن بیدار مغز اور صاحبِ نظر ہستیوں میں تھے جن کی نگاہیں موت کے ملبوں میں زندگی کے ابھرتے ہوئے آثار دیکھ لیتی ہیں۔ وہ بقول خود اُن ” آزادوں ” میں تھے جن کو ماضی کے مٹنے کا غم ” بیش ازیک نفس” نہیں ہوتا کیوں کہ؎
برق سے کرتے ہیں روشن شمعِ ماتم خانہ ہم
عام خیال یہ ہے کہ غالب میں جدید سیکولر رحجانات کلکتہ کے قیام کے دوران ابھرے جہاں ان کو اپنی پنشن کے سلسلے میں تقریباً دو سال رہنا پڑا تھا (1827ء تا 1829ء) لیکن واقعہ یہ ہے کہ مغرب کا جادو اُن پر بنگال جانے سے پہلے اثر کر چکا تھا البتہ ان کے مغرب نواز طرزِ فکر و احساس میں پختگی کلکتے میں مغربی معاشرت کا مشاہدہ کرنے سے آئی۔ ان کو یقین ہو گیا کہ مشرق کا معاشرتی نظام دم توڑ چکا ہے اور انگریز جو نظام اپنے ساتھ لائے ہیں وہ بڑا توانا اور جان دار ہے۔
مرزا غالب کے گھرانے نے 1803ء ہی میں جب کہ غالب کی عمر فقط چھ سال تھی انگریزوں کی ماتحتی قبول کر لی تھی۔ لارڈ لیک نے آگرہ فتح کرنے کے بعد غالب کے چچا اور سرپرست مرزا نصراللہ بیگ خاں کو چار سَو سواروں کا بریگیڈیر مقرر کردیا تھا اور دوگنے بطور معاش دے دیے تھے۔ مرزا کے نانا بھی میرٹھ میں کمپنی کی فوج میں معزز عہدے پر مامور تھے اور آگرے کے عمائدین میں شمار ہوتے تھے اور مرزا کی شادی بھی لوہار خاندان میں ہوئی تھی جو انگریزوں کا بڑا خیر خواہ تھا۔ غالب نے 1811ء میں جب دہلی میں مستقل سکونت اختیار کرلی تو ان انگریزوں سے راہ و رسم بڑھانے کے زیادہ مواقعے ملے۔ اُنھوں نے مسٹر اینڈ منٹن، مسٹر فریزر اور دوسرے انگریزی حکام سے اگرچہ حصولِ منفعت کی خاطر دوستانہ تعلقات قائم کیے تھے لیکن اس میل جول نے بھی ان کے مزاج و مذاق کو ضرور متاثر کیا۔ اس کے علاوہ معمولی سُوجھ بُوجھ رکھنے والا شخص بھی مغلیہ تہذیب کی زبوں حالی کا موازنہ انگریز حاکموں کی شان و شوکت سے کر کے اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ شمعِ مشرق عنقریب بجھنے والی ہے اور ان تِلوں میں اب تیل نہیں رہا؎
کیا شمع کے نہیں ہیں ہوا خواہ اہلِ بزم
جب غم ہی جاں گُداز ہو، غم خوار کیا کریں
یہ جاں گُدازی ایک معاشرتی نظام کے عالمِ نزع کا المیہ تھی مگر غالب کو موت سے کبھی الفت نہیں ہوئی نہ اُنھوں نے مُردہ پرستی کو کبھی پسند کیا ( مُردہ پرور دن مبارک کارِ نیست)
جو میلانات دہلی میں ہنوز زیرِ تشکیل تھے وہ کلکتہ میں تکمیل پا گئے۔ غالب نے کلکتہ کی آب و ہوا کی جو تعریف کی ہے وہ تو خیر ان کی شاعرانہ ہٹ دھرمی ہے کیوں کہ آب و ہوا کے اعتبار سے کلکتہ ہندوستان کا شاید سب سے خراب شہر تھا اور اب بھی ہے۔ وہاں کی گرمی، حبس، اُمس اور غلاظت کے خیال ہی سے بدن کانپنے لگتا ہے البتہ جس چیز نے غالب کو چکا چوند کردیا ہوگا وہ کلکتہ کی مغربی طرزِ معاشرت تھی، انگریزوں کے ٹھاٹھ باٹھ تھے۔ شہر کی خوش حالی اور گہما گہمی تھی اور ہنستی شور مچاتی زندگی تھی جب کہ دہلی کے اجڑے دیار میں ہر طرف ویرانی اور مفلسی برستی تھی۔ نہ کوئی کاروبار تھا نہ روزگار، پیٹ خالی، جیب خالی اور چہروں پر ہوائی اُڑتی ہوئی۔ غالب جیسا حساس و ذی ہوش شخص زمین و آسمان کے اس فرق کو اگر نہ دیکھتا تو حیرت ہوتی۔ اپنے ایک عزیز علی بخش رنجور کو کلکتہ کی ثنا و صف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
” کلکتہ کیا شہر گُوناگوں و مالا مال ہے کہ چارہ مرگ کے سِوا ہر پیشے کا ہُنر مند وہاں موجود ہے اور تقدیر کے علاوہ جو چاہو بازار میں سستے داموں مل سکتا ہے۔” (فارسی)
اور دہلی واپس آکر کلکتہ کے ایک دوست کو لکھتے ہیں کہ
” کلکتے کی خاک نشینی دوسرے مقام کی تخت نشینی سے بہتر ہے۔ خدا کی قسم۔ بال بچوں کا بکھیڑا نہ ہوتا تو میں کب کا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہیں پہنچ جاتا۔” (فارسی)
فارسی کے ایک قطعے میں ” ساقی بزم آگہی” (ساقی بزمِ عشق نہیں) سے مختف مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ باتوں باتوں میں بنارس اور پٹنہ کا ذکر آتا ہے تو ساقی ان شہروں کی بڑی تعریف کرتا ہے۔”تب میں نے کلکتہ کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا کہ کلکتہ کو آٹھویں اقلیم کہنا مناسب ہوگا ۔ میں نے پوچھا اور وہاں کے آدمی۔ وہ بولا ہر ملک اور ہر فن۔”
حالِ کلکتہ باز جُستم گفت
باید اقلیمِ ہشتمیں گفتن
گفتم آدم بہم رسد دروی
گفت از ہر دیار، ازہرفن
غالب کو اخبار بینی کا شوق بھی کلکتہ کے قیام کے دوران پیدا ہوا۔ ان کے ادراک و آگہی میں اس سے بھی اضافہ ہوا ہو گا۔ کلکتہ سے اُن دِنوں فارسی کے دو ہفت روزہ اخبار نکلتے تھے۔ ایک منشی سدا سُکھ کا “جامِ جہاں نما” دوسرا راجہ موہن رائے کا ” مراۃ الاخبار”۔ جامِ جہاں نما میں تو قتیل کے شاگردوں سے مرزا کی ادبی بحثوں کی رُوداد بھی چھپتی تھی جو غالب کی نظر سے یقیناً گزری ہو گی۔ مراۃ الاخبار اس شخص کے خیالات کا نقیب تھا جو غالب ہی کی طرح موحد تھا اور جس کا کیش بھی ” ترکِ رسوم” تھا۔ کیا عجب کہ وحدت الوجود پر ان کا ایمان مراۃ الاخبار کے مطالعے سے اور مستحکم ہو ا ہوا۔
مرزا غالب نے نثر نویسی کا جو نیا اسلوب اختیار کیا وہ بھی خالص مغربی تھا۔ مقفّا مسجع پیرایہ بیان کے بجائے، جو اس وقت کا عام دستور تھا سہل اور رواں تحریر، مکتوب علیہ کو بے تکلفی سے مخاطب کرنا اور خطوں کا مکالمہ بنا دینا حتیٰ کہ لفافے پر پتہ بھی جدید طریقے پر لکھنا ان سب باتوں میں انگریزوں کے مذاق اور مشرب کا رنگ صاف نمایاں ہے۔ وہ صحیح معنی میں مرد آزاد تھے۔ مذہبی تعصبات سے مُبّرا، رسوم و قیود کی بندشوں سے گریزاں ، رنگ و نسل کی تفریق کے منکر، دینِ بزرگاں کی پیروی سے بے زار، خرد کے گرویدہ اور توہمات سے متنفر، ایسے فراخ دل اور روشن خیال شخص کو مغربی تمدن کی خوبیوں کی تہ تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی ہوگی۔
اُنھوں نے سید احمد خان کی تصحیح کردہ ” آئینِ اکبری” پر جو منظوم تقریط لکھی اس کے مطالعے کے بعد تو غالب کی روشن خیالی کے بارے میں کسی شک و شبہے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ واقعہ 1855ء کا ہے۔ اس وقت تک سید احمد خان کو کمپنی کی ملازمت کرتے سولہ سترہ برس گزر چکے تھے مگر ان کی سوچ ہنوز روایتی تھی۔ تقریظ کی تمہید میں غالب سید احمد خان کی تعریف کرتے ہیں کہ ایک “دیدہ بینا” نے ” کہنگی” کو نیا لباس پہنایا ہے لیکن ” آئینِِ اکبری” کی تصحیح ان کی ” ہمت والا” کے لیے باعث ” ننگ و عار ” ہے ۔ اُنھوں نے اس مشغلے سے اپنا دل بے شک خوش کیا مگر میں ” آئین ریا” کا دشمن ہوں لہٰذا ان کے کام پر آفریں نہیں کہہ سکتا کیوں کہ میں تو تخلیقِ نو کا جویا ہوں اور اب میں ” آئین” سے ہٹ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آنکھیں کھولو اور اس ” دیرِ کہن” میں
صاحبان انگلستان رانگر صاحبانِ انگلش کو اور
شیوہ و اندازِ انیاں رانگر ان کے شیوہ و انداز کو دیکھو
تاچہ آئین ہا پدید آور دہ اند اُنھوں نے کیسے کیسے آئین وضع کیے ہی اور ایسے آئین
آنچہ ہر گز کس نہ دید، آوردہ اند جن کو کسی نے پہلے کبھی نہ دیکھا یہاں لائے ہیں
زیں ہنر منداں ہنر بیشی گرفت ان سے ہنر مندوں نے ہنر کے اصول سیکھے ہیں
سعی بر پیشیناں پیشی گرفت اور اپنے اجداد سے بھی آگے نکل گئے ہیں
حق ایں قوم است “آئیں” داشتن آئین پر عمل کرنا اس قوم کا حق ہے
کس نیارد ملک بہ زیں داشتن کسی اور کو ملک کو اس سے بہتر چلانا نہیں آتا
داد و دانش رابہم پیوستہ اند اُنھوں نے عدل اور دانائی کا مِلا دیا ہے
ہند را صد گو نہ آئین بستہ اند اور ہندوستان کو سَو گنا ملکِ آئین بنا دیا ہے
آتشے کز سنگ بیرون آورند لوگ پتھر سے چنگاری پیدا کرتے ہیں (چمقان کو رگڑکر)
ایں ہنر منداں زخس چو آورند مگر یہ ایسے ہنر مند ہیں کہ تنکے سے آگ نکالتے ہیں (دِیا سلائی)
تاچہ افسوں خواندہ اندانیاں برآب اُنھوں نے پانی پر نہ جانے کیا جادو کردیا ہے کہ
دُور کشتی راہمی راند در آب کہ دھواں کشتی کو پانی میں ہانکتا ہے
کہ دُخاں، کشتی بہ جیحوں می برد بھاپ کبھی جہاز کو سمندر میں لے جاتی ہے
کہ دُخاں، گردوں بہ ہاموں می برد اور کبھی چیزوں کو بلندی سے زمین پر لے آتی ہے
از دُخاں زورق بہ رفتار آمدہ بھاپ کی قوت سے کشتی رفتار پکڑتی ہے اور اس کے سامنے
باد و موج ایں ہر دوبے کار آمدہ ہوا اور پانی کی لہریں دونوں بے بس ہو جاتی ہیں
نغمہ بے زخمہ ازساز آورند یہ لوگ ساز سے بِلا دستانے کے دُھن نکال لیتے ہیں
حرف چوں طائر بہ پرواز آورند اور حروف کو پرندوں کی پرواز عطا کرتے ہیں
ہیں، نمی بینی کہ ایں دانا گروہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ دانا گروہ
در د دم آرند از صد کروہ لفظوں کا پیغام لمحوں میں سو کوس تک پہنچا دیتا ہے (تاربرقی)
می زنند آتش بہ باد اندر ہمی ہوا (گیس) کو ا س طرح آگ دکھاتے ہیں کہ ہوا، انگارے کی طرح دہکنے لگتی ہے(گیس کی روشنی)
روبہ لندن کا ندراں رخشندہ باغ لندن پر نظر ڈالو
شہر روشن گشتہ درشب بے چراغ جو رات کے وقت بِلا چراغ کے جگمگاتا رہتا ہے
کاروبارِ مردمِ ہشیار بیں ہوشیار انسانوں کے کاروبار کو دیکھو
در ہر آئیں صد نو آئیں کارِ بیں ایک آئین میں سینکڑوں نئے آئین کی کارفرمائی دیکھو
پیش ایں آئیں کہ دارد روزگار اس آئین کے آگے
گشتہ آئینِ دگر تقویم پار دوسرے آئین پرانی جنتری کی حیثیت رکھتے ہیں
ہست، اے فرزانہ بیدار مغز؟ اے میرے بیدار مغزعاقل
درکتاب ایں گونہ آئین ہائے نغر کیا تمھاری کتاب (آئینِ اکبری) میں ایسی دانائی کی باتیں ہیں؟
چوں چنین گنج گہر بیند کسے اگر کسی کو موتیوں کا خزانہ دکھائی دے تو
خوشہ زاں خرمن چرا چیند کسے وہ کھلیان میں سے ایک بالی کیوں چنے
مبداءِ فیاض را مشمر نجیل فیض کے سر چشمے کو کنجوس مت جانو
نورمی ریزدر طب ہازاں نخیل خرمے کے درخت سے سورج رسیلے پھل ٹپکاتا ہے
مُردہ پروردن مبارک کارِ نیست مُردہ پروری اچھا مشغلہ نہیں
خود بگو، کان نیز جز گفتار نیس تم خود ہی کہو کہ کیا یہ سب باتیں ہی باتیں نہیں ہیں
اس نظم میں مرزا غالب سید احمد خان کو اشارۃً کناتیہً بھی مغربی تہذیب کو اپنانے کا مشورہ نہیں دیتے۔ ان کو انگریزوں کی پوشاک،خوراک سے کوئی دل چسپی نہیں، نہ وہ صاحبانِ عالی شان کی طرزِ بُود و ماند سے مرعوب ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ اپنی مادری زبان ترک کر کے انگریزی زبان اختیار کرلو اس لیے کہ غالب کو اپنی مشرقی تہذیب پر بڑا ناز تھا اور اُنھوں نے آخر وقت تک اپنی مشرقی قدروں کو بڑی آن بان سے نباہا۔ البتہ وہ ہماری سوچ کا انداز بدلنا چاہتے ہیں۔ وہ ” کہنگی” اور مُردہ پرستی کے سخت دشمن ہیں۔ اپنی مشہور غزل میں جو کلکتہ سے واپسی پر1830ء میں کہی گئی تھی فرماتے ہیں کہ
رفتم، کہ کہنگی زتماشا بر افنگم میں گیا تاکہ زندگی سے کہنگی کو خارج کردوں
در بزمِ رنگ و بُو نمطی دیر افکنم اور اس دنیا میں ایک دوسرا طریقہ رائج کروں
دروّ جدِ اہلِ صومعہ ذوقِ نظارہ نیست زاہدوں کے وجد حقیقت شناسی کے ذوق سے خالی ہیں
ناہید رابہ زمزمہ از منظر افکنم لہٰذا میں اپنے زمزموں سے زہرہ فلک کے اقتدار کو ختم کرتا ہوں
دیر ِ کہن کیا، وہ تو ” قاعدہ آسماں” کو بھی بدل دینا چاہتے ہیں (بیاکہ قاعدہ آسماں بہ گردانیم) فیوڈلزم کی جدید اصطلاح سے ان کے کان اگرچہ آشنا نہیں لیکن کہنگی سے ان کی مرد یقیناً فیوڈلزم کا فرسودہ نظام تھا۔ البتہ وہ مغربی تمدن کے حامی ہیں اور مغرب میں جو نئی نئی صنعتی ایجادیں ہوئی تھیں سید احمد خان کو ان کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئلے اور بھاپ سے چلنے والی مشینیں، تار برقی، گیس، دِیا سلائی وغیرہ لیکن غالب کی نظرمیں ان چیزوں سے بھی زیادہ اہم مغرب کا آئینِ نو یعنی نظامِ مملکت ہے جو عدل و انصاف کے اصولوں پر مبنی ہے۔ اٹھارویں صدی میں سلطنتِ مغلیہ کے زوال کے بعد ملک میں جو طوائف الملوکی، لا قانونیت اور افراتفری پھیلی اس کے پیشِ نظر مرزا غالب برطانیہ کے نافذ کردہ آئیںِ نو کی طرف داری کرنے میں یقیناً حق بہ جانب تھے۔ اس نئے آئین کے آگے آئینِ اکبری کی حیثیت واقعی پرانی جنتری سے زیادہ نہ تھی ۔
سید احمد خان کو غالب کے یہ بے لاگ تنقید پسند نہیں آئی لہٰذا اُنھوں نے تقریظ کو کتاب میں شامل نہیں کیا۔ وہ انگریزوں کے وفادار ضرور تھے مگر ان کے خیالات ابھی تک قدیم دائرے میں محدود تھے اور جو کتابیں اُنھوں نے اس دور میں لکھیں وہ یا تو روایتی انداز کی تھیں یا ایسے مذہبی موضوعات پر رسالے لکھے جو وہابی اندازِ فکر سے متاثر تھے نیز مناظرانہ انداز کے تھے 37۔ سید احمد خان کا یہ اندازِ فکر غدر کے بعد بھی 1862ء تک قائم رہا۔
سید احمد خان(1817ء۔1898ء) دہلی کے ایک ممتاز خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے والد سید متقَی (وفات 1838ء) بادشاہ کے مقربینِ خاص میں تھے۔ ان کے نانا خواجہ فریدالدین (وفات 1828ء) بڑے عالم فاضل بزرگ تھے۔ کمپنی نے ان کو سات سو روپے ماہانہ پر کلکتہ مدرسے کا ناظم مقرر کردیا تھا۔ انگریز ان کی فراست و ذکاوت سے اتنے متاثر تھے کہ اُنھوں نے خواجہ فریدالدین کو دوبار سفارت پر بھیجا، پہلے ایران پھر برما، 1815ء میں اکبر شاہ ثانی نے ان کو وزیرِ مال و خزانہ مقرر کیا مگر درباری سازشوں سے تنگ آکر اُنھوں نے بالآخر استعفیٰ دے دیا۔ سید احمد خان کا بچپن اسی لائق اور مُدبر نانا کے گھر میں گزرا۔ ان کے سوانح نگار کا کہنا ہے کہ سید احمد خان کا آنا جانا شاہی دربار میں بھی ہوتا تھا اور وہیں ” ان کو راجہ رام موہن رائے جیسے عظیم ہندوستانی رہنما کو دیکھنے کا موقع ملا”۔۔۔۔ سید احمد خان اپنے نانا کے تذکرے کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ ” راجہ رام موہن رائے نہایت لائق اور ذی علم اور متین ، مہذب و با اخلاق شخص تھے۔ وہ دِلی میں آئے اور بادشاہ کی ملازمت کی اور ان کو راجہ کا خطاب بادشاہ کی طرف سے دیا گیا اور آخرکار وہ بادشاہ کے وکیل ہو کر لندن بھیجے گئے۔ راقم نے ان کو متعدد بار دربارِ شاہی میں دیکھا ہے (اس وقت سرسید کی عمر 12 ،13 برس سے زیادہ نہ تھی) اور دِلّی کے لوگ یقین کرتے تھے کہ ان کو مذہبِ اسلام کی نسبت زیادہ رحجانِ خاطر ہے۔” 38 راجہ رام موہن رائے کے اِنھیں اوصاف کی شہرت سن کر اکبر شاہ ثانی نے ان کو دہلی بلوایا تھا اور لندن اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا کہ وہ بادشاہ کی پنشن میں اضافے کی کوشش کریں۔ راجہ رام موہن رائے پنشن میں تین لاکھ روپیہ سالانہ اضافہ کروانے میں کامیاب ہوگئے مگر واپسی سےپہلے برسٹل میں بیمار پڑے اور وفات پاگئے۔ ان کی لاش وہیں دریا کنارے نذرِ آتش کردی گئی۔ افسوس ہے کہ ہماری نئی نسل عربی فارسی کے اس عالم، بت پرستی کےے دشمن اور سلطنتِ مغلیہ کے وفادار خادم کے نام سے بھی واقف نہیں البتہ بچوں کی کتابوں میں ہمارے ہیرو کون ہیں؟ احمد شاہ ابدالی، جس ظالم نے سرحد، پنجاب اور سندھ کے مسلمانوں کو درجنوں بار حملہ کر کے لوٹا اور قتل کیا۔
سید احمد خان 1838ء دہلی کے صدر امین کے دفتر میں سر رشتہ دار ہوئے۔ چند ماہ بعد ان کو کمشنر آگرہ کے دفتر میں نائب منشی کا عہدہ مل گیا۔ تین سال بعد وہ مین پوری میں منصف مقرر ہوئے پھر فتح پور سیکری، دہلی، بجنور، مراد آباد، غازی پور، علی گڑھ اور بنارس میں مختلف اعلیٰ عہدوں پر مامور رہے ۔ بجنور میں غدر کے زمانے میں اُنھوں نے انگریزوں کی جان بچانے کی کوشش میں کئی بار اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ مراد آباد میں اُنھوں نے قحط زدگان کی خدمت بڑے خلوص اور خوش اسلوبی سے کی۔ 1863ء میں اُنھوں نے غازی پور میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی بنائی تاکہ مغربی علوم کی کتابوں کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا جائے۔ غازی پور ہی میں اُنھوں نے ایک اسکول کھولا جس میں انگریزی بھی پڑھائی جاتی تھی۔1869ء میں وہ لندن گئے اور وہاں کے طرزِ تعلیم کا بالخصوص آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کے طریقہ تعلیم کا بغور مطالعہ کیا۔ لندن ہی میں اُنھوں نے اپنے خیالات اور منصوبوں کی اشاعت کے لیے ایک رسالہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا اور 1870ء میں لندن سے واپس آتے ہی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ 1873ء میں اُنھوں نے مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم کی خاطر ایک کالج قائم کرنے کی اسکیم شائع کی اور 1875ء میں ایم اے او کالج علی گڑھ میں قائم کردیا۔ دوسرے سال وہ پنشن لے کر علی گڑھ آگئے اور 1898ء وہیں وفات پائی۔
سرسید کو ” تقلیدِ مغربی” کے طعنے دینا ہمارے نام نہاد “جدیدی” ادیبوں کا شعار ہو گیا ہے۔ وہ سرسید کے طرزِ عمل کا ذکر اس حقارت سے کرتے ہیں گویا جدیدی حضرات کو اپنی زندگی مغربی تہذیب اور مغربی خیالات کے خلاف جدو جہد میں گزری ہے اور مغربی تہذیب نے ان کو چُھوا تک نہیں ہے حالانکہ مغربی تہذیب کے گندے انڈے ہی ان کے فکر کی خوراک ہیں۔ ہائی ڈیگر اور کیر کے گارد جیسے پرستار انِ مرگ اور حریفانِ عقل ان کے پیر ہیں اوران کے قلم ایذرا پاؤنڈ اور انزیو، ایلیٹ اور جارج آرویل ، کامیو اور کروچے کی مدح و ثنا کرتے نہیں تھکتے۔ سرسید نے مغرب کی روشن خیالیوں سے رشتہ جوڑا تھا مگر ہمارے یہ بزر جمہر مغرب کی ہر انسانیت دشمن تحریک کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہر ظلمت پرست کو بانس پر چڑھاتے ہیں ۔
سرسید نے مسلمانوں کی اصلاح و ترقی کا اس وقت بیڑا اٹھایا جب زمین مسلمانوں پر تنگ تھی اور انگریز ان کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ وہ توپوں سے اُڑائے جاتے تھے، سُولی پر لٹکائے جاتے تھے،کالے پانی بھیجے جاتے تھے، ان کے گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی تھیں، نوکریوں کے دروازے ان پر بند تھے اور معاش کی تمام راہیں مسدود تھیں۔
سرسید نے اپنا نصب العین کتابوں سے تیار نہیں کیا تھا بلکہ اس کے پیچھے ان کا تیس سال کا وسیع تجربہ اور ہندوستان کے معروضی حالات کا گہرا مطالعہ تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اصلاحِ احوال کی اگر جلد کوشش نہیں کی گئی تو مسلمان ” سائیس، خانساماں، خدمت گار اور گھاس کھودنے والوں کے سوا کچھ اور نہ رہیں گے۔” سرسید نے محسوس کرلیا تھا کہ اونچے اور درمیانہ طبقوں کے تباہ حال مسلمان جب تک باپ دادا کے کارناموں پر شیخی بگھارتے رہیں گے، غیر اسلامی رسوم و رواج کو ترک نہیں کریں گے، توہم پرستیوں ہی کو اصل اسلام سمجھ کر مولویوں کے پیچھے بھاگیں گے اور انگریزی زبان اور مغربی علوم سے نفرت کرتے رہیں گے اس وقت تک بدستور ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ ان کو کامل یقین تھا کہ مسلمانوں کی ان ذہنی اور سماجی بیماریوں کا واحد علاج انگریزی زبان اور مغربی علوم کی تعلیم ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر وہ تمام عمر جدوجہد کرتے رہے۔
سرسید نے حصولِ مقصد کے لیے دو مورچے قائم کیے۔ ایک تنظیمی مورچہ، دوسرا تبلیغی مورچہ، ان کی تنظیمی کوششوں کا شاہکار ایم۔ اے کالج تھا جو ترقی کر کے مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوا اور جس کے فیض سے ہزاروں لاکھوں مسلمان انگریزی زبان اور مغربی علوم سے بہرہ اندوز ہوئے اور اب بھی ہو رہے ہیں۔ اپنے خیالات کی نشر واشاعت اور مسلمانوں کی ذہنی تربیت کی خاطر اُنھوں نے ” تہذیب الاخلاق” جاری کیا جو اپنے وقت کا سب سے با اثر رسالہ تھا۔ اُنھوں نے اپنی پر خلوص سرگرمیوں سے نہ صرف بے شمار ہمدرد پیدا کیے بلکہ انیسویں صدی کے قریب قریب سب ہی ممتاز ادیبوں اور دانش وروں کا علمی تعاون بھی حاصل کر لیا۔ نواب محسن الملک، مولانا شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد اور مولانا حالی جو اردو ادب کے ستون ہیں بزمِ سرسید ہی کے شب چراغ تھے۔
سرسید نے جس جوش اور ولولے سے انگریزی زبان اور مغربی علوم کی حمایت کی اُسی جوش اور ولولے سے عربی مدارس اور مروجہ مذہبی تعلیم کی مخالفت کی اور واضح کردیا کہ فی زمانہ یہ مذہبی تعلیم مسلمانوں کے لیے بے مصرف ہی نہیں مضرت رساں بھی ہے۔ مروجہ مذہبی تعلیم پر تنقید کرتے ہوئےوہ لکھتے ہیں کہ
” اب میں نہایت ادب سے پوچھتا ہوں کہ جو جو کتبِ مذہبی اب تک ہمارے ہاں موجود ہیں اور پڑھنے پڑھانے میں آتی ہیں ان میں سے کون سی کتاب ہے جس میں فلسفہ مغربیہ اور علومِ جدیدہ کے مسائل کی تردید یا تطبیق مسائلِ مذہبیہ سے کی ہو۔ وجودِ سماوات سبع کی ابطال پر جو دلیلیں ہیں ان کی تردید کس کتاب میں لکھی ہے۔ اثباتِ حرکتِ زمین اور ابطالِ حرکت و دَورئی آفتاب پر جو دلیلیں ہیں ان کی تردید کس سے جا کر پوچھیں۔ عناصر اربع کا غلط ہونا جواب ثابت ہوگیا ہے اس کا کیا علاج کریں۔۔۔۔ پس ایسی حالت میں ان (مذہبی) کتابوں کا نہ پڑھنا ان کے پڑھنے سے ہزار درجہ بہتر ہے۔ ہاں اگر مسلمان مردِ میدان ہیں اور اپنے مذہب کو سچا سمجھتے ہیں تو بے دھڑک میدان میں آویں اور جو کچھ ان کے بزرگوں نے فلسفہ یونانیہ کے ساتھ کیا تھا وہ فلسفہ مغربیہ اور علومِ محققہ جدیدہ کے ساتھ کریں۔ تب ان کا پڑھنا پڑھانا مفید ہوگا ورنہ اپنے مُنھ میاں مٹّھو کہہ لینے سے کوئی فائدہ نہیں”۔39
مگر علمائے دین میں اس چیلنچ کو قبول کرنے کی اہلیت ہی نہ تھی کیوں کہ ” کیا مقلد، کیا اہل حدیث سب تقلید کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں اور ان میں مادہ اجتہاد و تحقیق معدوم ہو گیا ہے۔ بس ہر ایک اپنی لکیر پر فقیر ہے اور کولھو کے بیل کی مانند اس حلقے میں چکر کھاتا جاتا ہے جس حلقے میں اس کو آنکھ بند کر کے ہانکا تھا”۔ 40
سرسید کا موقف یہ تھا کہ منقولات کی اندھی تقلید کرنے کے بجائے۔۔۔۔ جو مولویوں کا شیوہ ہے۔۔۔۔ ہم کو اپنے ہر عقیدے ، ہر فکر کو عقل و فہم کی کسوٹی پر کسنا چاہیے کیوں کہ “عقل ہی وہ آلہ ہے جس میں تمام باتوں کی اصلیت کا علم ہوتا ہے اور انسان سچائیوں کی تہ تک پہنچتا ہے۔”41 مگر عقل کو علم کہاں سے فراہم کیا جائے؟ سرسید جو اب دیتے ہیں کہ پرانی مذہبی کتابیں اور درس گاہیں تو اس قابل نہیں البتہ جدید سائنسی علوم سے ہماری عقل کو مناسب غذا مل سکتی ہے کیوں کہ سائنسی سوچ عقل کے مطابق ہے اور قوانینِ قدرت اور مظاہرِ قدرت کی سچی تشریح کرتی ہے۔ سائنس کے انکشافات اور نظریات نے، سائنس کی دریافتوں اور ایجادوں نے کائنات کی اصل حقیقت ہم پر روشن کردی ہے۔ پس ہم کو لازم ہے کہ اپنے عقاید و افکار کا محاسبہ مغربی علوم کی روشنی میں کریں۔ سائنسی علوم سے اُنھوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قوانینِ قدرت کو کوئی ماورائی طاقت نہیں بدلتی نہ ان میں مداخلت کرتی ہے بلکہ دنیا میں جو کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے خواہ اس کا تعلق مادی اشیا سے ہو یا انسانی معاشرے سے اس کے اسباب دنیاوی ہوتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کے دنیاوی مسائل دعا تعویذ، نذر نیاز، منتوں، چڑھاؤں سے یاد درگاہوں کی چوکھٹ چومنے، چلے کاٹنے اور زرپرست پیروں کی جھولیاں بھرنے سے حل نہیں ہوں گے بلکہ ان کی نجات توہمات کے اس طلسم کو توڑنے ہی میں ہے۔ ہم مغربی علوم و افکار اور مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا کر ہی دوسری قوموں کی طرح دنیا میں سر فراز و سُرخ رُو ہو سکتے ہیں۔
مسلمانوں کے روایتی عقاید کی اساس قرآن اور احادیث ہیں مگر سرسید کے علمِ کلام میں احادیث کی گنجائش بہت کم ہے۔ ان کے خیال میں احادیث کی نقل و روایت سے مسلمانوں میں تفرقے پیدا ہوئے اور گمراہیاں پھیلیں۔ وہ اپنی تائید میں حضرت ابوبکررضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ کے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
” حضرت ابو بکر رضی اللہ نے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ تم رسولِ خدا صلعم کی بہت حدیثیں بیان کرتے ہو اوران میں اختلاف کرتے ہو اور تمھارے بعد کے لوگ بہت زیادہ اختلاف کریں گے۔ پس تم رسولِؐ سے کوئی حدیث نہ بیان کیا کرو۔ جو کوئی تم سے کچھ پوچھے تو کہہ دو کہ ہم میں اور تمھارے میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے۔۔۔ کہا جاتا ہے خود حضرت ابو بکر رضی اللہ نے جس قدر حدیثیں جمع کی تھیں وہ جلا دی تھیں۔”
” حضرت عمررضی اللہ نے بھی بہت دفعہ اور بہت لوگوں کو آنحضرتؐ سے حدیثوں کی روایت کرنے سے منع کیا اور کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، یہاں تک کہ ایک دفعہ اُنھوں نے بڑے عالم اور فقیہہ تین صحابیوں کو یعنی ابنِ مسعود، ابو درداء اور ابو مسعود انصاری کو اس لیے کہ وہ آنحضرتؐ سے بہت سی حدیثیں روایت کرتے تھے قید کردیا”۔ 42
اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے سرسید لکھتے ہیں کہ
” اس کے بعد زُہاد اور شائقین فی الخیرات پیدا ہوئے اور اوروں کو بھی زہد و ریاضت و عبادت پر ترغیب دلانے کو اور قیامت کے عذاب کا ڈر جتلانے کو روایاتِ ضعیف اور موضوع کے رواج پر مائل ہو گئے اور چھوٹے چھوٹے اعمال سے جنت الفردوس کا مِلنا اور ادنیٰ ادنیٰ معصیت پر جہنم میں داخل ہونے کا وعظ کرنے لگے۔ یہ سب رطب ویا بس کتابوں میں جمع ہوگیا ہے۔”
سرسید نے قرآنی آیات کی تاویل عقلی اور سائنسی بنیادوں پر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ” خدا کی بات اور اس کا کام ایک ہونا چاہیے۔” 43 ان کے نزدیک ” خدا کا قول یعنی مذہب اور خدا کا فعل یعنی فطرت، موجودات دونوں ایک ہیں۔”44 دونوں میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ قدما نے بھی اسی اصول کی پابندی کی تھی اور موجوداتِ عالم کے جو تصورات ان کے زمانے میں حقائق ثابتہ کا درجہ رکھتے تھے اُنھیں کی روشنی میں قرآن کی تفسیریں لکھی تھیں۔ چوں کہ حقائق ہستی کی جو تفصیلات قرآن میں بیان ہوئیں قریب قریب وہی تورات و انجیل میں موجود تھیں اور عربوں کے عام عقاید بھی وہی تھے لہٰذا ان مفسرین نے آیات قرآنی کے باطنی معنی و مفہوم پر غور کرنے کے بجائے ان کے ظاہری معنی و مفہوم پر اکتفا کی۔ سرسید کا موقف یہ تھا کہ چوں کہ موجوداتِ عالم کے علم نے اب بہت ترقی کرلی ہے اور بیش تر پرانے مفروضات غلط ثابت ہو چکے ہیں لہٰذا ہم کو آیاتِ قرآنی کی تشریح ان نئی معلومات کی روشنی میں کرنی چاہیے۔ اس کے برعکس علمائے دین فرماتے تھے کہ موجوداتِ عالم کی جو تشریح سائنس داں کرتے ہیں وہ قرآن سے ٹکراتی ہے۔ مگر کلام خدا چونکہ غلط نہیں ہو سکتا لہٰذا سائنس کی تشریحات لا محالہ غلط ہیں۔ سرسید نے اس منطق کو تسلیم نہیں کیا ۔ وہ کہتے تھے کہ
موجوداتِ عالم کی سائنسی نشریحیں سچی اور ثابت شدہ ہیں لہٰذا ہم کو کلام خدا کے معنی و مفہوم انھیں سچائیوں سے متعین کرنے ہوں گے۔ چنانچہ انھوں نے کائنات کی تخلیق، آدم و حوا کا، ہبوطِ آسمان، انبیا، وحی اور الہام کی اصل حقیقت، فرشتے، جن اور شیطان، لوح و قلم، نوشتہ تقدیر، میزان و معاد، حشر ونشر، جبرو اختیار، معراج معجزہ اور کرامات، نماز و دعا وغیرہ کی عقلی تشریحیں کیں۔ حضرت موسٰیؑ، حضرت نوحؑ اور دوسرے نبیوں کےقصوں میں جو واقعات قانونِ قدرت کے خلاف معلوم ہوتے ہیں جیسے یدِبیضا، عصا کا اژدہا بن جانا، فرعون کے لشکر کا غرق ہونا، خدا کا موسیٰ سے کلام کرنا، پہاڑ پر تجلی ہونا، گئوسالہ سامری کا بولنا، من و سلویٰ کا اُترنا یا عیسیٰ کا گہوارے میں کلام کرنا، مُردوں کو زندہ کرنا اور اندھوں ، کوڑھیوں کو چنگا کرنا، ان باتوں کی تاویل بھی سرسید نے نئے انداز میں کی۔ قرآن میں چورکی سزا ہاتھ کاٹنا لکھا ہے مگرسرسید احمد خان کہتے تھے کہ یہ سزا لازمی نہیں ہے ” کیوں کہ لازمی ہوتی تو فقہا اس کو مالِ مسروقہ کی ایک خاص مقدار کے ساتھ مشروط نہ کرتے اور نیز صحابہ کے وقت میں متعدد موقعوں پر سارق کو صرف قید کی سزا نہ دی جاتی۔” مولانا حالی نے حیاتِ جاوید میں 51 اُن امور کی نشان دہی کی ہے جن کے بارے میں سرسید نے مروجہ اسلامی عقاید سے اختلاف کیا اور ان کی سائنسی اور عقلی تشریحیں پیش کیں۔
سرسید کی سوچ سیکولر تھی۔ وہ دینی امور کو دنیاوی امورسے الگ کر کے دیکھتے تھے۔ انھوں نے اس موضوع پر اپنی وفات سے کچھ عرصے پہلے ایک مضمون بھی لکھا تھا۔ بحث کی ابتدا وہ توریتِ موسوی سے کرتے ہیں جس میں دنیاوی احکام کثرت سے پائے جاتے ہیں اور یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ” حضرتِ موسیٰ کے تمام دنیوی احکام مثل ایک انسان کے احکام کے ہیں جو بہ صلاح بعض دانش مندوں کے اور بطور انتظام مناسب وقت و حالاتِ قوم کے دیے گئے ہوں” مگر ” بنی اسرائیل نے تمام دنیاوی احکام کو جو درحقیقت مذہب سے کچھ علاقہ نہیں رکھتے تھے مذہب میں شامل کرلیا اور پھر اس کے مقاصد کو چھوڑ کر صرف لفظی معنوں کی پیروی کرنا ٹھیٹ یہودی مذہب قرار پایا”۔ 45
فقہائے اسلام نے بھی دینی اور دنیاوی امور کو آپس میں گڈ مڈ کر کے جو غلطی کی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سرسید لکھتے ہیں کہ” عرب کی تمام قوموں کا یہ طریقہ تھا کہ جس کو شیخ یا سردارِ قوم قرار دیتے تھے، تمام دنیاوی امور میں بھی اس کی اطاعت کرتے تھے اوراسی کے حکم پر چلتے تھے۔ پس بطور قدرتی امر کے ضروری تھا کہ تمام قومِ عرب آنحضرتؐ کو اپنا دنیاوی سردار بھی قرار دیں اور آنحضرتؐ کو بھی مجبوراً دنیاوی سرداری اختیار کرنی لازم تھی مگر جس طرح کہ حضرتِ موسیٰؑ میں دو منصب جدا جدا جمع ہو گئے تھے اسی طرح آنحضرتؐ میں بھی دو جداگانہ منصب جمع تھے۔
” دنیاوی سرداری کے متعلق آنحضرتؐ بھی مثل حضرت موسیٰؑ کے اپنے صحابہ کےمشورے سے اور ضرورت و مصلحتِ وقت کے لحاظ سے احکام صادر فرماتے تھے اور یا تو یہودیوں کی پیروی سے یا اسی لازمی نتیجے سے جس کا میں نے اوپر ذکر کیا آنحضرتؐ نے بھی دنیاوی امور کی نسبت جو کچھ کیا یا فرمایا بطور ربانی احکام کے سمجھا گیا اور لوگوں نے ” وانتم اعلم با مورو نیاکم” کو ایک لخت بھلا دیا۔
” مسلمان عالموں نے قدم بہ قدم یہودیوں کی پیروی کی اور تمام دنیاوی احکام کو جو در حقیقت مذہب سے کچھ علاقہ نہیں رکھتے تھے مذہب میں شامل کرلیا اور پھر یہودیوں کی تقلید سے اس کے مقاصد کو چھوڑ کر صرف لفظی معنوں کی پیروی کرنا ٹھیٹ مذہبِ اسلام قرار پایا”۔46
اس کے بعد سرسید ان علما پر گرجتے برستے ہیں جن کے مذہب میں دو انگل اونچی ازار پہننے سے بہشت ملتی ہے اور دو انگل نیچی پہننے سے دوزخ میں ڈالا جاتا ہے۔ ” غرضیکہ انسانوں کی بد بختی کی جڑ دنیاوی مسائل کو دینی مسائل میں جو ناقابلِ تغیر و تبدل ہیں شامل کرلینا ہے۔” وہ اپنی سیکولر سوچ پر اس سختی سے قائم ہیں کہ کہہ دیتے ہیں کہ ” دنیاوی معاملات کو دینی معاملات میں ملا لینا جنون ہے۔” کیوں کہ ” دینی احکام کا نیچر دنیاوی احکامِ معاشرت سے بالکل مختلف ہے۔۔۔۔ امورِ معاشرت و تمدن جو روز بروز تبدیل ہوتے جاتے ہیں پس وہ داخلِ احکامِ مذہبی نہیں ہو سکتے”۔ 47
اور مضمون کا خاتمہ وہ ان فقروں پر کرتے ہیں کہ ” قرآن کا ہر ایک لفظ احکامِ مذہبی سے علاقہ نہیں رکھتا۔ اگر میں اپنے ہم نام مُلا احمد جونپوری کی تفسیرِ آیاتِ احکام ہی کو تسلیم کرلوں تو صرف پانسو آیاتِ احکام اس میں ہیں اور درحقیقت اتنی بھی نہیں۔ پس دنیاوی امور کا قرآن مجید میں ذکر ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوسکتا کہ دنیاوی معاملات بھی مذہب میں داخل ہیں۔”
سرسید کے مضامین ” تہذیب الاخلاق” میں شائع ہونے لگے تو قدامت پرست حلقوں میں کہرام مچ گیا اور اسلام خطرے میں ہے کی دہائی دی جانے لگی۔ بس پھر کیا تھا سرسید پر ہر سمت سے تہمتوں اور دشنام طرازیوں کے تیر برسنے لگے۔ کسی نے کہا کہ سید احمد خان کرسٹان ہوگیا ہے، کسی نے کہا یہ ملحد، نیچری، کافر اور دجال لائقِ قتل ہے۔ اس کے کالج کے لیے چندہ دینا اور لڑکوں کو وہاں پڑھنے کے لیے بھیجنا ناجائز ہے۔ تہذیب الاخلاق کے جواب میں کئی اخبار نکالے گئے اور اشتہار جاری کیے گئے کہ سید احمد خان سے کوئی نہ ملے نہ ان کے ساتھ کھانا کھاوے اور جو ایسا کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مولویوں نے اس پر بھی اکتفا نہ کی بلکہ مولوی امداد العلی نے ملک کے بڑے برے شہروں کے علمائے دین سے فتوے جمع کیے اور ایک رسالہ ” امداد الافاق برجم اہل النافق بہ جواب پرچہ تہذیب الاخلاق” چھاپ کر تمام ہندوستان میں مفت تقسیم کیا ۔ مولوی عبدالحئی فرنگی محل اپنے فتوے میں لکھتے ہیں کہ
” وجودِ شیطان اور اجنّہ منصوص قطعی ہیں اور منکر اس کا شیطان ہے بلکہ اس سے بھی زائد۔۔۔۔ اور وجودِ آسمان منصوصِ قرآنی ہے، منکر اس کا مبتلائے و سواسِ شیطانی ہے۔ مذہب نیچر خدا جانے کیا بلا ہے۔ ہر متشرع اور متدین کو اس کے قبول سے اِبا ہے۔۔۔ ہر مسلمان کو حق جل شانہ ، اتباعِ شریعتِ محمدیہ پر قائم رکھے اور مذہب نیچر اور مشرب بدتر سے محفوظ رکھے۔ جو شخص محزبِ دین ، ابلیس لعین کے وسوسے سے صورتِ اسلام میں تخریبِ دینِ محمدی کی فکر میں ہے اور بنام تجدیدِ مدرسہ جدیدہ افسادِ شریعت اس کی منظورِ نظر ہے، جو چیزیں کہ اس کے نزدیک موجبِ تہذیب ہیں اہلِ سنت کے نزدیک باعثِ تخریب ہیں۔” 48
اگرچہ دِلّی، رام پور، امروہہ، مراد آباد، بریلی، لکھنو، بھوپال وغیرہ کے ساٹھ عالموں، مولویوں اور واعظوں نے کفر کے فتووں پر دستخط کیے تھے مگر صرف خدا کی طرف سے اس کی تصدیق اور تصویب باقی رہ گئی تھی سو مولوی علی بخش خان نے یہ کمی پوری کردی۔ انھوں نے حجاز جا کر مکّے کے چاروں فقہوں کے چاروں مفتیوں سے سر سید کے خلاف فتویٰ حاصل کیا جس میں ان مفتیوں نے سر سید کے لیے ” ضرب و حبس” کی سزا تجویز کی تھی۔ مدینہ منورہ کے مفتی احناف شیخ محمد امین بابی نے اپنے فتوے میں سر سید کی سزا اور بڑھا دی اور ان کو واجب القتل قرار دے دیا لیکن خیریت گزری کہ سید احمد خان ہندوستان میں تھے۔ اگر عثمانی سلطنت کی رعیت ہوتے تو شاید قتل کر دیے جاتے۔ مولانا حالی حیاتِ جاوید میں لکھتے ہیں کہ مولویوں کے اشتعال دلانے پر بعض سر پھروں نے سرسید کو قتل کرنے کی تیاری بھی کرلی تھی مگر ارادے کو عمل میں لانے کی نوبت نہیں آئی البتہ گالیوں اور دھمکیوں کے خطوط سرسید کے پاس آخر تک آتے رہے۔
سر سید کے سیکولر خیالات کو وہ مقبولیت نصیب نہیں ہوئی جس کی ان کو توقع تھی۔ اس کی بڑی وجہ حالات کی ناسازگاری تھی۔ سیکولر خیالات صنعتی نظام کے ماحول میں جڑ پکڑتے اور بار آور ہوتے ہیں کہ فیوڈل ماحول میں چنانچہ سیکولر خیالات اور اداروں نے کلکتہ، بمبئی اور مدارس میں جہاں صنعتی ماحول تھا نسبتاً زیادہ ترقی کی جب کہ سر سید اُس خطے میں سیکولرازم کی تبلیغ کررہے تھے جو خالصتاً فیوڈل تھا اور جہاں کے مسلمانوں کی فکری اور تہذیبی قدریں بھی فیوڈل تھیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ سیکولرازم کا نازک پودا اس سرزمین سے از خود نہیں اگا تھا بلکہ سات سمندر پار سے یہاں لایا گیا تھا اور لانے والے بھی غیر ملکی آقا تھے جن کی اچھی باتیں بھی لوگوں کو بری لگتی تھیں اور جن کی طرف سے ہر دم یہ خدشہ رہتا تھا کہ؎
ساقی نے کچھ مِلا نہ دیا ہو شراب میں
کالجوں اور اسکولوں میں انگریزی تو مجبوراً پڑھنا پڑتی تھی کہ اس کے بغیر سرکاری نوکری نہیں مل سکتی تھی نہ کارو بار چل سکتا تھا لیکن لوگ مغربی خیالات کو قبول کرنے پر مجبور نہ تھے
مزید برآں سرسید کی تعلیمی پالیسی بڑی ناقص تھی ان کی نظرمیں آکسفورڈ اور کیمبرج مثالی یونیورسٹیاں تھیں۔ جن میں اونچے طبقے کے نوجوان تعلیم پاتے تھے اور بعد میں پارلیمنٹ کے رکن، وزیر، سفیر یا سول سروس کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے تھے۔ سرسید بھی چاہتے تھے کہ ایم اے او کالج کی روش یہی ہو اور مسلمان طلبا وہاں سے نکل کر ڈپٹی کلکٹر، جج اور کپتان پولیس بنیں۔ کامرس، انجینئرنگ اور ڈاکٹر جیسے آزاد پیشوں کی طرف ان کا ذہن کبھی نہیں گیا حتیٰ کہ انھوں نے ٹیچرس ٹریننگ کالج بھی قائم نہ کیا۔ اس فروگزاشت کا سبب ممکن ہے کہ وسائل کی کمی ہو لیکن ہم کو ان کی تحریروں مین بھی صنعتی نظام کی اہمیت اور افادیت کا ذکر نہیں ملتا۔ نہ وہ لوگوں کو فیکٹریوں اور ملیں لگانے کی تلقین کرتے ہیں نہ ان کو تجارت یا ٹیکنیکل علوم و فنون کی ضرورت کا احساس ہے۔ ان باتوں کو اگر کہیں ذکر ہے تو برسبیلِ تذکرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ سرسید نے مغربی تہذیب ہی کو مغربی تمدن سمجھ لیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں نے اگر انگریزی زبان سیکھ لی اور مغربی تہذیب اپنا لی تو ان کے اقتصادی اور سیاسی مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے (مسلمانوں سے ان کی مراد اورنچے اور درمیانہ طبقے کے افراد تھے) اس لحاظ سے وہ مرزا غالب کی فکری سطح تک نہیں پہنچ سکے جنھوں نے سرسید کو مغربی تمدن کو قبول کرنے کا مشورہ دیا تھا اور صنعتی نظام کی خوبیاں بتائی تھیں، انگریزوں کے طرزِ طعام و لباس کی ثنا خوانی نہیں کی تھی۔
برطانوی حکومتِ ہند کی غیر مشروط اطاعت و فرماں برداری سرسید کا مسلک تھی۔ وہ برابر یہی کوشش کرتے رہے کہ مسلمان ملکی سیاست سے دُور رہیں اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو انگریزوں کی ناراضگی کا باعث ہو۔ وہ کالج کے لڑکوں کو بھی سیاسی مسائل میں دل چسپی لینے اور سیاسی بحثوں میں الجھنے سے سختی سے منع کرتے تھے۔ احتیاط کی حد یہ تھی کہ تہذیب الاخلاق کا داخلہ بھی کالج میں بند تھا۔ طرفہ تماشایہ تھا کہ انھوں نے ایک انگریز مسٹربک کو کالج کا پرنسپل مقرر کررکھا تھا جو نہایت قدامت پرست شخص تھا۔ اس کو سرسید کے مزاج میں اوران کی سیاسی پالیسی وضع کرنے میں بڑا دخل تھا۔ غالباً اسی کے مشورے سے سرسید نے مسلمانوں کو ملکی سیاست اور نئے تمدنی دھارے سے الگ رہنے کا مشورہ دیا اور جو سیکولر ادارے نئے ماحول میں نشو ونما پارہے تھے ان میں شرکت سے باز رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علی گڑھ سے انگریزی داں تو کھیپ کے کھیپ نکلے مگر روشن خیال شاذو نادر۔ غالب اکثریت ان لوگوں کی تھی جن کی ذہنیت غلامانہ تھی اور غلامانہ ذہنیت سے روایت پرستی کو تقویت ملتی ہے نہ کہ سیکولرازم کو۔
علی گڑھ تحریک کی ان خامیوں کے باوجود ہندوستان کے تعلیم یافتہ مسلمان سیکولر فکر سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ علمِ سیاستِ مدن کے اصولوں سے پہلی بار واقف ہوئے۔ ری پبلک کیا ہے، جمہوریت کس کو کہتے ہیں، اقتدارِ اعلیٰ سے کیا مراد ہےے، تقسیمِ اختیار کے اعتبار سے ریاست کے عناصر ثلاثہ کون کون سے ہیں، مجلس قانون ساز کے حقوق و فرائض کیا ہیں اور اس کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، حق رائے دہی کیا شے ہے، نمائندہ حکومت کیسے بنتی ہے، قومی حق خودارادیت کے کیا معنی ہیں، وفاقی اور وحدانی ریاستوں میں کیا فرق ہے، صوبائی خود مختاری کی تعریف کیا ہے، بنیادی حقوق کیا ہیں اور کیسے حاصل کیے جاتے ہیں، سیاسی پارٹیاں کیوں اور کیسے تشکیل پاتی ہیں یہ سوالات سیکولر علوم سے آگہی کی بدولت لوگوں کے ذہنوں میں ابھرے اور سیکولر علوم اور سیکولر اداروں کے تجربے ہی نے ان سوالوں کے جواب فراہم کیے۔ نہ وید اور پران نے رہبری کی، نہ توریت و انجیل نے اور نہ امام غزالی اور امام مخرالدین رازی نے۔ سیکولرازم کے نام چڑنے والے ہمارے سیاست داں حضرات یہ محسوس نہیں کرتے کہ ان کے نُطق و لب سے نکلا ہوا ہر سیاسی کلمہ سیکولر فکر ہی کی ترجمانی کرتا ہے ورنہ اہلِ مشرق کے فرشتوں کو بھی ان باتوں کی خبر نہ تھی۔
صورتِ احوال یہ ہے کہ وہی حلقے جو کل تک بڑے فخر سے دعویٰ کرتے تھے کہ ان تصورات کا مخرج و منبع اسلام ہے اور مسلمانوں ہی نے یہ باتیں یورپ والوں کو سکھائیں آج بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی سے اپنے ہی دعوؤں کی تردید کررہےے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ باتیں غیر اسلامی ہیں، اسلام کا اپنا مخصوص سیاسی نظام ہے جس کی اساس امیر کی اطاعت ہے خواہ امیر نے اقتدار بزورِ شمشیر کیوں نہ حاصل کیا ہو اور مجلس شوریٰ کو کسی فردِ واحد نے ہی کیوں نہ نامزد کیا ہو۔ ہم گھوم پھر کر ایک صدی پیچھے پہنچ گئے ہیں جب وائسرائے ہند اپنی کو نسل نامزد کیا کرتا تھا اور سر سید مسلمانوں کو حکومتِ ہند کی اطاعت کا سبق پڑھایا کرتے تھے۔
سیکولر فکر کی جمہوری قدروں کے بارے میں ہم نے ابھی ابھی جو دعوے کیے وہ تاریخی حقیقتوں پر مبنی ہیں چنانچہ مسٹر الطاف گوہر کو بھی ہر چند کہ وہ سیکولرازم کے سخت مخالف ہیں اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ
” سیکولر معاشرے کے ممتاز ادارے، 1۔ وہ مقنّہ ہے جو آزاد اور غیر جانب دار الیکشن کے عمل کے ذریعے وجود میں آئے۔ 2۔ وہ عدلیہ ہے جس کو مرکزی اور خود مختاری مرتبہ حاصل ہو۔3۔ وہ انتظامیہ ہے جو عدلیہ اور عدالتی حاکمیت کی اطاعت کرتی ہو۔ 4۔ وہ پریس ہے جو رائے عامہ کے اظہارو تشکیل کا مقبول حربہ ہے”۔49
موصوف کی رائے میں یہ ادارے سیکولرازم کا ” اعلیٰ نصب العین ہیں۔۔۔ جن کے لیے سیکولر سوسائٹی نے اپنے آپ کو وقف کردیا تھا”۔ مگران کو مغرب کی سیکولر سو سائٹیوں سے شکوہ ہے کہ انھوں نے اپنے نصب العین سے بے وفائی کی بالخصوص مشرق میں جہاں سامراجی طاقتوں نے سیکولر اصولوں پر عمل نہیں کیا۔ اغیار کا گِلہ شِکوہ بجا و درست لیکن آزادی کے بعد پاکستان میں ان اصولوں سے جو بے وفائیاں اپنوں نے کیں ان کا شکوہ ہم کس سے کریں؟ الطاف گوہر صاحب ایک زمانے میں پاکستان کے سیکریٹری اطلاعات اور فیلڈ مارشل ایوب خان کی ناک کے بال تھے۔ ان کے عشرہ ترقی” کے دوران “سیکولر سوسائٹی کے ممتاز اداروں” کو جس بے دردی سے نیست و نابود کیا گیا اس سے مسٹر الطاف گوہر سے زیادہ کون واقف ہوگا۔ ملکی آئین کی منسوخی، مارشل لاء کا نفاذ، اسمبلیوں اور وزارتوں کی برطرفی، شہری حقوق کی ضبطی، اخباروں پر کڑی سنسر شپ، ہزاروں بے قصور افراد کی گرفتاری اور ادیبوں ، دانش وروں اور صحافیوں کے ضمیر کی خریدوفروخت؎
مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا تمھیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو
مسٹر الطاف گوہر نے اپنے ایک مقالے میں مغرب کے اخلاقی اور روحانی انحطاط پر بڑی تفصیل سے تبصرہ کیا ہے۔ ان کی رائے ہے کہ ” سیکولر سوسائٹی اور سیکولر ادارے شکست و ریخت کی حالت میں ہیں۔”50 سرمایہ داری نظام کے داخلی تضاد اور دیوالیے پن کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں الطاف گوہر صاحب نے ان کی ذمہ داری سیکولرازم کے سرتھوپ دی ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ بندہ نواز سیکولرازم کے جن اصولوں کے آپ خود معترف ہیں سرمایہ دار طبقہ اگر ان سے ” غداری” کرتا ہے تو اس میں سیکولرازم کا کیا قصور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مغرب کے اخلاقی اور روحانی انحطاط کا بنیادی سبب ہی یہ ہے کہ وہاں کا سرمایہ داری نظام سیکولرازم سے غداری کررہا ہے۔ اگر زوالِ مغرب کا باعث سیکولر خیالات ہوتے تو وہ اخلاقی یا روحانی خرابیاں جن میں مغرب مبتلا ہے سوشلسٹ ملکوں اور عوامی جمہوریتوں میں بھی عام ہوتیں کیونککہ یہ معاشرے تو زیادہ ہی سیکولر ہیں مگر کیا کسی نے سنا کہ سویت یونین یا چین یا ویت نام یا کیوبا یا ہنگری وغیرہ میں بھی مغرب کے سرمایہ دار ملکوں کی طرح نائٹ کلب جوئے خانے کھلے ہوئے ہیں یا عیاشی کے اڈے قائ ہیں یا عورتیں سڑکوں پر کھڑی اپنے جسم کا سودا کرتی رہتی ہیں یا بیسواؤں کے محلے آبا د ہیں یا غنڈے مدمعاش چرس پی کر راہ گیروں کو لوٹتے مارتے ہیں یا سر مُنڈے لونڈے کالے لوگوں کو چھرے چاقو سے حملے کرتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں اور ان کے گھروں، دکانوں کو آگ لگاتے ہیں ۔ کیا کبھی کسی نے سنا کہ وہاں بھی بینکوں پر دن دہاڑے ڈاکے پڑتے ہیں اور رات کے وقت سنسان سڑکوں پر چلنا خطرناک ہے، کیا کبھی کسی نے سنا کہ سوشلسٹ ملکوں میں بھی جرائم پیشہ گروہ پولیس سے مل کر اپنا کاروبار چلاتا ہے۔ کیا سوشلسٹ ملکوں میں بھی لوگ ذریعہ معاش کی بے یقینی کے باعث ضبطِ تولید پر مجبور ہوتے ہیں۔ کیا وہاں بھی لاکھوں کروڑوں ہٹے کٹے لوگ ذہنی اور اعصابی بیماریوں میں مبتلا ہیں یا نرخ بالا کرنے کی غرض سے گیہوں، آلو اور کافی کے ذخیرے ضائع کردیے جاتے ہیں۔ کیا وہاں بھی کروڑوں بے روزگاروں کی ” محفوظ فوج” جنگ کا ایندھن بننے کی خاطر موجود ہے۔ کیا ان ملکوں میں بھی ہر پانچویں ساتویں برس اقتصادی بحران آتا رہتا ہے اور مہنگائی اور افراطِ زر نے لوگوں کی زندگی اجیرن کردی ہے۔
اگران سوالوں کا جواب نفی میں ہے اور لازماً نفی میں ہوگا تو ہم یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بہ جانب ہوں گے کہ الطاف گوہر صاحب نے مشرق و مغرب کے سرمایہ دار حلقوں سے اپنے گہرے ربط کی وجہ سے اصل مجرم یعنی سرمایہ داری نظام کی نشان دہی سے گریز کیا ہے اورسیکولرازم کو قصور ٹھہرایا ہے۔
مسٹرالطاف گوہر فرماتے ہیں کہ 1۔ سیکولرازم اور اسلام میں کوئی شے مشترک نہیں ہے۔2۔ سیکولرازم اسلام کی مکمل ضد ہے کیوں کہ سیکولرازم خدا، الہام اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتی۔3۔ سیکولرازم کا بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ دنیا میں مادی خوش حالی انسانی مسرت کا اہم ذریعہ ہے۔51
ہم فاضل مضمون نگار سے پوچھتے ہیں کہ جنابِ والا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اورسیکولرازم میں کوئی چیز مشترک نہیں تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام منتخب شدہ مقنّہ کے خلاف ہے یا اسلام آزاد عدلیہ کے خلاف ہے یا اسلام منتخب شدہ انتظامیہ کے خلاف ہے یا اسلام پریس کی آزادی کے خلاف ہے یا اسلام شہریوں کے بنیادی حقوق اور جمہوریت کے خلاف ہے۔ کیوں کہ سیکولرازم کے بنیادی اصول آپ کے بقول یہی ہیں۔اگرآپ کا جواب اثبات میں ہے تو آپ کے اسلام اور سیکولرازم میں واقعی کوئی چیز مشترک نہیں ہے مگر جس اسلام کی آپ وکالت کررہے ہیں وہ تیل کے مالکوں اور ان کے خیمہ برداروں کا اسلام ہو تو ہو عام مسلمانوں کا اسلام ہرگزنہیں ہے۔
جہاں تک خدا، الہام اور آخرت پر ایمان کا تعلق ہے تو عرض یہ ہے کہ سیکولرازم کا دائرہ فکر و عمل مذہبی عقاید سے متصادم نہیں بلکہ الگ ہے۔ سیکولرازم کو کسی فرد ، جماعت یا معاشرے کے مذہبی عقاید سے کوئی سروکار نہیں۔ سیکولرازم کا مسلک وہی ہے جو سر سید کا ہے یعنی دین امور اور دنیاوی امور کے تقاضے اور دائرہ کا ر جدا جدا ہیں لہٰذا نہ ریاست کو اپنے باشندوں کے مذہبی عقاید میں مداخلت کرنی چاہیے اور نہ مذہب کو ریاستی امور میں دخل دینا چاہیے۔
اس کلیے کی بنا پر سیکولر ریاست کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ فرد اور جمعیت کو مذہبی آزادی کی پوری پوری ضمانت دے اور اس بات کا خیال رکھے کہ کوئی گروہ یا طبقہ کسی دوسرے کی مذہبی آزادی کو غصب نہ کرنے پائے۔ سیکولر ریاست میں ہر شخص بِلا لحاظِ مذہب مساوی درجے کا شہری ہوتا ہے۔ سیکولر ریاست کسی شہری کے مذہبی معاملات میں دخیل نہیں ہوتی نہ کسی کو مذہبی عقاید کی پابندی کرنے یا نہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ سیکولر ریاست آئینی طورپر کسی مذہب سے وابستہ بھی نہیں ہوتی نہ کسی مخصوص فرقے کے عقاید کو فروغ دیتی ہے۔ اس تصور کے پیش نظر فرد، ریاست اور مذہب کے مابین رشتوں کی تین جوڑیاں بنتی ہیں۔52
1۔ فرد اور مذہب
2۔ فرد اور ریاست
3۔ مذہب اور ریاست
1۔ فرد اور مذہب پر غور کرتے وقت بقیہ دونوں رشتوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا۔ یہ رشتہ ریاست کے وجود میں آنے سے ہزاروں برس پہلے بھی موجود تھا اور آج بھی دنیا کے بعض گمنام گوشوں میں ایسے قبیلے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی مذہب ضرور ہے مگر ان کی زندگی میں ریاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ان کو نہ ریاست کے وجود کی پروا ہے نہ وہ ریاستی قوانین کے تابع ہیں۔ یہودی مذہب ، دینِ مسیحی اوراسلام کی تاریخ بھی شاہد ہے کہ فرد اور مذہب کا رشتہ ریاست سے منسلک نہیں ہے۔ شریعتِ موسوی اس وقت نازل ہوئی ب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں خانہ بدوشی کی زندگی بسر کررہے تھے اور اسرائیلی ریاستوں کا نام و نشان نہ تھا۔ گوتم بدھ نے چھٹی صدی قبلِ مسیح میں بدھ مت کا پرچار شروع کیا لیکن پہلی بُدھ ریاست تین سو سال بعد اشوکِ اعظم نے قائم کی۔ عیسائی مذہب کی تاریخ بھی یہی ہے۔ چنانچہ پہلی عیسائی ریاست حضرت مسیح کے تین سو سال بعد فلسطین سے سینکڑوں میل دور قسطنطنیہ میں قائم ہوئی۔ خود اسلام کا ظہور کسی ریاست کا مرہونِ منت نہیں بلکہ مکے میں تو جہاں آنحضرتؐ نے اسلام کا اعلان فرمایا اسلام کے دشمنوں کا غلبہ تھا۔ مسلمانوں نے ہندوستان پر سات سو سال حکومت کی لیکن دہلی، یوپی اور بہار میں مسلمانوں کی آبادی 14 فیصد سے کبھی آگے نہ بڑھی۔ اگر اسلام کا دارومدار ریاست کی قوتِ قاہرہ پر ہوتا تو کم از کم شمالی ہند میں ہندو مذہب کا کوئی نام لیوا باقی نہ رہتا۔ انڈونیشیا، ملایا، سری لنکا، برما، تھائی لینڈ اور فلپائن میں مسلمان کروڑوں کی تعداد میں آباد ہیں مگر وہ ریاست کے دباؤ سے تو مسلمان نہیں ہوئے۔ انگریزوں نے یہاں ڈیرھ دو سو سال تک راج کیا لیکن وہ کے فیصد ہندوستانیوں کو عیسائی بنا پائے۔ پس معلوم ہوا کہ مذہب کا دارو مدار ریاست پر نہیں ہے۔ اگر مودودی صاحب اسلام کے لیے ریاست کی قوتِ قاہرہ کو ضروری سمجھتے ہیں تو وہ مذہب اور ریاست دونوں کی تاریخ سے نا واقفیت کا ثبوت دیتے ہیں۔
اگر ہم ریاست اور مذہب کے رشتے سے صرفِ نظرکرلیں تو فرد کی مذہبی آزادی کا تصور نمایاں ہو جاتا ہے۔ ریاست اس رشتے سے بے تعلق ہو جاتی ہے۔ ریاست کے ہر باشندے کو اختیار ہوتا ہے کہ جس مذہب کو چاہے قبول کرے اور جس کو چاہے رد کرے۔ اگر کوئی شخص خدا، الہام اور آخرت پر یقین رکھتا ہے تو شوق سے رکھے۔ ریاست کو اس سے باز پُرس کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ ریاست کسی خاص مذہبی رسم یا مذہبی فریضے کی حمایت یا مخالفت میں قانون نافذ کرنے کی مجاز نہیں ہوتی البتہ اس کو یہ حق ضرور ہوتا ہے کہ امن عامہ کے تحفظ یا حفظانِ صحت کے اصولوں کے پیش نظر مذہبی رسوم کی ادائیگی کے ضابطے مقرر کردے مثلاً حج کے ضابطے، مذہبی جلسوں جلوسوں کی نگرانی یا دل آزار تقریروں، تحریروں کی ممانعت مگر ریاست کو مذہبی تنظیموں پر یا مذہبی عقاید کی تبلیغ و اشاعت پر پابندیاں عاید کرنے کا حق نہیں ہوتا۔
فرد اور ریاست کے رشتے پر غور کرتے وقت ہم کو تیسرے عنصر یعنی مذہب کو نظر انداز کرنا پڑے گا۔ ریاست میں فرد کی حیثیت شہری کی ہوتی ہے اوراس کے شہری حقوق مذہبی عقاید سے متعین نہیں ہوتے۔ ریاست کی نظر میں ہندو، مسلمان، عیسائی، پارسی، شہری ہونے کی حیثیت سے برابر ہوتے ہیں۔ ریاست کسی ایک مذہب کے شہری کو دوسرے مذہب کے شہری پر فقط مذہب کی بنا پر ترجیح نہیں دے سکتی نہ ایسے قانون وضع کر سکتی ہے جس سے ایک مذہب والوں کو فائدہ اور دوسروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ ریاست کسی مذہب سے امتیازی سلوک بھی نہیں کرسکتی نہ ایسا نصابِ تعلیم جاری کرسکتی ہے جس کسی مخصوص مذہب یا فرقے کی جانب داری یا مخالفت مقصود ہو اور نہ کسی فرقے پر کوئی مخصوص ٹیکس لگاسکتی ہے۔
فرد، ریاست اورمذہب کے رشتوں کی شکل ایک مثلث کی ہے جس کا بالائی سرِا افراد کی نمائندگی کرتا ہے اور زیریں گوشے ریاست اور مذہب کی نمائندگی کرتے ہیں ۔
فرد
مذہب ریاست
مذہب کی آزادی کا تعلق فرد سے ہے لہٰذا ریاست کا پہلو اس سے خارج ہے۔ فرد کے شہری حقوق کا تعلق ریاست سے ہے لہٰذا مذہب کا پہلو اس سے خارج ہے لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب ریاست مذہب سے جدا ہو۔ ریاست اور مذہب میں جتنا قریبی تعلق ہوگا فرد کی مذہبی اور شہری آزادیاں اسی نسبت سے متاثر ہوں گی۔ اس کے برعکس مذہب ریاست سے جتنا دُور ہوگا مذہب اور ریاست دونوں کو آزادی سے ترقی کرنے کے اتنے ہی زیادہ مواقع ملیں گے۔
مسٹر الطاف گوہر کے اس الزام کو کہ سیکولرازم کے نزدیک دنیاوی خوش حالی انسانی مسرت کا اہم ذریعہ ہے ہم اقراری مجرم بن کربہ خوشی تسلیم کرتے ہیں مگر مجرموں کے کٹہرے میں ہم اکیلے نہ ہوں گے بلکہ کروڑوں فاقہ کش مسلمان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وہ سب لوگ جن کی دِلی آرزو ہے کہ دنیا میں آرام اور عزت و آبرو کی زندگی بسر کریں مگر جن کے شب و روز روٹی ، روزگار کی تلاش میں گزرتے ہیں، جن کے بچے تعلیم سے محروم ہیں اور جن کے پاس نہ سر چھپانے کی جگہ ہے نہ دوا علاج کے لیے دام ہیں۔ ہماری صفوں میں وہ بزرگ ہستیاں بھی ہوں گی جنھوں نے اپنی زندگی مسلمانوں کی دنیاوی حالت درست کرنے کی کوششوں میں گزار دیں۔ ہمارے ساتھ سرسید بھی ہوں گے اور علامہ اقبال بھی اور مسٹر محمد علی جناح بھی۔
شکر ہے کہ محکوم ملکوں کے مسلمانوں کی سوچ مسٹر الطاف گوہر کی مابعد الطیعیاتی سوچ سے مختلف تھی ورنہ الجزائر اور لیبیا، شام و یمن ، ایران اور انڈونیشیا کبھی آزاد نہ ہوتے نہ پاکستان وجود میں آتاکیوں کہ ان ملکوں میں آزادی کی جنگ مسلمانوں کی دنیا سنوارنے اوران کو خوش حالی اور ترقی کے موقعے فراہم کرنے کے لیے لڑی گئی تھی نہ کہ عاقبت درست کرنے کی خاطر۔ اگردنیاوی زندگی کی مسرت و شادمانی مقصود نہ ہوتی تو آزادی کی کیا ضرورت تھی۔ ہم انگریزوں کے غلام تھے مگر انھوں نے ہم کو شرعی احکام پر عمل کرنے سے کبھی نہیں روکا نہ اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگائی۔ انھوں نے ہم کو خدا، الہام اور آخرت پر یقین رکھنے سے منع نہیں کیا نہ کبھی یہ کہا کہ تم نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور حج کرنا ترک کردو۔پھر مسلمانوں نے تحریکِ پاکستان میں کیوں حصہ لیا؟ پاکستان کیوں بنایا؟
کہا جاتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے۔ یہ شوشہ جماعتِ اسلامی نے چھوڑا ہے جو تحریکِ پاکستان کے سخت خلاف تھی اور پاکستان کو ” نا پاکستان” کہتی تھی۔ چنانچہ جسٹس محمد منیر مرحوم نے اپنی کتاب From Jinnah to Zia میں جماعتِ اسلامی نے اپنے ماضی کے داغ دھونے اور نئی نسل کو (جس تحریک پاکستان کا ذاتی تجربہ نہیں) گمراہ کرنے کی خاطر یہ نعرہ 1953ء میں وضع کیا تھا۔ ورنہ مسلم لیگ کی دستاویزیں اور قائدِاعظم اور تحریک پاکستا کے دوسرے ممتاز رہنماؤں کے بیانات گواہ ہیں کہ تحریکِ پاکستان ایک سیاسی تحریک تھی جو قومی حق خود ارادیت کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی اور جس کا مطالبہ تھا کہ مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کو اپنی خود مختار ریاستیں بنانے کا حق دیا جائے مگر قومی حق خودارادیت مغرب کا خاصل سیکولر نظریہ ہے جو وہاں اٹھارویں صدی میں قومی ریاستوں کے وجود کے دوران وضع ہوا۔ اسی نظریے کے مطابق اٹلی، یونان، جرمنی، فرانس، ہالینڈ، بلجیم اور امریکا غرضیکہ بے شمار مغربی ریاستیں وجود میں آئیں۔ اسی نظریے کے مطابق پہلی جنگِ عظیم کے بع مجلس اقوام نے یورپ ہنگری ، چیکو سلوواکیہ، رومانیہ، بلغاریہ اور یوگو سلاویہ کی نئی ریاستیں قائم کیں اور دوسری جنگِ عظیم کے بعد ایشیا اور افریقہ میں درجنوں قومی ریاستیں بنیں۔ قوموں کے حقِ خود اختیاری کا تصور نہ عیسائی مذہب پیش کرتا ہے اور نہ اسلام۔ اسلام تو اُمت واحدہ کا قائل ہے جو قوم، نسل، رنگ، زبان اور جغرافیائی سرحدوں کی تفریق سے زیادہ وسیع وارفع تصور ہے۔
پاکستان کا تصور خواہ سرسید احمد خان کے ذہن کی تخلیق ہو یا علامہ اقبال اور مسٹر محمد علی جناح کی سوچ کا نتیجہ ، ان میں سے ہر ایک کا مقصد برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی اور ثقافتی خود مختاری تھی۔ انھوں نے مسلمانوں کی دنیاوی فلاح و بہبود کے پیشِ نظر آزاد پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ اسی بنا پر ہم تحریکِ پاکستان کو سیکولر تحریک کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کا لقب ” مفکر پاکستان” ہے۔ وہ اپنے خطبہ صدارت میں جو آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں 1930ء میں الہ آباد میں پڑھا گیا تھا فرماتے ہیں کہ:
” جہاں تک میں مسلم ذہن پڑھ سکا ہوں مجھ کو یہ اعلان کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی کہ مستقل فرقہ وارانہ سمجھوتے کی خاطر ہندوستانی مسلمان کا اگریہ حق تسلیم کرلیا جائے کہ وہ اپنی تہذیب اور روایت کی روشنی میں آزاد اور مکمل ترقی کا مجاز ہے تو وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دے گا۔۔۔۔ میں چاہوں گا کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان ایک ریاست میں ضم کردیے جائیں، خواہ سلطنت برطانیہ کے اندر خود مختاری، خواہ سلطنت سے باہر۔ میری نظر میں کم از کم شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کی تقدیر یہی ہے۔ ہندوؤں کو یہ ڈر نہ ہونا چاہیے کہ ان خود مختار مسلم ریاستوں کے معنی ان میں کسی قسم کی مذہبی حکومت کے قیام کے ہوں گے۔”
اپنے اسی موقف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ” مفکر پاکستان 21 جون 1937ء کو مسٹر جناح کو لکھا تھا کہ ” شمال مغربی ہندوستان اور بنگال کے مسلمانوں کو حق خود ارادیت کی مستحق قوم کیوں نہ سمجھا جائے کیوں کہ ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر دوسری قوموں کا بھی یہی حال ہے”۔ قراردادِ پاکستان اس طرزِ فکر کی آخری شکل تھی۔ چنانچہ مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں 23 مارچ 1940ء کو قوموں کے حقِ خود ارادیت ہی کی بنا پر یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ
” جغرافیائی اعتبار سے ملحق وحدتوں کی اس طرح حد بندی کی جائے کہ جن علاقوں میں، مسلمان اکثریت میں ہیں جیسے ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی منطقوں میں ان کو ملا کر آزاد ریاستوں کی تشکیل کی جائے جن میں شامل ہونے والی وحدتیں خود مختار اور اقتدارِ اعلیٰ کی مالک (ساورین) ہوں”۔
مسٹر جناح نے اپنی تقریروں اور اخباری بیانوں میں مسلمانوں کی قومی انفرادیت کی باربار تشریح کی ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ” ہم ایک قوم ہیں، ہماری مخصوص تہذیب ہے زبان، ادب، آرٹ اور فن ہیں، اسماء و اصطلاحات ہیں، قدریں اور پہچانیں ہیں، قانون و اخلاق کے ضابطے، رواج اور جنتری، تاریخ و روایات اور مذاق اور آرزؤئیں ہیں۔ مختصر یہ کہ زندگی کے بارے میں ہمارا مخصوص نقطہ نظر ہے۔ لہٰذا قانونِ قوم کے ہر قاعدے سے ہم ایک قوم ہیں۔” 53
پاکستان میں سیکولر نظام کے حق میں سب سے وزنی آواز قائدِاعظم کی وہ تقریر تھی جو انھوں نے 11، اگست 1947ء کو آئین ساز اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں کی تھی۔ اس تقریر میں انھوں نے حاضرین سے اپیل ککی تھی کہ وہ اپنے پرانے اختلافات کو بھول جائیں اور ” رنگ ذات اور عقیدے” کے فرق کو نظر انداز کر کے ” اول و آخر پاکستان کے شہری” کی حیثیت سے مل کر کام کریں۔
” ہم کو اسی جذبے کے تحت مل کر کام کرنا چاہیے۔ امتدادِ زمانہ کے ساتھ اکثریتی فرقے اور اقلیتی فرقے کے زاویوں کا فرق مٹ جائے گا۔ کیوں کہ مسلمانوں میں پٹھان ہیں، پنجابی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں اور ہندوؤں میں برہمن، وشنو اور کھتری ہیں اورپھر بنگالی اور مدراسی ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہی کہوں گا کہ ہندوستان کی حصولِ آزادی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی فرق رہا ہے۔اگریہ نہ ہوتا تو ہم کب کے آزاد ہو چکے ہوتے لہٰذا ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اب آپ آزاد ہیں۔ آپ مندر میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ مسجد میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔۔۔۔ آپ کسی مذہب، کسی ذات، کسی عقیدے کے بھی ہوں امورریاست کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ آ پ جانتے ہیں کچھ مدت پہلے انگلستان کے حالات ہندوستان کے موجودہ حالات سے بھی کہیں بدتر تھے۔ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ایک دوسرے کو اذیت پہنچاتے رہتے تھے۔ آج بھی بعض ملک ایسے ہیں جن میں بعض طبقوں کے ساتھ امتیازی برتاؤ ہوتا ہے اورپابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اس عہد میں کام نہیں شروع کررہے ہیں۔ ہم ایسے عہد میں کام شروع کررہے ہیں جب ایک فرقے اوردوسرے فرقے کے درمیان کوئی فرق، کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے۔ہم اس بنیادی اصول کے تحت کام شروع کررہے ہیں کہ ہم سب شہری ہیں اورایک واحد ریاست کے مساوی شہری ہیں۔ انگلستان کے لوگوں کو زندگی کی حقیقتوں سے سابقہ پڑا تھا اور حکومت نے ان پر جو ذمے داریاں عائد کی تھیں ان کو پورا کرنا تھا۔ اور وہ اس آگ میں قدم بہ قدم گزرے۔ آج آپ یہ کہنے حق بہ جانب ہوں گے کہ (وہاں) رومن کیتھولکوں اور پروٹسٹوں کا وجود نہیں ہے۔ جو موجود ہے وہ یہ حقیقت ہے کہ ہر شخص ایک شہری ہے اور برطانیہ عظمیٰ کا مساوی شہری ہے اور وہ سب اپنی قوم کے رکن ہیں۔
” میرا خیال ہے کہ ہم سب کو یہی نصب العین اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور آپ دیکھیں گے کہ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا ہندو، ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے ۔ مذہبی مفہوم میں نہیں کیوں کہ وہ ہر شخص کا ذاتی عقیدہ ہے بلکہ سیاسی معنی میں ، بہ حیثیت ریاست کے شہریوں کے”۔
قائدِ اعظم جب یہ کہتے ہیں کہ امورِ ریاست میں مذہبی عقیدوں کا دخل نہیں ہونا چاہیے تو ظاہر ہے کہ وہ سیکولر ریاست ہی کا مفہوم پیش کررہے ہیں۔ انھوں نے بار بار انگلستان کا جو ذکر کیا ہے تو وہ پاکستانیوں کو یہ بات ذہن نشین کروانا چاہتے تھے کہ جس طرح انگلستان میں مختلف فرقوں کے لوگ آباد ہیں اور اپنے اپنے عقیدوں کی پیروی کرتے ہیں مگر مذہب ریاستی امو رمیں دخیل نہیں ہوتا اسی طرح یہاں بھی مذہب کو ریاستی امور میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور نہ ریاستی امور کا تصفیہ مذہبی بنیادوں پر ہونا چاہیے۔
قائدِاعظم کی سوچ کا انداز سیکولر تھا۔ ان کا آبائی پیشہ تجارت تھا۔ ان کی تعلیم کراچی ، بمبئی اور لندن کے تجارتی شہروں میں ہوئی تھی۔ ان کو جاگیریت اور ملائیت سے دور کا بھی تعلق نہ تھا اور نہ اس خرافات سے ان کا کوئی مفاد وابستہ تھا بلکہ برطانوی طرزِ فکرو سیاست کی لبرل روایتیں ان کا مزاج بن گئی تھیں۔ چنانچہ تحریکِ پاکستان کے دوران انھوں نے اس بات پر بار بار زور دیا تھا کہ پاکستان تھیو کریسی نہیں بلکہ ایک ماڈرن جمہوری ریاست ہوگا۔ اگروہ کچھ دنوں اور جیتے تو شاید سیکولر قدروں کو پامل کرنا آسان نہ ہوتا مگر موت نے ان کو مہلت نہ دی۔
قائدِاعظم کے بعد جو حضرات برسرِ اقتدار آئے جاگیری نظام اور اس کی قدروں سے ان کا بڑا گہرا رشتہ تھا بلکہ وہ خود نواب اور جاگیر دار تھے۔ انھوں نے جمہوریت کو فروغ کی اجازت ہی نہ دی اور نہ خردمندی کی حوصلہ افزائی کی بلکہ مذہب کی آر لے کر نہایت فرسودہ رسوم و توہمات اور رجعت پرست نظریات کی ترویج و اشاعت شروع کردی۔ وہ ملاؤں، پیروں اور سجادہ نشینوں سے ساز باز کرنے لگے۔ عرسوں، میلاد شریف کے جلسوں، عزاداری کی مجلسوں اور قوالی کی محفلوں میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہونے لگی۔ قبرپرستی عام ہوئی اور مزاروں کی آرائش و زیبائش پر لاکھوں روپے خرچ ہونے لگے۔ ملک میں مویشیوں کی شدید قلت تھی پھر بھی جانوروں کے بے دریغ قربانی پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ اخبار، ریڈیو، ٹی وی غرض کہ ابلاغ کے ذرائع اس مہم میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں مصروف ہوگئے ۔ زرعی پیداوار گھٹتی رہی مگر جاگیری نظام کو منسوخ کرکے زمین کاشت کاروں میں تقسیم کرنے کا کسی کو خیال نہ آیا۔ ابتدا میں تو جمہوری آئین اور بنیادی حقوق کا زبان سے اقرار ہوتا رہا لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ تکلف بھی بالائے طاق رکھ دیا گیا اور ملک میں فوجی ڈکٹیٹر شپ قائم ہو گئی۔
بعض حلقوں کا خیال ہے کہ سیکولرازم سوشلزم ہی کا دوسرا نام ہے اور اشتراکی کوچہ گرد اپنے سوشلسٹ نظریوں کو سیکولرازم کے چور دروازے سے داخل کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ اس حقیقت سے کون انکار کرسکتا ہے کہ جدید سیکولرازم اور سائنسی سوشلزم دونوں صنعتی نظام کے بطن سے نکلے ہیں اور دونوں میں بہت سی باتیں مشترک ہیں مثلاً سائنسی اندازِ فکر اور سائنسی طرزِ تعلیم پر اصرار، جاگیری نظام کی مخالفت اور صنعتی نظام کی حمایت ، جمہوری حکومت اور اقتدارِ اعلیٰ کا غیر مابعد الطبیعاتی تصور، شہری حقوق کا احترام، آزادی فکر اور ریاست و مذہب کی خود مختاری وغیرہ۔ مگران مشترکہ اقدار کے باوجود دونوں کے اقتصادی نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہر چند کہ کسی سیکولر ریاست کو سوشلزم کے اقتصادی اصولوں کے اختیار کرنے میں کوئی امر مانع نہیں ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ سیکولرازم کا رحجان عموماً سرمایہ داری نظام کی جانب رہا ہے اس لیے کہا جاتا ہے سیکولرازم دراصل بور ژواجمہوریتوں کا سیاسی نظریہ ہے۔ اگر بینک ، فیکٹریاں، ملیں، کانیں، زمینیں اور صنعتی اور تجارتی کارپوریشن چند افراد کی ذاتی ملکیت ہوں اور سرمایہ دار طبقہ محنت کشوں کی قوت و محنت کا آزادانہ استحصال کرتا رہے تو بھی سیکولرازم کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ سیکولرازم کو نہ محنت کشوں کی طبقاتی جدو جہد سے کوئی دل چسپی ہے نہ ان کو برسرِ اقتدار لانا اس کے لائحہ عمل میں شامل ہے۔ اس کے برعکس سوشلزم دولت آفرینی کے ذرائع کو جن پر استحصالی طبقوں کا قبضہ ہے قومی ملکیت میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ ان کا انتظام محنت کشوں کی چنی ہوئی حکومت اور چنے ہوئے نمائندوں کے سپرد ہو اور معاشرے کی تنظیم اس اصول پر ہو کہ ” جو محنت کرے گا وہ کھائے گا ” یعنی سوشلسٹ معاشرے میں بچوں، بوڑھوں اور بیماروں سے قطع نظر کسی مفت خورے گروہ کی گنجائش نہ ہوگی۔ یہی بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے بیش تر سیکولر ریاستوں کا اقتصادی نظام سرمایہ دارانہ ہے بلکہ بعض ریاستوں کا حاکم طبقہ تو سوشلزم کا شدت سے مخالف ہے۔ مثلاً امریکا، برطانیہ، جنوبی افریقہ، انڈونیشیا اور ترکی وغیرہ۔
سوشلزم کو سیکولرازم کی سپر بھی درکار نہیں ہے۔ سوشلزم کے بازو اتنے قوی ہیں کہ اس کو اپنی ڈیڑھ سو سال کی تاریخ میں سیکولرازم کی بیساکھی لگانے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئی۔ آج آدھی دنیا میں معاشرے اور ریاست کی تعمیر نواگرسوشلسٹ نظریات کے مطابق ہو رہی ہے تو یہ سیکولر ازم کا فیض نہیں بلکہ محنت کشوں کی جدو جہد کا ثمر ہے۔ سوشلزم کے بڑھتے ہوے اخلاقی وقار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بہت سے ملک جو دراصل سوشلسٹ نہیں ہیں وہ بھی خود کو سوشلسٹ کہتے ہیں مثلاً یونان، فرانس، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، شام و عراق، چین اور ہندوستان، برما اور سری لنکا حتیٰ کہ مصربھی۔ آخر ہٹلر کی فاشسٹ پارٹی کا نام بھی تو نیشنل ” سوشلسٹ” پارٹی تھا۔
پاکستان گزشتہ 30،32 برس سے سیاسی اور اقتصادی بحرانوں کا شکارہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ یہاں زندگی کے ہر شعبے میں فیوڈل عناصر اور فیوڈل اقدار کا غلبہ ہے۔ حالانکہ فیوڈلزم مدت ہوئی اپنی افادیت کھو چکا ہے اوراب اس میں دورِ حاضر کے تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت باقی نہیں۔ وہ ایک پیرِ تسمہ پا ہے جس کو گردن پر سے اتارے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب جمہوری اصولوں کو فروغ کا موقع ملے اور معاشرے کی ازسرِ نو تنظیم سیکولر خطوط پر کی جائے۔ اس تاریخی منصب کو ملک کے روشن خیال عناصر عامتہ الناس کے عملی تعاون ہی سے پورا کرسکتے ہیں۔
حوالہ جات و حواشی
1۔ مولانا در خواستی زندگی میں ایک آدھ بار ضرور بیمار پڑے ہوں گے اور کسی ڈاکٹر یا حکیم نے ان کا علاج بھی کیا ہوگا لیکن ان سے اگر عرض کیا جائے کہ حضورِ والا آپ کی شفا یابی کے ذرائع سیکولر تھے تو وہ ہرگز نہ مانیں گے۔
2۔ انسائیکلو پیڈیا بریٹینیکا، جلد 20، ص 264
3۔ ایضاً جلد، 24،ص 521
4۔ایضاً۔ ص 1091
5۔H.A.L. Fisher. History of Europe vol. I London. 1972. P. 186
6۔ ایضاً۔ ص 260
7۔ ایضاً
8۔ Phillip Hitti, History of the Arabs. P. 582.587
9۔ Cambridge History of Islam, vol.11. Cambridge. P 801
10۔ Will Durant. The Age of Faith. P 956
11۔ Amold Toynbee. A Histotian’s Approach to Religion, New York. 1956 p. 184
12۔ خالدہ ادیب خانم، Conflict of East and West in Turkey, Delhi, 1935, pp. 40.42
13۔ Niazi Berkes, Development of Secularism in turkey, Montreal, 1964, p. 33
14۔ خالدہ ادیب ، ص 51
15۔ Cambridge History of Islam, vol1.p. 368
16۔ خالدہ ادیب، ص 154
17۔ نیازی برکس، ص 259
18۔ خالدہ ادیب خانم، ص 163
19۔ خالدہ ادیب خانم، ص 160۔162
20۔ Cambridge History of Islam, Opcit, p.555
21۔ نیازی برکس، ص 262
22۔ نپولین نے 1798ء میں اسکندریہ پر قبضہ کرنے کے بعد جو پہلا اعلان جاری کیا اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اور سورہ اخلاص سے ہوئی۔ پھر مصریوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ ” ہم پر یہ تہمت لگائی جا ریہ ہے کہ ہم آپ کا مذہب برباد کرنے آئے ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ہم آپ کو ظالموں کے پنجے سے آزاد کروانے آئے ہیں۔ میں خدائے واحد کی عبادت کرتا ہوں اور پیغمبر خدا اور قرآن مجید کا احترام کرتا ہوں۔ لوگوں سے کہہ دو کہ فرانسیسی بھی سچے مسلمان ہیں۔ ثبوت یہ ہے کہ انھوں نے روم پر قبضہ کر کے پاپائے روم کی قوت کو خاک میں ملا دیا ہے جو ہمیشہ عیسائیوں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ترغیب دیتا تھا اور ہم نے مالٹا کے عیسائی مہم پسندوں کو جو (صلیبی جنگوں کے وقت سے ) مسلمانوں کے خلاف لڑنے کو خدا کا حکم سمجھتے تھے زیر کرلیا ہے۔ فرانسیسی ہمیشہ سلاطینِ عثمانی کے مخلص دوست اور ان کے دشمن کے دشمن رہے ہیں۔”
23۔انقلاب اور قدامت پرستی، 1923، ضیاء گو کلپ کے خیالات ان کے مضامین کے مجموعے کے انگریزی ترجمے کے ماخوذ ہیں:
Zia Gokalp: Trukish Nationalism and Western Civilization, Londo, 1959.
24۔ Mohammad Iqbal: Reconstruction of Religious Thought in Islam, p. 162
25۔ Dr Ziaul Haq. “ Muslim Religious Education in Indo-Pakistan”. Islamic studies. Islamabad, 1975
26۔ History of Freedom Movemet, vol.11, Karachi, 1960, p. 172
27۔ Dr. Abid Husain: The National Culture of India, Bombay, 1951, p. 71
28۔ برنیٹر، عہد اورنگزیب، ترجمہ محمد حسین، کراچی، 1960ء، ص 231۔232
29۔ منقول ازڈاکٹر ضیاءالحق، ص 279
30۔ S.N. Mukherji, Sir William Joes, Cambridge, 1968, p. 82
31۔ خلیق احمد نظامی، سید احمد خان، نئی دہلی، 1971، ص 12
32۔ W.H. Cary, The Good old Days of Hon’ble John Company, vol,1, simla. 1882 p. 234
33۔ محمد عقیق صدیقی ، ہندوستانی اخبار نویسی ، علی گڑھ، انجمن ترقی اردو، 1957، ص 150
34۔ مولوی عبدالحق ، مرحوم دہلی کالج، کراچی، 1962ء ص 15۔16
35۔ سر سید احمد خان ، مقالاتِ سرسید، لاہور، 1962ء، ص 105
36۔ الطاف حسین حالی، حیات جاوید، ضمیمہ، اسباب بغاوت ہند، لاہور، سن ندارد، ص 902
37۔ خلیق احمد نظامی ، سید احمد خان، ص 25
38۔ مقالاتِ سرسید، جلد 16، لاہور، 1965ء ص 663،6
39۔ ایضاً۔ جلد اول ، لاہور، 1962ء، ص 97۔98
40۔ ایضا۔ ص 273
41۔ایضاً۔ جلد 5، لاہور، 19622ء ص 251
42۔ ایضاً جلد اول، ص 191، بحوالہ تذکرہ الحافظ، جلد اول، ص 3 ، ص 266
43۔ ایضاً۔ جلد اول، ص 98
44۔ ایضا۔ ص 288
45۔ مقالاتِ سرسید، جلد 5، ص 1، 3
46۔ ایضا۔ 3، 4
47۔ ص 2
48۔ منقول ازالطاف حسین حالی، جاوید، ص 269
49۔ Translation From Quran, Lahor, 1975, p. 21
50۔ Altaf Gauhar (ed), The Challenge of Islam, London, 1978, p. 299
51۔ ایضاً۔ ص 299۔ 300
52۔Donald E. Smith , India as a Secular State, Princeton, 1963. P. 5
فرد ، ریاست اور مذہب کے رشتوں کی اس بحث کے لیے راقم مسٹر ڈونلڈ اسمتھ کا ممنون ہے۔
53۔ Gunar Myrdal Asian Drame, vol, 1, London, 1968. P. 233