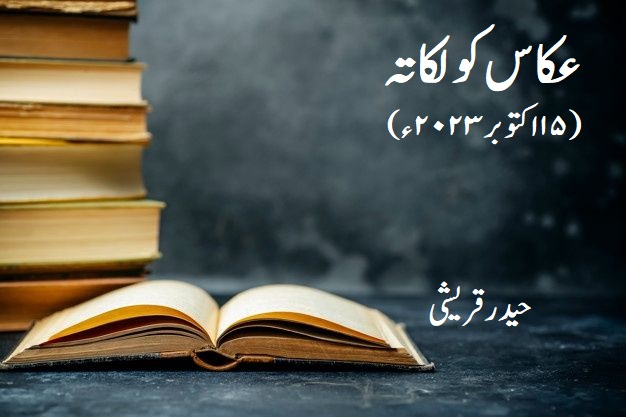یہاں جرمنی میں ایک بار مجھے صوفیانہ خیالات نے پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا۔زندگی کی ہر سرگرمی بے معنی لگ رہی تھی۔جی چاہتا تھاکہ کسی ویرانے میں جا کر اﷲ اﷲ کرتے ہوئے زندگی بسر کروں۔پھر زندگی ہی بے معنی لگنے لگی۔میں نے دنیا کی بے ثباتی پر گفتگو شروع کر دی۔گفتگو گہری اور طویل ہونے لگی تو مبارکہ نے کہا’’ٹھہریں!میں آپ کی شوگر چیک کرتی ہوں‘‘۔۔۔۔جب شوگر چیک کی گئی تو اس کا لیول معمول سے خاصا زیادہ تھا۔شوگر کنٹرول کرنے والی دوا لینے سے حالت بہترہوئی تو زندگی بامعنی اور خوشی سے بھری ہوئی لگنے لگی۔تب میں نے شریر انداز سے مبارکہ سے کہا’’پہلے زمانے میں شوگر کی بیماری کی تشخیص کرنے‘اسے ماپنے اور کنٹرول کرنے کا کچھ پتہ نہ تھا۔شاید اسی وجہ سے بعض شہزادے اپنے محل چھوڑ کر جنگلوںمیں چلے گئے۔بُرا ہو اِن جدید سہولیات کا جن کے باعث میں گوتم بُدھ بنتے بنتے رہ گیا‘‘
خانپور میں بنک کے شعبہ سے وابستہ دوستوں میں ارشد خالد‘ظفر اقبال ماچے توڑ اور صفدر صدیق رضی کا ذکر تو ’’میری محبتیں‘‘میں آچکا ہے۔بنک سے وابستہ ایک اور دوست نجم الحسن نجمی تھے۔شاعر تھے اور خوش باش قسم کے انسان تھے۔رحیم یارخاں کے قریب کے کسی گاؤں میں ایک شاعر عاشق قریشی رہتے تھے۔بہت ہی روایتی قسم کے شاعر تھے لیکن ان کا کمال یہ تھا کہ دھڑا دھڑ اپنے شعری مجموعے چھپوا رہے تھے۔ایک بار نجمی نے میری موجودگی میں اُن سے پوچھا کہ یار!تم اتنے مجموعے کیسے چھپواتے ہو؟۔۔۔عاشق قریشی نے بتایا کہ ارد گرد کے دیہاتوں کے بڑے زمینداروں سے پہلے سے طے کرلیتا ہوں ۔ پھرکتاب کا انتساب دو تین زمینداروں کے نام کرکے ان سے کتاب کی لاگت نکلوا لیتا ہوں اور جو کتاب بِکتی ہے وہ میرا منافع ہوتا ہے۔
’’ہائیں!تمہارے مجموعے بِکتے بھی ہیں؟‘‘نجمی نے مضحکہ اُڑانے والے انداز سے پوچھا۔
اس پر عاشق قریشی نے بڑی ہی صاف گوئی سے بتایا کہ چھ سات تھانے والوں سے اس کی دوستی ہے۔وہ سب اس سے پچاس‘پچاس جِلدیں لے لیتے ہیںاور تھانے آنے والوں کو تھوپ دیتے ہیں۔جو رقم ملتی ہے ‘آدھی آدھی کرلیتے ہیں۔۔تب نجم الحسن نجمی نے کہا کہ یہ کرامت تو سُنی تھی کہ’’تُوں چوراں نُوں قطب بنانویں‘‘(تم نے اپنی نظر سے چوروں کو بھی قطب بنادیا)لیکن ابے سالے تُونے تو کمال کردیا ’’تُوں چوراں نُوں کتب پڑھانویں‘‘ (تم نے چوروں کو مطالعۂ کتب پر لگا دیا ہے)۔۔۔۔۔(ایک عرصہ کے وقفہ کے بعد آج کل نجم الحسن نجمی سے پھر گہرا رابطہ ہے)
میری دُور کی نظر کمزور ہے۔پاکستان میں میری عینک کا نمبر -3.75تھا۔ایبٹ آباد میں یہ-3.50ہوگیا تھا اور جرمنی آکر چیک کرایا تو عینک کا نمبر-3.25ہو گیا۔تب میں نے بعض قریبی عزیزوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہمیں ہمارے بزرگوں نے زندگی بھر غضّ ِ بصر کی تلقین کر کرکے نظر کمزورکرادی۔لیکن ایبٹ آباد میں لیڈی ٹیچرز کی رفاقت سے اور یہاں جرمنی کے کھلے ماحول سے آنکھوں کا درست استعمال شروع کیا تو ان کی کم ہوتی ہوئی روشنی بحال ہونے لگی ہے۔ویسے یہ بات شوخی کی حد تک ہے وگرنہ ڈاکٹر نے میرے استفسار پر بتایا تھا کہ ایک عمر کے بعد دور کی نظر کا نمبر تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجہ میں نزدیک کی نظر پر اثر پڑتا ہے۔یہ اور بات کہ میری دور کی نظر پہلے سے بہتر ہونے کے ساتھ نزدیک کی نظر بھی خدا کے فضل سے ابھی تک بالکل ٹھیک ہے۔ ۔۔۔۔(لیکن اب ربع صدی کے بعد دوریاں ، نزد یکیا ں سب بے معنی ہو چکی ہیں۔)
بچپن اور لڑکپن میں میرا سب سے پسندیدہ کھیل ’’گُلّی ڈنڈا‘‘ تھا ۔ گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں بھی یہ کھیل کھیلنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔تھوڑی سی کرکٹ بھی کھیلے تھے لیکن ہماری کرکٹ کے قواعد ہمارے اپنے تھے۔کپڑے کی کترنوں کو مِلا جُلا کر گیند تیار کی جاتی۔اسے پنجابی میں’’کھِدّ ُو‘‘کہتے ہیں۔تختی سے بیٹ کا کام لیتے۔وکٹوں کی جگہ اینٹیں سجائی جاتیں تاکہ وکٹ گرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ بیٹس مین شاٹ کھیلنے کے بعد جتنی چاہے رنز بنا سکتا تھا۔’’کھِدّ ُو‘‘کبھی قریبی جھاڑیوں میں گُم ہو جاتا تو بیٹس مین کے وارے نیارے ہو جاتے۔ایسے ہی ایک موقعہ پر میں نے مسلسل پندرہ رنز بنائے تھے۔پھر تھک گیا تھا اس لئے مزید رنز نہیں بنائے۔وگرنہ ایک شاٹ پر سنچری ہو سکتی تھی کیونکہ گیند جھاڑیوں سے ملی ہی نہیں تھی۔
رحیم یارخان میں ہمارے قیام کے زمانے میںایک بار میرے ننھال سے بے جی‘خالہ حبیبہ‘ماموں سمیع‘ماموں صادق ‘ماموںکوثر‘ ماموںناصر ۔۔ ۔ بہت سارے عزیز آئے ہوئے تھے۔تب اباجی اور چاروں ماموؤں نے ایک تفریحی گراؤنڈ میں دوڑکا مقابلہ کیا۔یہ مقابلہ ابا جی نے جیت لیا تھا۔جن دنوں میں بے جی(نانی جان)کے ساتھ سارے مذکورہ عزیز آئے ہوئے تھے‘انہیں دنوں ایک نیم دیوانے قسم کے میاں کالے خاں بھی آوارد ہوئے۔یہ ہمارے ننھال کے جاننے والے تھے۔امی جی کودعا یا آشیر واد دینے کے لئے آئے۔ایک بگل سا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔اپنا نام اس بگل پر’’کالے خاں ۔۔۔ امام مہدی‘‘لکھوا رکھا تھا۔لیکن بیعت کسی کی نہیں لی۔ان کے بارے میں پتہ چلا کہ پیِروں کے مزاروں پر چڑھائی جانے والی چادریںاتار کر لے جاتے۔کوئی روکتا تو برہم ہو کر کہتے زندوں کو کپڑا ملتا نہیں اور تم مزاروں پر چڑھاتے پھرتے ہو۔مزاروں والے انہیں بھی کوئی پہنچا ہوا سمجھ کر چُپ کر جاتے۔ہمارے ہاں ایک دن رہے۔صبح اُٹھتے ہی کہنے لگے مجھے خدا نے کہا ہے:قالوبلیٰ قد جاء نا۔پھر اس کا پنجابی میں ترجمہ بھی کردیا ۔کالے خاں توں کدوں جانا ایں؟(کالے خاں!تم نے کب یہاں سے جانا ہے؟)اور پھر سب کو دعا دیتے ہوئے فقیرانہ شان کے ساتھ رخصت ہو گئے۔جاتے ہوئے بگل بھی بجاتے جاتے تھے۔قرآنی الفاظ کے پنجابی استعمال کی ایک دلچسپ بات سید عطا ء اﷲ شاہ بخاری کے لڑکپن سے متعلق ہے۔کہیں پڑھا تھا کہ وہ لڑکپن میں امرتسر کے کسی معروف حکیم صاحب کے شاگرد بنے تھے۔حکیم صاحب کے مطب کے سامنے ہی ان کا گھر تھا۔گھر والے حکیم صاحب کے لئے(غالباََ حقہ کے لئے)دہکتے کوئلوں کا تسلا تیار کردیتے تھے اور کوئی شاگرد آکر وہ تسلا لے جاتاتھا۔ سید عطا ء اﷲ شاہ بخاری کو جب پہلی بار تسلا لانے کے لئے بھیجا گیا تو انہوں نے کسی کپڑے کے بغیر انگلیوں سے تسلے کے کنارے پکڑے ۔ظاہر ہے کہ لوہے کا تسلا خاصا گرم تھا۔ شاہ صاحب جلدی سے سڑک پار کرکے مطب کے تھڑے پر ہی تسلا رکھ کر کہنے لگے:’’استاد جی! تصلیٰ نار حامیہ۔‘‘۔۔ ایسے ہی حکیم نورالدین صاحب کا یہ قصہ بھی مشہور ہے ۔کسی نے ان سے قولو قولاََ سدیدا کا مطلب پوچھا تو انہوں نے رواں پنجابی میں اسے یوںواضح کردیا۔قولو۔۔۔کہہ دے‘ قولاََ۔۔۔گَل (بات)‘سدیدا۔۔۔سیدھی سیدھی۔۔۔
کالے خاں کی بات سے بات کہاں جاپہنچی۔بات ہو رہی تھی ابا جی اور ماموؤں کی ریس کی۔ایک اور موقعہ پر ابا جی‘ماموں کوثر‘ماموں صادق ‘ماموں سمیع اور محلے کے بہت سارے احباب شامل ہوئے ۔فٹ بال میچ کھیلا گیا۔بچوں کو بھی ٹیموں میں شامل کیا گیا۔میں ابا جی کی ٹیم میں تھا۔مجھے ابھی کھیلنا تو آتا نہیں تھا‘پھر بڑوں کے سامنے ویسے بھی کیا کھیل پاتا۔اس کے باوجود ابا جی باآواز بلند ’’شاباش۔ ۔ حیدر شاباش۔۔۔‘‘کہہ کر میری ہمت بندھاتے رہے۔کک وہ خود مارتے اور مجھے شاباش دیتے جاتے۔اسی دوران مجھے پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی۔میں گراؤنڈ سے باہر کسی مناسب جگہ پرکھڑا ہوکر پیشاب کررہا تھا۔تب بھی ابا جی کی آواز آئی:’’شاباش۔۔حیدر شاباش‘‘یہ ایسی سچویشن تھی کہ دونوں ٹیمیں دیر تک ہنستی رہیں۔
آپی مجھ سے ایک سال بڑی تھی۔میرے بعد پھر ایک بہن (زبیدہ)پیدا ہوئی۔یوں میں ابتدائی بچپن میں دو بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔(ویسے ہم پانچ بھائی اور پانچ بہنیں‘کُل دس بہن بھائی تھے۔ ایک بہن شمسہ فوت ہوگئی تھی)محلے میں بچیوں کی تعدادزیادہ تھی۔چنانچہ میرے بچپن کی ابتدائی گیمز لڑکوں والی کم اور لڑکیوں والی زیادہ تھیں۔رحیم یارخاں کے ماحول میں تب یہ گیمز مقبول تھیں۔’’کوکلا چھپا کے جمعرات آئی اے‘‘۔’’مائی نی مائی تنور تپیا کے نائیں؟‘‘۔’’ککلی کلیر دی‘‘اور’’لکن میٹی‘‘۔ذرا بڑے ہوئے تو بچیوں کی گیمز کی جگہ بچوں کی گیمز کا پتہ چلا۔’’پٹھو گرم‘‘۔’’چکّر بتی‘‘۔’’مِیرو ڈبہ‘‘اور’’گلّی ڈنڈا‘‘ ۔۔ ’’چکر بتی‘‘اور ’’میرو ڈبہ‘‘ملتی جلتی گیمز تھیں۔آجکل مغرب میں جو ’’بیس بال‘‘ گیم مقبول ہے‘اسے’’چکر بتی ‘‘اور’’میرو ڈبہ‘‘کی بدلی ہوئی صورت سمجھیں۔’’پٹھو گرم‘‘میں نے بہت کھیلا لیکن سب سے زیادہ مزہ ’’گلی ڈنڈا‘‘کے کھیل میں آیا۔ایک بار ہم سارے عزیزوں نے یہاں جرمنی کے ایک پارک میں’’کوکلا‘‘کھیلا تو بہت مزہ آیا۔بعد میں ’’گلی ڈنڈا‘‘کھیلنے کا طے کیا تھالیکن ابھی تک پروگرام نہیں بن سکا۔
جب ہم لوگ خانپور شفٹ ہوئے تب بابا جی نے مجھے پہلوانی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی ۔پہلوان تو میں کیا بنتا البتہ کبڈی کے دو تین داؤ بابا جی سے ضرور سیکھ لئے۔لیکن مجھے یہ کھیل اچھا نہیں لگا۔سچی بات یہ ہے کہ میں جسمانی لڑائی لڑنے کا اہل ہی نہیں ہوں ذہنی لڑائی اور ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ذہنی لڑائی لڑنے میں مجھے ہمیشہ مزہ آیا ہے۔اسی لئے ادبی پنگوں میں الجھا رہتا ہوں۔
پنگوں کے لفظ سے’’پِینگ‘‘یاد آگئی۔درختوں پر ’’پینگ‘‘ (جھولا) ڈال کرپینگ چڑھانے کا بھی ایک وقت تک شوق رہا لیکن ایک گیم ایسی ہے جو بچپن سے لے کر جوانی تک ‘شادی کے بعد بھی دیر تک کھیلی ہے۔یہ گیم ’’اشٹاپُو‘‘ہے۔چھ خانے بنا کر‘ایک ٹھیکری کے ساتھ وہ خانے ایک ٹانگ کے بَل پر پُگانے ہوتے تھے۔دواور گیمز بھی یاد آگئیں۔۔’’ماماں جمال خاں‘‘ اور’’ہرا سمندر‘‘۔ ۔ ۔ یہ بھی بچپن کے مزیدار کھیل تھے۔اِن ڈور گیمز میں ’’کیرم‘‘بھی تھوڑا سا کھیلا ہوں لیکن ’’لوڈو‘‘۔’’بارہ ٹہنی‘‘ اور ’’نوٹہنی‘‘(جسے ہماری سرائیکی میں ’’نَوں تَرین‘‘کہتے ہیں)میری پسندیدہ گیمز ر ہی ہیں۔اب بھی کبھی کبھار کھیل لیتا ہوں۔ ’’کانچ کی گولیاں‘‘۔’’اخروٹ‘‘اور’’تاش کے پتے ‘‘ ان تین گیمز سے بچپن میں ہی اتنا ڈرا دیا گیاتھا کہ یہ بہت بُری گیمز لگتی تھیں۔’’بہت ہی بُرے بچے ایسی گیمز کھیلتے ہیں‘‘۔۔ ۔ کانچ کی گو لیاں اور اخروٹ تو کبھی نہیں کھیلا البتہ ایک بار چھوٹے بھائی اکبر نے تاش کے پتے کھیلنے کے گُر سکھا دئیے۔دوتین برس یہ گیم خوب کھیلی لیکن پھر مجھے محسوس ہوا کہ یہ بہت ہی واہیات گیم ہے۔اس میں ہارنے والا‘جیتنے کی اُمید لئے کھیلنے پر تُلا رہتا ہے اور جیتنے والا جیت کے نشے میں مزید کھیلتا چلا جاتا ہے۔یوں ساری ساری رات اس کھیل میں گزر جاتی ہے۔مجھے لگا کہ یہ گیم وقت کا ضیاع ہے۔چنانچہ پھر طبیعت خود ہی اس سے اُچاٹ ہو گئی اور اب میرے سامنے اس کھیل کی رونق بھی لگی ہوئی ہو تب بھی کھیلنے کو جی نہیں کرتا۔
ایک بار میں رحیم یارخان گیا ۔اپنے پرانے محلے میں گیا تو گلی وہی تھی لیکن گلی کے بیشتر مکان پختہ‘قد آور اور خوبصورت بن چکے تھے جو مکینوں کی خوشحالی کو ظاہر کر رہے تھے۔بُوا زیبُو کا گھر البتہ ویسے کا ویسا ہی کچا کوٹھا اور جھونپڑی نما تھا۔مجھے اس گھرکوجوں کا توں دیکھ کر اس گھر سے جُڑی ہوئی ساری یادیں مسکراتی‘گاتی اور اچھلتی‘کودتی دکھائی دینے لگیں ۔ہر منظر‘ہر یاد‘اس گھر کی چیزوں سے دِکھنے لگی تو میں اپنی خوشی کو نہ چھپا سکا اور بے اختیارانہ میں نے کہہ دیا کہ اس گھر کو جوں کا توں دیکھ کر مجھے بیحدخوشی ہوئی ہے۔تب بوا زیبو کی بڑی بہو نے دُکھی لہجے میں کہا:اگر اس گھر کو ایسے دیکھ کر آپ خوش ہوئے ہیں تو ہمیں بھی خوشی ہے ورنہ ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کب حالات بہتر ہوں اور گھر کو پکا کرالیں۔بُوا زیبو کی بہو کا وہ دُکھی لہجہ مجھے ابھی تک شرمندہ کرتا رہتا ہے۔(تحریر جولائی،اگست 2000 )
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
- Latest
- Trending