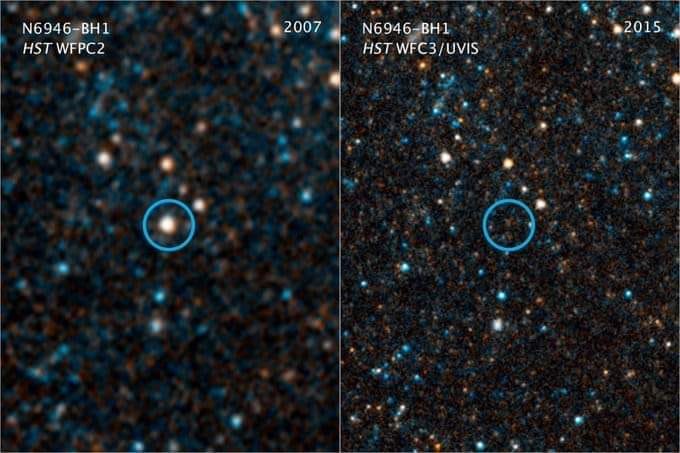عمران شاہد بھنڈر نے اپنے چار مضامین میں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کے جن سرقوں کو متوازی اقتباسات کے ساتھ پیش کیا ہے،ان کو یہاں یکجا کر کے پیش کر ہا ہوں۔ان اقتباسات کے بعد آخر میں عمران شاہد کی نئی کتاب’’گوپی چند نارنگ کا سرقہ تناظر اور مابعد جدیدیت‘‘ سے ایک طو یل سرقہ شدہ اقتباس بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ان تمام اقتباسات کے ساتھ یہاں عمران شاہد بھنڈر کے صرف وہ متعلقہ الفاظ شامل کر رہا ہوں جن کا اقتباسات کے تناظر میں پیش کیا جانا بے حد ضروری ہے۔ورنہ بنیادی مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ عمران شاہد بھنڈر کے تحریر کردہ چار مضامین میں سے پیش کیے گئے یہ اقتباسات اور ایک نیا اقتباس ،یہ سب ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کے سرقوں کی صرف ایک جھلک ہیں ۔عمران کی مذکورہ زیرِ اشاعت میں یہ سرقے اور مزید بے شمار سرقے سامنے آرہے ہیں۔اور ان کے بعد عمران شاہد بھنڈر کی اسی حوالے سے ایک اور دلچسپ کتاب بھی آنے ہی والی ہے۔ حیدر قریشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
گوپی چند نارنگ لکھتے ہیں ،
’’اس سوسیئری تناظر سے ظاہر ہے کہ ادب کا وہ نظریہ جسے حقیقت نگاری کہتے ہیں ،قابلِ مدافعت نہیں ہے۔ یہ دعوی ٰکہ ادبی فارم حقیقت کا عکس پیش کرتی ہے ،صرف تکرار بالمعنی، (Tautological) ہے۔اگر حقیقت سے ہماری مراد وہ حقیقت ہے جس کا ہم تجربہ کرتے ہیں ،یعنی جو تفریقی طور پر زبان کے ذریعے قائم ہوتی ہے تو یہ دعوی کہ ’حقیقت نگاری حقیقت کا عکس پیش کرتی ہے ، دراصل یہ ہوا کہ ،حقیقت نگاری اس دنیا کا عکس پیش کرتی ہے جو زبان کے ذریعے قائم ہوتی ہے‘(Constructed in Language) ظاہر ہے یہ’ تکرار بالمعنی‘ (Tautology) کے سوا کچھ نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔(ص،۷۸)
کیتھرین بیلسی لکھتی ہے،
From this post-Saussurean perspective it is clear that the theory of literature as expressive realism is no longer tenable. The claim that a literary form reflects the world is simply tautological. If by ‘the word’ we understand the world we experience, the world differentiated by language, then the claim that realism reflects the world means that realism reflects the world constructed in language. This is a tautology…………….
(Belsey, Catherine. Critical Practice, London, Routledge, 2003, P,43)
گوپی چند نارنگ نے جو اقتباس درج کیا ہے اس میں سے بیلسی کے لفظ پوسٹ کو حذف کیا ہے جس سے بیلسی کا قائم کردہ معنی بھی متاثر ہوا ہے۔تاہم اس کے صفحہ نمبر کا حوالہ کہیں نہیں ہے ۔ دوسرا انھوں نے مندرجہ بالا اقتباس میں ” تکرار بالمعنی” کو واوین میں لکھ کر یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ خاص اصطلاح کسی دوسرے نظریہ ساز سے ماخوذہے جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے ۔ سارے کا سارا اقتباس جسے یہاں مختصراََ پیش کیا گیا ہے بیلسی کی کتاب سے ماخوذہے ۔ مندرجہ بالا تجزیہ کیتھرین بیلسی کا ہے گوپی چند نارنگ کا نہیں ہے
گوپی چند نارنگ نے محض ایک ہی اقتباس کو نقل نہیں کیا بلکہ بیلسی کی اسی کتاب سے کئی اقتباسات لفظ بہ لفظ اپنے نام سے ترجمہ کیے ہیں ۔آئیے ایک اور اقتباس پر توجہ مرکوز کریں ،
’’ سیو سئر کی دلیل لفظوں کی ان کڑیوں پر مبنی ہے جو ایک تصور کے لیے مختلف زبانوں میں پائے جاتے ہیں ۔’اگرلفظ ما قبل موجود تصورات کے لیے قائم ‘ ہوتے تو ایک زبان سے دوسری زبان میں ان کے معنی متبادل پائے جاتے ،لیکن ایسا نہیں ہے ،(کورس ص،۱۱۶) حقیقت یہ ہے کہ مختلف زبانیں دنیا کی چیزوں کو مختلف طور پر دیکھتی اور ظاہر کرتی ہیں ۔سیوسئر نے کئی مثالیں دی ہیں ۔فرانسیسی میں ایک لفظ ہےMoutonاس کے برعکس انگریزی اس کے متبادل Muttonاور Sheepمیں فرق کرتی ہے‘‘ (گوپی چند نارنگ ،ص،۶۸)۔
اب بیلسی کی طرف رجوع کرتے ہیں،
Saussure’s argument depends on the different division of the chain of meaning in different languages. ‘ If words stood for pre-existing concepts’ they would all have exact equivalents in meaning from one language to the next; but this is not true’ (Saussure, 1974: 116). The truth is that different languages divide or articulate the world in different worlds. Saussure gives a number of examples. For instance, where French has the single mouton, English differentiates between mutton, which we eat, and sheep………….(Belsey, 36-37).
طوالت کے باعث اس اقتباس کو بھی مختصر رکھا گیا ہے ،تاہم انتہائی قابلِ توجہ امر یہ ہے کہ بیلسی نے اپنے تجزیے میں سیوسئر کی کتاب سے لیے گئے حوالے کو بشمول صفحہ نمبر پیش کیا ہے ،جبکہ گوپی چند نارنگ نے یہ تاثر قائم کیا ہے کہ سیوسئر کا حوالہ انھوں نے بیلسی کی کتاب سے اخذ نہیں کیا بلکہ انھوں نے سیوسئر کا براہِ راست مطالعہ کیا ہے ،یہ ادبی بدیانتی کی واضح مثال ہے۔
مذکورہ بالا حوالہ جات کے علاوہ روسی ہئیت پسندی پر لکھے گئے باب کا بیشتر حصہ جوناتھن کلر کی Strucuralist Poeticsسے نقل کیا گیا ہے ۔ اس کے علاوہ رومن جیکبسن پر لکھا گیا مکمل باب ٹیرنس ہاکس کی کتابStructuralism and Semioticsسے لفظ بہ لفظ گوپی چند نارنگ نے ترجمہ کیا ہے۔ آئیے اقتباس ملاحظہ فرمائیں،
’’روسی ہئیت پسندوں کے ضمن میں ہم مکارووسکی کے اس خیال سے بحث کر آئے ہیں کہ’ زبان کا تخلیقی استعمال فن پارے میں زبان کو ’پیشِ منظر‘ میں لے آتا ہے، یعنی اظہاری عمل اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہے، جیکبسن اس پر اضافہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شاعری کی تخلیقی زبان میں استعاراتی پہلو نمایاں رہتا ہے، نثر کی تخلیقی زبان میں انسلاکی پہلو زیادہ حاوی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرادفیت(equivalence) شاعری میں اس قدر اہمیت رکھتی ہے ۔ متوازیت بھی مرادفیت کا ایک رخ ہے۔۔۔۔۔۔۔‘‘(۱۴۰)
اب Terence Hawkesکے اس انگریزی اقتباس پر توجہ فرمائیں،
We have already noticed the argument of Jakobson’s fellow Prague school critic Mukarovsky with regard to foregrounding: that the aesthetic use of language pushes into the foreground the ‘act of expression’ itself. Jakobson offers the more refined proposal that the metaphoric mode tends to be foregrounding in poetry, whereas the metonymic mode tends to be foregrounded in prose. This makes the operation of ‘equivalence’ of crucial importance to poetry……..(Structuralism and semiotics, 1984, p80)
میرا یہ دعویٰ ہے کہ گوپی چند نارنگ نے ٹیرنس ہاکس کی کتاب Structuralism and Semioticsکو چند ایک پیراگراف کی ترتیب کو تبدیل کر کے ساری کی ساری کتاب ترجمہ کر کے اپنے نام سے شائع کرادی ہے۔
ٹیرنس ہاکس کی کتاب Structuralism and Semioticsمیں سے گوپی صاحب نے ساری کتاب لفظ بہ لفظ محض ان کی ترتیب بدل کر نقل کی ہے۔ مثلاََ اگر ٹیرنس ہاکس ایک پیراگراف پہلے لکھتا ہے تو اسی پیراگراف کو گوپی صاحب درمیان میں لکھ دیتے ہیں۔اگر الفاظ وہی ہیں تو محض پیراگراف کی ترتیب بدلنے سے کیا ہوگا۔ ویسے یہ ہوسکتا ہے کہ اس وقت ان کے ذہن میں جولیا کرسٹیوا کیintertexuality کی تھیوری گردش کررہی ہو۔ آئیے اس پیراگراف کا flavourدیکھتے ہیں۔ ٹیرنس ہاکس ، Todorovپر لکھے ہوئے باب میں کچھ یوں کہتا ہے،
The notion that literary works are ultimately about language, that their medium is their message, is one of the most fruitful of structuralist ideas and we have already noticed its theoretical foundations in the work of Jakobson. It validates the post-romantic sense that form and content are one, because it postulates that form is content. At one level, this permits, for instance, Todorov to argue that the ultimate subject of a work like The Thousand and One Night is the act of story-telling, of narration itself: that for the character involved- indeed for homo loquens at large- narration equals life: ‘the absence of narration death’……….. (Structuralism and Semiotics, p,100).
گوپی چند نارنگ صاحب یوں تحریر فرماتے ہیں،
’’یہ خیال کہ ادبی فن پارہ زبان سے قائم ہوتا ہے ، اور زبان ہی پیغام ہے: ‘THE MEDIUM IS THE MESSAGE‘بنیادی ساختیاتی نظریہ ہے، اور جیکب سن نے اس کی نظریاتی بنیادوں کو واضح کیا تھا۔ یہ خیال پَس رومانوی تصور کی بھی توثیق کرتا ہے کہ فارم اور مواد دراصل ایک ہیں، کیونکہ اس میں یہ تصور جاگزیں ہے کہ فارم ہی مواد ہے۔ اسی خیال کی بنا پر تودوروف نے ایک جگہ یہ نہایت دلچسپ بحث اٹھائی کہ الف لیلی جیسے شاہکار کا بنیادی ’موضوع‘ دراصل خود کہانی کہنے کا عمل‘ ہے کیونکہ کردار سب انسان (HOMO LOQUENS) یعنی’بولنے والے جاندار‘ ہیں اور ان کے لیے کہانی سنانا زندہ رہنے کی علامت ہے اور کہانی کے ختم ہوجانے کا مطلب ہے موت۔ ‘‘ ‘NARRATION EQUALS LIFE: THE ABSENCE OF NARRATION DEATH’ P’ 92 (ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، صفحات،۱۲۹۔۱۳۰)۔
مندرجہ بالا پیراگراف قارئین سے انتہائی توجہ کا تقاضہ کرتا ہے۔ گوپی صاحب نے اوپر والے اقتباس میں بعض فقرے واوین میں بھی لکھے ہیں اور اس کے بعد آخر میں ایک فقرہ انگریزی میں بھی لکھا ہے اوریہاں تک کہ صفحہ نمبر بھی درج کیا ہے جس میں اصل ذریعے کا حوالہ نہیں ہے۔اس سے وہ یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے Todorovکی کتاب کا مطالعہ کیا ہے۔ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لفظ بہ لفظ اس اقتباس کا مطالعہ ٹیرنس ہاکس کی کتاب کے صفحہ نمبر ۱۰۰پر کیا جاسکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نقاد گوپی چند نارنگ صاحب نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تاکہ قاری کہیں اپنی توجہ ٹیرنس ہاکس کی کتاب کی طرف مرکوز نہ کربیٹھے۔
اب ایک اور اقتباس پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ٹیرنس ہاکس کہتا ہے،
We have already noticed the arguments of Jakobson’s fellow Prague school critic Mukarovsky with regard to ‘foregrounding’: that the aesthetic use of language pushes into the foreground ‘the act of expression’ itself. Jakobson offered the most refined proposal that the metaphoric mode tends to be foregrounded in poetry, whereas the metonymic mode tends to be foregrounded in prose. This makes the operation ‘equivalence’ of crucial importance to poetry, not only in the area of analogy, but also in the area of ‘sound’ of those metrical, rythmic and phonic devices,…….continue. (Terence Hawkes, P, 80).
نارنگ صاحب کا یہ توجہ طلب اقتباس یوں ہے،
’’روسی ہیئت پسندوں کے ضمن میں ہم مکارووسکی کے اس خیال سے بحث کر آئے ہیں کہ’ زبان کا تخلیقی استعمال فن پارے میں زبان کو ’پیش منظر‘ میں لے آتا ہے، یعنی اظہاری عمل اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہے۔ جیکب سن اس پر اضافہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شاعری کی تخلیقی زبان میں استعاراتی پہلو نمایاں رہتا ہے، نثر کی تخلیقی زبان میں انسلاکی پہلو زیادہ حاوی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ’مرادفیت‘ EQUIVALENCEشاعری میں اس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ متوازیت بھی مرادفیت کا ایک رخ ہے۔ ردیف و قوافی، اصوات، اور اوزان وبحور تکرار و متوازیت کی جو اہمیت ہے، وہ اسی قبیل سے ہے‘‘جاری ہے (ص، ۱۴۰)۔
آئیے ٹیرنس ہاکس کے ایک اور اقتباس پر غور کرتے ہیں،
ُPoetic language is deliberately self-conscious, self-aware. It emphasises itself as a medium over and above the ‘message’ it contains: it characteristically draws attention to itself and systematically intensifies its own linguistic qualities. As a result, words in poetry have the status not simply of vehicles for thought, but of objects in their own right, autonomous concrete entities, In Sausure’s terms, then, they cease to be ‘signifiers’ and become ‘signifieds’, …(P, 63-64).
نارنگ صاحب لکھتے ہیں:
’’شعری زبان عمداََ اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے، یہ خود آگاہ اور خود شناس ہوتی ہے۔ یہ موضوع یا پیغام سے بلند تر ہوکر ، جو اس کے ذریعے بیان ہوا ہے،خود اپنی حیثیت کا احساس دلاتی ہے۔ شعری زبان کا بنیادی تفاعل توجہ کو اپنی جانب مبذول کرنا اور اپنے اوصاف کو نمایاں کرنا ہے۔ نتیجتاََ شعری زبان میں الفاظ فقط خیال یا جذبے کی ترسیل کا ذریعہ نہیں رہتے، بلکہ خود ٹھوس حقیقت بن جاتے ہیں جو قائم بالذات ہوتی ہے۔ ساسئیر کے معنی میں لفظ محض signifiersنہیں رہتے بلکہsignifiedبن جاتے ہیں۔۔۔‘‘جاری ہے (ص،۸۹)۔
ٹیرنس ہاکس کے اس اقتباس پر غور فرمائیں،
Formalist theory realised that the ‘meaning’ habitually carried by words can never be fully seperated from the words themselves because no word has ‘simple’ one meaning. The ‘meaning of A is not simply A 1or A 2or A3, for A has a larger capacity to mean which derives from its particular context or use. No word is ever really a mere proxy for a denoted object. Infact the transaction of ‘meaning’ has a coplexity of dimensions which the ‘poetic’ use of language further complicates. Poetry, in short, does not seperate a word from its meaning, so much as multiply – bewildering – the range of meanings available to it… (P, 64).
نارنگ صاحب کے اس اقتباس پر نظر ڈالتے ہیں:
’’ہیئت پسندوں کو اس کا احساس تھا کہ لفظ معنی سے اور معنی لفظ سے یکسر جدا نہیں کیے جاسکتے، اور معنی کا نظام اتنا سادہ نہیں جتنا بالعموم سمجھا جاتا ہے۔الف کا مطلب محض الف ۱، الف۲، یا الف ۳نہیں ہے کیونکہ الف کے معنی سیاق و سباق سے اور دوسرے لفظوں سے مل کر یکسر بدلتے رہتے ہیں۔ کوئی لفظ کسی شے کے محدود معنی میں ہمیشہ کے لیے قائم نہیں ہے۔ پس شعری زبان اگرچہ لفظ کو قائم بالذات کرتی ہے لیکن اس کو معنی سے جدا نہیں کرتی، بلکہ اس کے مختلف مفاہیمی امکانات کو ابھارتی ہے، یعنی معنیاتی قوسِ قزح کو پیدا کرتی ہے۔ معنی کی یہ بوقلمونی اکثر طلسمِ خیال یا حیرت و استعجاب کی کیفیت کی حامل ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔‘‘جاری ہے (ص،۸۹)۔
پروفیسررامن سیلڈن لکھتے ہیں،
There is another stand in poststructuralist thought which believes that the world is more than a galaxy of text, and that some theories of textuality ignore the fact that the discourse is involved in power. They reduce political and economic forces, and ideological and social control, to aspects of signifying processes. When a Hitler or a Stalin seems to dictate to an entire nation by wielding the power of discourse, it is absurd to treat the effect as simply occurring within discourse. It is evident that real power is exercised through discourse, and that this power has real effects……. The father of this line of thought is the German philosopher Nietzsche, who said that people first decide what they want and then fit the facts to their aim: ‘Ultimately man finds in things nothing but what he himself has imported into them.’ All knowledge is an expression of the ‘will to power’.This means that we can not speak of any absolute truths or of objective knowledge…. Foucault regards discourse as a central human activity, but not as a universal, ‘general text’, a vast sea of signification. He is interested in the historical dimention of discursive change. What it is possible to say will change from one era to another. In science a theory is not recognised in its own period if it deos not conform to the power consensus of the institutions and official organs of science. Mendel’s genetic theories fell on deaf ears in the 1860s; they were promulgated in a ‘void’ and had to wait until the twentieth century for acceptance. It is not enough to speak the truth; one must be ‘in the truth‘.
(Selden, Raman. Contemporary Literary Theory,3rd ed, Britain,1993,P158-159)
گوپی چند نارنگ کے سرقے کی جانب توجہ مبذول کرتے ہیں،
’’پس ساختیات میں ایک فکری دھارا اور بھی ہے جو اصرار کرتا ہے کہ ’متنیت‘(TEXTUALITY) ہی سب کچھ نہیں، بلکہ دنیا میں طاقت کے کھیل میں بجائے متن کے ’ڈسکورس‘ (مدلل مبرہن بیان) شامل ہے۔ مثل فوکو(MICHEL FOUCAULT) کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ’متنیت‘ کے نظریے سیاسی اور سماجی طاقتوں اور آئیڈیالوجی کو ’معنی خیزی‘ کے وسائل قرار دے کر ان کی حیثیت کو گھٹا دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی ہٹلر، موسولینی،یا اسٹالن ایک پوری قوم کو اپنے حکم پر چلاتا ہے، تو ایسا ’ڈسکورس‘ کی طاقت کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس طاقت کے اثرات کو ’متن‘ تک محدود رکھنا مہمل بات ہے۔ فوکو کہتا ہے کہ اصل طاقت کا استعمال ’ڈسکورس‘ کے ذریعے ہوتا ہے، اور اس طاقت کے ٹھوس اثرات مرتب ہوتے ہیں۔۔۔۔۔نٹشے نے کہا تھا کہ’لوگ پہلے طے کرتے ہیں کہ انھیں کیا چاہیے،اور پھر حقائق کو اپنے مقصد کے مطابق ڈھال لیتے ہیں‘۔نتیجتاََ انسان کو اشیاء میں وہی کچھ نظر آتا ہے جو ان میں خود اس نے داخل کیا ہے۔ فوکو اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمام علم طاقت کی خواہش ( WILL TO POWER) کا مظہر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مطلق صداقت یا معروضی علم کی بات نہیں کرسکتے۔ لوگ کسی فلسفے یا سائنسی نظریے کو صرف اسی وقت تسلیم کرتے ہیں ، جب وہ اپنے عہد کے سیاسی اور دانشورانہ متقدرات یا آئیڈیالوجی یا سچائی سے لگا کھائے یا وقت کے رائج پیمانوں پر پورا اُترے۔فوکو’ڈسکورس‘ کو ذہنِ انسانی کی مرکزی سرگرمی قرار دیتا ہے، ایک عام آفاقی ’متن‘ کے طور پر نہیں بلکہ ’معنی خیزی‘ کے ایک وسیع سمندر کے طور پر۔وہ تبدیلی کی تاریخی جہت میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ کہنا ممکن ہے وہ ایک عہد سے دوسرے عہد میں بدل جاتا ہے۔ سائنس میں بھی کوئی نظریہ اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جاتا، جب تک کہ وہ سائنس کے مقتدر اداروں اور ان کے سرکاری ترجمانوں کے طاقتی توافق سے مطابقت پیدا نہ کر لے۔فو کو کہتا ہے کہ مینڈل (MENDEL) کے علم توالّد کے نظریے کی ۱۸۶۰ء کے زمانے میں کوئی پذیرائی نہ ہوئی تھی گویا یہ خیالات خلاء میں پیش ہوئے تھے، اور ان کی اپنی قبولیت کے لئے بیسویں صدی کا انتظار کرنا پڑا۔ اس کا مشہور قول ہے کہ’صرف سچ بولنا کافی نہیں ہے سچائی کے’ اندر ‘ہونا بھی ضروری ہے‘(نارنگ،ص، ۱۹۴۔ ۱۹۶)۔
پروفیسر سیلڈن کے جوناتھن کلر پر لکھے گئے باب سے اقتباس پیش کرتے ہیں۔سیلڈن لکھتے ہیں،
Jonathan Culler (see also chapter 5) has argued that a theory of reading has to uncover the interpretative operations used by readers. We all know that different readers produce different interpretations. While this has led some theorists to despair of developing a theory of reading at all, Culler argues in The Pursuit of Signs (1981) that it is this variety of interpretation which theory has to explain. While readers may differ about meaning, they may well follow the same set of interpretative conventions…. (Selden, P62).
نارنگ صاحب کا کارنامہ ملاحظہ فرمائیں،
’’جونتھن کلر اس بات پر زور دیتا ہے کہ قراَت کے نظریے کے لئے ضروری ہے کہ وہ افہام و تفہیم اور تحسین قاری کو ضابطہ بند کر سکے جو بالعموم قارئین قراَت کے دوران استعمال کرتے ہیں۔اس بات کو نظر میں رکھنا چاہیے کہ ایک ہی متن سے مختلف قاری مختلف مفاہیم برآمد کرتے ہیں۔ اگرچہ تعبیر و تفہیم کا یہی تنوع دراصل قاری اساس تنقید کے بہت سے نظریہ سازوں کے لئے دقّت کا باعث بنتا ہے، لیکن کلر بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نظریے کا چیلنج یہی ہے کہ مختلف قرأتوں کے امکانات اور مفاہیم کے تنوع کو ضابطہ بند کیا جائے ، اس لئے قارئین میں معنی کا اختلاف تو ہوسکتا ہے لیکن تفہیم و تعبیر کے لئے قارئین جو پیرائے اور طور طریقے استعمال کرتے ہیں، ان میں کچھ تو ملتے جلتے ہونگے، اُن کو دریافت کرنے کی کوشش کی جاسکتی ہے‘‘(نارنگ،ص،۳۱۸۔۳۱۹)۔
سیلڈن کے جولیا کرسٹیوا پر لکھے گئے باب میں سے اس اقتباس کو ملاحظہ فرمائیں،
The word ‘revolution’ in Kristeva’s title is not simply metaphoric. The possibility of radical social change is, in her view, bound up with the disruption of authoritarian discourses. Poetic language introduces the subversive openness of the semiotic ‘across’ society’s ‘closed’ symbolic order: ‘What the theory of the unconscious seeks, poetic language practices, within and against the social order.’ Sometimes she considers that the modernist poetry actually prefigures a social revolution which in the distant future will come about when society has evolved a more conplex form. However, at other times she fears that bourgeois ideology will simply recuperate this poetic revolution by treating it as a safety valve for the repressed impulses it denies in society. Kristeva’s view of the revolutionary potential of women writers in society is just as ambivalent…. (Selden, P142).
نارنگ صاحب کو دیکھیں،
’’کرسٹیوا کا انقلاب کا تصور یہ ہے کہ سماجی ریڈیکل تبدیلی مقتدر ڈسکورس میں تخریب اور خلل اندازی کے عمل پر منحصر ہے۔ شعری زبان سماج کے ضابطہ بند اور مقید علامتی نظام میں نشانیاتی تخریب کاری کی آزادہ روی ( کھلی ڈھلی تنقید) کو راہ دیتی ہے۔لاشعور جو چاہتا ہے ، شعری زبان اس کو سماج کے اندر اور سماج کے خلاف برت سکنے پر قادر ہے۔کرسٹیوا کو یقین ہے کہ سماجی نظام جب زیادہ ضابطہ بند، زیادہ پیچیدہ ہوجائے گا تو نئی شعری زبان کے ذریعے انقلاب لایا جاسکے گا،لیکن اس کو یہ بھی خدشہ ہے کہ بورژوا آئیڈیالوجی ہر نئی چیز کو اپنا کر اس کا ڈنک نکال دیتی ہے ، چناچہ ممکن ہے کہ شعری انقلاب کو بھی بورژوا آئیڈیالوجی ایک سیفٹی والو کے طور پر استعمال کرے، ان دبے ہوئے ہیجانات کے اخراج کے لئے جن کی سماج میں بالعموم اجازت نہیں ہے‘‘(نارنگ،ص،۲۰۲)۔
جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ نارنگ صاحب کی ساری کتاب ترجمہ ہے ،لیکن انہوں نے چونکہ خود کو مترجم نہیں کہا اس لئے ہمیں ان کو سارق کہنا پڑ رہا ہے۔ سیلڈن کی تمام کتاب چند ایک اقتباسات چھوڑ کر نارنگ صاحب نے اپنے نام سے شائع کرائی ہے۔ نارنگ صاحب کے لئے بیٹھ کر سرقہ لکھنا اس لئے آسان ہوگیا کہ ایوارڈ ان کا منتظر تھا۔ کسی بھی دوسرے شخص کے لئے یہ کام آسان نہیں ہے کہ وہ قاری کو یقین دہانی کرانے کے لئے اپنے وقت کا زیاں کرتا رہے۔اس لئے یہاں پر سیلڈن کی کتاب سے اقتباسات کے مزید حوالے دینے کی بجائے ہم صرف صفحات کی تفصیل دینے پر ہی اکتفا کریں گے ۔ سنجیدہ قاری اصل مآخذات تک ضرور رسائی حاصل کریں گے۔
رامن سیلڈن کی کتاب کے صفحات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ گوپی چند نارنگ کی کتاب کے صفحات
2 7- 42۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 7 9-106
4 9- 70۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔28 8- 329
14 9- 158 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔23 4- 240
8 6- 103 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔24 3- 267
ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ سیلڈن کی کتاب سے دئیے گئے تمام صفحات گوپی چند نارنگ نے اپنے نام سے شائع کرائے ہیں۔حیرت زدہ کرنے والا امر یہ ہے کہ نارنگ صاحب نے اس کتاب میں شاید ہی چند الفاظ خود تحریر کئے ہوں۔ راقم کی حیرت میں اس لئے بھی اضافہ ہوا کہ نارنگ صاحب کو کتاب پر بطورِ مصنف اپنا نام لکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ کیا ان کو خود بھی یہ خبر نہ ہو سکی کہ آج نہیں تو کل یہ راز آشکار ہوجائے گا۔
سیلڈن کی کتاب سے نارنگ صاحب کے سرقے کے حقائق بمعہ تمام تر تفصیل پیش کرنے کے اب ایک دوسری کتاب کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ اس کتاب سے نارنگ صاحب نے رولاں بارتھ پر لکھے گئے مضمون کا سرقہ فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ اسی مضمون کے بعض حصے جوناتھن کلر کی Structuralist Poeticsسے چرائے گئے ہیں۔لیکن یہاں پر جو اقتباسات پیش کئے جارہے ہیں وہ John Sturrockکی کتاب سے لئے گئے ہیں ۔ سٹرک نے اس کتاب میں پانچ مابعد جدید مفکروں پر لکھے گئے مضامین کو مرتب کیا ہے ۔جس مضمون کا نارنگ صاحب نے سرقہ کیا ہے وہ سٹرک کا اپنا تحریر کردہ ہے۔سٹرک نے مصنفانہ سچائی کا لحاظ کیا اور تمام مضامین کو ان کے مصنفوں کے نام سے شائع کیا۔ نارنگ صاحب نے دوسری زبان کا بھر پور فائدہ اٹھاتے ہوئے بارتھ پر لکھے ہوئے مضمون کو اپنے نام کرلیا۔آئیے دونوں کا موازنہ پیش کرتے ہیں۔ جان سٹرک لکھتے ہیں،
ؑExistentialism, on the contrary, preaches the total freedom of the individual constantly to change….. Barthes, like Sartre, pits therefore the fluidity, the anarchy, even, of existence against the rigor mortis of essentialism; not least because, again following Sartre, he sees essentialism as the ideology which sustains that tradional bugbear of all French intellectuals, the bourgeoisie… he writes at the conclusion of his most feroriously anti-bourgeois book, the devastating Mythologies (1957………
In one way, Barthes goes beyond Sartre in his abhorrence of essentialism. Sartre, as so far as one can see, allows the human person a certain integrity or unity; but Barthes professes a philosophy of disintegration, whereby the presumed unity of any individual is dissolved into a plurality or discontinuous. This biography is especially offensive to him as a literary form because it represents a counterfeit integration of its individual. It is a false memorial to a living person…….
(Sturrock, John. Structuralism and Since. London, Oxford University Press,1979, P 53)
نارنگ صاحب کی طرف چلتے ہیں:
’’ لازمیت‘‘(ESSANTIALISM) کے مقابلے میں وجودیت نے انسان کی اس بنیادی آزادی پر زور دیا تھا جو ہر تبدیلی کی بنیاد ہے۔ بارتھ بھی سارتر کی طرح لازمیت اور جبریت کے خلاف ہر طرح کی بغاوت بلکہ نراجیت (انارکی) تک کا قائل تھا۔ سارتر کی طرح وہ بھی لازمیت کو بورژوازی کا نشان سمجھتا تھا، اور پوری قوت سے اس کو رد کرتا تھا جیسا کہ اس کی ایک ابتدائی بحث انگیز تصنیف MYTHOLOGIES (1957) سے ظاہر ہے۔
لازمیت اور بورژوازی کی مخالفت میں بارتھ ایک اعتبار سے سارتر سے بھی آگے نکل گیا، کیونکہ سارتر وحدت اور سا لمیت (INTEGRITY)کا منکر نہیں تھا،لیکن بارتھ اپنی دھن میں بورژوازی سا لمیت کے خلاف شکست و ریخت کے فلسفے کی حمایت تک سے گریز نہیں کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا انسان کی وحدت ایک طرح کا واہمہ ہے، اگر غور سے دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر ایک دراصل ’کئی‘ ہے۔ وہ وحدت کا سرے سے قائل ہی نہیں تھا، خدا کا بھی نہیں، ہر وہ چیز جو غیر مسلسل اور غیر واحد ہے، بارتھ اس کی حمایت کرتا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ سوانح اسی لئے ادب نہیں کہ وحدت پیدا کرنے کی کوشش میں جعل کا نمونہ پیش کرتی ہے اور غیر اصل ہے۔ ‘‘(نارنگ، ص،۱۶۲۔۱۶۱)۔
جان سٹرک کے اسی مضمون میں سے ایک اور اقتباس پر غور کرتے ہیں،
his arch enemy is the doxa, the prevailing view of things, which very often prevails to the extent that people are unaware it is only one of several possible alternative views. Barthes may not be able to destroy the doxa but he can lesson its authority by localizing it, by subjugating it to a paradox of his own……
Barthes is only fully to be appreciated, then, as some one who set out to disrupt as profoundly as he could the orthodox views of literature he found in France………..The grievances against contemporary criticism with which Barthes began were deeply influential on what he came to write later. There were four main ones. First, he objected that literary criticism was predominantly ahistorical, working as it did on the assumption that the moral and the formal values of the texts it studied were timeless…..Barthes was never a member of the Communist party – let us say neo-Marxist objection. He dismissed existing histories of French literature as meaningless choronicles of names and dates… (Sturrock, P, 54-55)
اسی صفحے پر نارنگ صاحب نے قاری کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لئے پیراگراف کی تفصیل کو بڑی مہارت سے تبدیل کیا ہے،اگر قاری بھی سمجھ بوجھ کا حامل ہو تو یہ سرقہ بھی اس کی نظر سے اوجھل نہیں رہ سکتا۔نارنگ صاحب کے اقتباس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
’’DOXAیعنی اشیاء و صورتحال کا تسلیم شدہ تصور جسے اکثریت قبول کرتی ہو، اُسے بارتھ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا۔ وہ DOXAکو تباہ کر سکا یا نہیں، لیکن اس نے اسکا احساس دلا دیا کہ حقیقت کا وہ تصور جسے بالعموم لوگ صحیح سمجھتے ہیں، حقیقت کے ممکنہ تصورات میں سے محض ایک ہوتا ہے۔ ۔۔۔چنانچہ ادب کے مقلدانہ تصور پر بھی رولاں بارتھ نے کاری ضرب لگائی۔ مدرسانہ تنقید اور مکتبی تنقید پر اس نے بار بار حملے کیے۔اُسے ادبی نظریات پر چار خاص اعتراض تھے:اوّل یہ کہ ادبی تنقید میں غالب رجحان غیر تاریخیت کا ہے، کیونکہ عام خیال ہے کہ متن کی ہئیتی اور اخلاقی اقدار دائمی ہیں۔بارتھ کبھی کمیونسٹ نہیں رہا لیکن ادب کی تاریخیت کے بارے میں اس کا نظریہ مارکسی نہ سہی تو نو مارکسی ضرور ہے۔ اس نے اپنے عہد کی ادبی تاریخوں کو ناموں اور سنین کا بے جان پُشتارہ قرار دیا‘‘(نارنگ، ص، ۱۶۳۔۱۶۲)۔
سٹرک نے بارتھ کے حوالے سے دوسرا اعتراض ان الفاظ میں اٹھایا ہے:
Barthes’s second complaints against academic criticism was that it was psychologically naive and deterministic….when critics chose to explain textual data by biographical ones, or the work by the life….The elements of a literary work – and this is an absolutely central point in literary structuralism – must be understood in the first instance in their relationship to other elements of that work….. (Sturrock, P,56)
نارنگ صاحب نے سٹرک کے بارتھ کے حوالے سے دوسرے اعتراض پر ان الفاظ میں قبضہ جمانے کی کوشش کی ہے:
’’ مکتبی یک سطحی تنقید پر اس کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ مکتبی تنقید کا نفسیات کا شعور مجرمانہ حد تک معصومانہ ہے۔ سوانح معلومات کی مدد سے متن کو سمجھنا اس کے نزدیک ناقابلِ معافی جرم تھا۔۔۔اس کے نزدیک ادبی متن کے عناصر کو صرف ان داخلی رشتوں کی مدد سے سمجھا جاسکتا ہے جو وہ متن کے دوسرے عناصر سے رکھتے ہیں۔ یہ نکتہ ساختیاتی فکر کا بنیادی پتھر ہے‘‘ (نارنگ، ص، ۱۶۳)۔
سٹرک کے بارتھ کے حوالے سے مکتبی تنقید پر تیسرا اعتراض سٹرک کے الفاظ میں کچھ یوں ہے:
They could see only one meaning in the texts they concerned themselves with, and that one meaning was usually a very literal one. This they subsequently held the meaning of the text, and that to search further for supplementary or alternative meanings was futile. They were men of narrow and autocratic temper who fancied they were being scientific when they were merely being culpably dogmatic. Their minds were closed to the ambiguities of language, to the co-existence of various meaning within a single form of words,……. (Sturrock, P 57-58)
نارنگ نے سٹرک کے بیان کردہ بارتھ کے تیسرے اعتراض کو ان الفاظ میں اپنے سرقے کی بھینٹ چڑھایا ہے:
’’مکتبی تنقید متن کے صرف متعینہ طے شدہ معنی کو صحیح سمجھتی ہے اور نہایت ڈھٹائی سے اس پر اصرار کرتی ہے۔ متعینہ معنی تو صرف لغوی معنی ہوسکتے ہیں ، اور ادب میں اکثر و بیشتر بے ہودگی کی حد تک غلط ہوتے ہیں۔ مکتبی نقادوں کے بارے میں بارتھ نے لکھا ہے کہ اُن کا ذہن چھوٹا اور نظر محدود ہوتی ہے،وہ ادعایت کا شکار ہیں اور ادب میں اکثریت کے علمبردار ہیں۔ ۔۔ادب فی نفسہ ابہام سے لبریز ہے اور ایک ہی فارم میں کئی معنی ساتھ ساتھ عمل آراء ہوسکتے ہیں‘‘ (نارنگ، ص، ۱۶۳)۔
نارنگ صاحب نے مندرجہ بالا تمام مصنفین کا تمسخر اڑانے کے بعد رابرٹ سکولز پر بھی اپنی ’سچائی‘ کو مسلط کیا ہے۔آئیے پہلے سکولز کی طرف چلتے ہیں:
Attempting to distinguish between constant and variable elements in a collection of a hundered Russian fairytales, Propp arrives at the principle that though the personage of a tale are variable, their functions in the tales are constant and limited. Describing function as “an act of a character, defined from the point of view of its significance for the course of the action,” Propp developed inductively four laws which put the study of folk literature and of fiction itself on a new footing. I their baldness and universality, laws 3and 4have the shocking effect of certain scientific discoveries:
1. Functions of characters serve as stable, constant elements in a tale, independent of how and by whom they are fulfilled. They constitute the fundamental components of a tale.
2. The number of function known to the fairy-tale is limited.
3. The sequence of functions is always identical.
4. All fairy tales are of one type in regard to their structure.
(Morphology of the Folktale, pp. 21,22,23)
In comparing the functions of tale after tale, Propp discovered that his total numbers of functions never surpassed thirty-one, and that however many of the thirty-one functions a tale had (none has every one) those that it had always appeared in the same order…. After the initial situation, in which the members of a family are enemerated or the future hero is introduced, a tale begins, consisting of some selection of the following functions in the following order:
1. One of the members of a family absents himself from home.
2. An interdiction is addressed to the hero.
3. The interdiction is voilated.
4. The villain makes an attempt at reconnaissance.
5. The villain recieves information about his victim.
6. The villain attempts to deceive his victim in order to take possession of him or of his belongings.
7. The victim submits to deception and thereby unwittingly helps his enemy.
یہ فہرست اکتیس پر جاکر ختم ہوتی ہے۔ مکمل فہرست دینے سے مضمون کی طوالت میں اضافہ ہوجائے گا، جو قطعی غیر ضروری ہوگا۔اگر مکمل فہرست دی جائے تو صفحات کی تعداد تقریباََ نو تک چلی جاتی ہے۔اس لئے قاری ان صفحات پر ازخود غور کرئے، جبکہ نارنگ کے سرقے کی تفصیل میں قلمبند کررہا ہوں
Scholes, Robert, Structuralism in Literature, New York, Vail-Ballou Press,197 4P, 62-70.
نارنگ صاحب کی حرکت پر توجہ مرکوز کرتے ہیں:
’’پروپ نے ایک سو لوک کہانیوں کا انتخاب کیا اور اپنے تجزیے سے بتایا کہ کرداروں اور ان کے ’تفاعل‘( FUNCTIONS) کی بناء پر ان لوک کہانیوں کی داخلی ساخت کو بے نقاب کیا جاسکتا ہے، اور ان کی درجہ بندی کس خوبی سے کی جاسکتی ہے۔ اس نے ان کہانیوں کے مختلف اور مشترک عناصر کا تجزیہ کیااور اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کہانیوں میں اگرچہ کردار بدلتے رہتے ہیں ، لیکن کرداروں کا ’تفاعل‘ (FUNCTIONS) مقرر ہے، اور تمام کہانیوں میں ایک سا رہتا ہے۔ کردار کے تفاعل کو کردار کا وہ عمل قرار دیتے ہوئے جو کہانی کی معنویت کے دوسرے اجزا سے جڑا ہوا ہے ، پروپ نے استقراری طور پر چار قوانین مرتب کیے جنھوں نے آگے چل کر لوک ادب اور بیانیہ کے مطالعے کے نئی دنیا فراہم کردی ۔ آفاقی اطلاقیت اور صداقت کے اعتبار سے قانون تین اور چار کو اکثر مفکرین نے سائنسی دریافت کا درجہ دیا ہے:
۱۔ کرداروں کے تفاعل کہانی کے راسخ اور غیر مذبذب عناصر ہیں،قطع نظر اس سے کہ کون ان کو سر انجام دیتا ہے،یہ کہانی کے بنیادی اجزا ہیں۔
۲۔ ’تفاعل ‘ کی تعداد کہانیوں میں محدود ہے۔
۳۔ ’ ’تفاعل‘ کی ’ترجیع ‘(SEQUENCE) ہمیشہ ایک سی رہتی ہے۔
۴۔ باوجود تنوع کے تمام کہانیوں میں ساخت ایک جیسی ہے۔
کرداروں کے ’تفاعل‘ (FUNCTIONS) کے اعتبا ر سے ایک کے بعد ایک کہانی کا تجزیہ کرتے ہوئے پروپ اس نتیجہ پر پہنچا کہ کہانیوں میں کرداروں کے ’تفاعل‘(FUNCTIONS) کی کُل تعداد اکتیس۳۱سے کسی طرح نہیں بڑھتی،اور اگرچہ بعض کہانیوں میں عمل کی کچھ لڑیاں نہیں ملتیں، لیکن ہمیشہ اُن کی ترتیب وہی رہتی ہے۔۔۔۔۔ابتدائی منظر کے بعد جب گھرانے کے افراد سامنے آتے ہیں، اور ہیرو کی نشاندہی ہو جاتی ہے تو کہانی ان تفاعل (FUNCTIONS) میں سے سب یا بعض کی مدد سے اسی ترتیب سے بیان ہوتی ہے:
۱۔ خاندان کا کوئی فرد گھر سے غائب ہو جاتا ہے۔
۲۔ ہیرو کی ممانعت کی جاتی ہے۔
۳۔ممانعت کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔
۴۔ولن جاسوسی کی کوشش کرتا ہے۔
۵۔ولن کو اپنے ’شکار‘ (VICTIM) کے بارے میں اطلاع ملتی ہے۔
۶۔ولن اپنے ’شکار ‘ کو دھوکہ دیتا ہے تا کہ اس پر یا اس کے مال و اسباب پر قبضہ کر لے۔
۷۔ ’شکار‘ دامِ تزویر میں آجاتا ہے اور نادانستہ اپنے دشمن کی مدد کرتا ہے۔ (نارنگ، ص، ۱۰۹۔۱۱۰)۔
نارنگ صاحب بھی اس فہرست کو اکتیس تک لفظ بہ لفظ نقل کرنے کے علاوہ سکولز کے تجزیے کو لفظ بہ لفظ نقل کرتے ہوئے صفحہ نمبر۱۱۷تک لے جاتے ہیں، لیکن کہیں بھی حوالہ دینا ضروری نہیں سمجھتے۔
ان صفحات کے علاوہ نارنگ صاحب اسی کتاب کے مختلف حصوں سے بھی خاطر خواہ اقتباسات کا سرقہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ آئیے پہلے انگریزی میں رابرٹ سکولزکے اس اقتباس پر غور کریں :
The last half of the nineteenth century and the last half of the twentieth were charecterized by the fragmentation of knowledge into isolated disciplines so formidable in their specialization as to seem beyond all synthesis. Even philosophy, the queen of the human sciences, came down from her throne to play solitary word games. Both the language -philosophy of Wittgenstein and the existentialism of the Continental thinkers are philosophy of retreat……
Scholes, Structuralism in Literature, New York, Vail-Ballou Press,1974, p,1) )
گوپی چند نارنگ کے مندرجہ ذیل اقتباس کو دیکھئے:
’’ ا نیسویں صدی کے نصفِ آ خر اور بیسویں صدی نصفِ اوّل میں فکرِ انسانی تخصیص کے مختلف میدانوں میں بٹ بٹا کر اس حد تک پارہ پارہ ہوگئی تھی کہ اس میں کسی طرح کی کوئی شیرازہ بندی ممکن نظر نہیں آتی تھی ۔ اور تو اور خالص فلسفہ بھی جسے علومِ انسانیہ کا بادشاہ کہا جاتا ہے ،وہ بھی لفظوں کے الگ تھلگ پڑ جانے والے کھیل میں لگ چکا تھا۔وٹگنسٹائن کا فلسفہ لسان ہو یا یورپی مفکرین کی وجودیت ،اصلاَ یہ سب مراجعت کے فلسفے ہیں۔۔(ص، ۳۴ )۔
برطانوی سوشل مفکرکرسٹو فر نورس لکھتے ہیں:
Derrida’s professional training was as a student of philosophy (at the Ecol Normale Superieure in Paris, where he taught until recently), and his writings demand of the reader a considerable knowledge of the subject. Yet Derrida’s texts are like nothing else in modern philosophy, and indeed represent a challenge to the whole tradition and self-understanding of that discipline.
Norris, Christopher. Deconstruction.3rd ed, London, Routledge,2002, P18-19)
نارنگ صاحب لکھتے ہیں:
’’تربیت کے اعتبار سے بھی دریدا فلسفی ہے، اور اس وقت بھی وہ۔۔Ecol Normale Superieure, Parisمیں فلسفے کا استاد ہے۔ نیز اس کی تحریروں کو فلسفے کی بنیادی باتوں کو جانے بغیر سمجھنا بھی ناممکن ہے۔تاہم دریدا کی تحریروں کو فلسفے میں شمار کرنا بھی مشکل ہے، اس لئے کہ فلسفے میں دریدا کی تحریروں کے مماثل کوئی چیز نہیں ملتی، کیونکہ وہ پوری فلسفیانہ روایت کو اور ان بنیادوں کو جن پر فلسفہ بحیثیت ضابطہ علم قائم ہے ،چیلنج کرتا ہے‘‘ (نارنگ، ص ۲۱۷)۔ ۔۔۔۔کرسٹوفر نورس لکھتے ہیں:
Derrida refuses to grant philosophy the kind of privileged status it has always claimed as the sovereign dispenser of reason. Derrida confronts this pre-emptive claim on its own chosen grounds. He argues that philosophers have been able to impose their various systems of thought only by ignoring, suppressing, the disruptive effects of languages. His aim is always to draw out these effects by a critical reading which fastens on, and skilfully unpicks, the elements of metaphor and other figural devices at work in the texts of philosophy. Deconstruction in this, its most rigorous form acts as a constant reminder of the ways in which language deflects or complicates the philosophers project. Above all deconstruction works to undo the idea-according to Derrida, the ruling illusion of Western metaphysics- that reason can somehow dispense with language and achieve a knowledge ideally unaffected by such mere linguistic foibles. Norris, P18-19). )
گوپی چند نارنگ کی کتاب کے اس اقتباس پر غور کریں :
’’دریدا فلسفے کو بحیثیت ضابطہ علم یہ آمرانہ درجہ دینے کو تیار نہیں کہ فکرِ انسانی کے جملہ حقوق فلسفے کے نام محفوظ کردیے جائیں ۔اس کا دعویٰ ہے کہ فلاسفہ اپنے نظام ہائے فکر کو مسلط کرنے کے لیے زبان کے داخلی تضادات کو دباتے،پسِ پشت ڈالتے یا نظر انداز کرتے رہے ہیں۔ دریدا اپنے ردِ تشکیلی مطالعات میں فلسفے کی ان کمزوریوں اور معذوریوں کو نمایا ں کرتا ہے۔ وہ بار بار نہایت سختی سے یاد دلاتا ہے کہ زبان کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ فلسفی کے کام کو مشکل سے مشکل تر بناتی ہے۔ اگرچہ مغربی مابعد الطبیعات میں یہ خیال عام رہا ہے کہ فکر انسانی کسی نہ کسی طرح زبان سے چھٹکارہ پاسکتی ہے اور سچائی کو بیان کرنے کا کوئی خالص اور مستند طریقہ وضع کر سکتی ہے۔۔۔(ص،۲۱۸۔۲۱۷)
کرسٹوفر نورس سوشل فلاسفر ہونے کی حیثیت سے فلسفے کی اہمیت سے بخوبی آگاہ ہیں۔اس لئے وہ کوئی ایسا انتہا پسندی پر مبنی بیان جاری نہیں کرتے، جس سے فلسفے کی غیر ضروری تضحیک کی جائے۔مندرجہ بالا اقتباس میں جہاں پر انہوں نے ڈیکنسٹرکشن کے حوالے سے فلسفے کا ذکر کیا ہے ،وہاں پر انہوں نے واضح الفاظ میں ’’دریدا کے مطابق‘‘ لکھ دیا ہے۔نارنگ صاحب کی اگر اب تک کی تصانیف کا جائزہ لیا جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اپنے مضامین میں کسی بھی فلسفی کے افکار پر بحث نہیں اٹھائی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ فلسفے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، جو ان کے اس اقتباس سے واضح ہے’’لیکن دریدا ناقابلِ تردید طور پر ثابت کرتا ہے کہ فلسفے کی یہ توقع واہمے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اور فلسفے کا زبان کے شکنجے سے آزاد ہونا قطعاََ ناممکن ہے‘‘(ص۲۱۸)۔
کرسٹوفر نورس لکھتے ہیں ،
In this sense Derria’s writings seem more akin to literary criticism than philosophy. They rest on the assumption that modes of rhetorical analysis, hitherto applied mainly to literary texts, are infact indispensable for reading any kind of discourse, philosophy included. Literature is no longer seen as a kind of poor relation to philosophy, contenting itself with mere fictive or illusory appearances and forgoing any claim to philosophic dignity and truth. This attitude has, of course, a long prehistory in Western tradition. It was plato who expelled the poets from his ideal republic, who set up reason as a guard against the false beguilements of rhetoric, and who called forth a series of critical ‘defences’ and ‘apologise’ which runs right through from Sir Philip Sydney to I. A. Richards and the Americans new critics. The lines of defence have been variously drawn up, according to whether the critic sees himself as contesting philosophy on its own argumentative ground, or as operating outside its reach on a different – though equally privileged – ground. (Norris,P19)
نارنگ صاحب اس اقتباس سے متاثر ہوکر کیاکمال دکھا رہے ہیں:
’’اس نظر سے دیکھا جائے تو فلسفے سے زیادہ ادب کی ذیل میں آتی ہیں، اس کا بنیادی ایقان یہ ہے کہ لسانی یا بدیعی تجزیہ جو فقط ادبی متن کا منصب سمجھا جاتا ہے، وہ درحقیقت کسی بھی بیان(discourse)بشمول فلسفیانہ بیان کے سنجیدہ مطالعے کے لئے ضروری ہے۔دریدا کا موقف ہے کہ ادب فلسفے کا دور کا رشتہ دار نہیں، جس کو فلسفی محض لفظوں کے تخیلی توتے مینا بنانے والے ضابطے کے طور پر رد کرتے رہے ہیں، بلکہ سچائی کا حصہ دار ہونے کے ناطے ادب اسی عزت و افتخار کا مستحق ہے جو فلسفے کے لئے مخصوص ہے۔ اتنی بات معلوم ہے کہ افلاطون نے ادیبوں، شاعروں کو اپنی مثالی ریاست سے اسی لئے خارج کردیا تھا کہ عقل کے مقابلے میں ادب کی مجازیت قابلِ برداشت نہ تھی۔ سر فلپ سڈنی سے لے کر رچرڈز اور نئی تنقید تک ادب کی آزادانہ حیثیت کا دفاع کیا جاتا رہا ہے۔۔۔۔۔‘‘(نارنگ،ص،۲۱۸)۔
نارنگ صاحب نے یہاں پر نورس کے لفظ ’امریکی‘ کو حذف کردیا ہے ، کہیں اُردو والے امریکہ کے نام سے ناراض نہ ہوجائیں۔اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈسکورس کو انگریزی میں لکھ دیا ہے، جس سے یہ تاثر ابھرے کہ نارنگ صاحب خود یہ تجزیہ پیش کر رہے ہیں جہاں انہوں نے ضروری سمجھا انگریزی لفظ کا استعمال بھی کردیا۔
راقم کا یہ دعویٰ ہے کہ گوپی چند نارنگ کی کتاب میں دریدا اور ردِ تشکیل پرلکھا ہواتمام مواد کرسٹوفر نورس کی کتاب سے ہوبہو ترجمہ ہے۔آئیے ایک اور اقتباس پر غور کریں۔کرسٹوفر نورس لکھتے ہیں:
The counter-arguments to deconstruction have therefore been situated mostly on commonsense, or ‘ordinary-language’ ground. There is support from the philosopher Ludwig Wittgenstein (1889-1951) for the view that such sceptical philosophies of language rest on a false epitemology, one that seeks (and inevitably fails) to discover some logical correspondence between language and the world. Wittgenstein himself started out from such a position, but came round to believing that language had many uses and legitimating ‘grammars’, non of them reducible to a clear-cut logic of explanatory concepts. His later philosophy repudiates the notion that meaning must entail some one-to-one link or ‘picturing’ relationship between propositions and factual status of affairs. Languages now conceived of as a repertoire of ‘games’ or enabling conventions, as diverse in nature as the jobs they are require to do (Wittgenstein 1953). The nagging problems of philosophy most often resulted, Wittgenstein thought, from the failure to recognise multiplicity of language games. Philosophers looked for logical solutions to problems which were only created in the first place by a false conception of language, logic and truth. Scepticism he argued, was the upshot of a deluded quest for certainty in areas of meaning and interpretation that resist any such strictly regimented logical account. (Norris, P127-128).
نارنگ صاحب کی ’لسانیاتی چال‘ دیکھیں:
’’دریدا کی ردِ تشکیل کے خلاف جتنی بھی بحث کی گئی ہے وہ عام زبان (ORDINARY-ANGUAGE) کے نکتہء نظر سے کی گئی ہے۔خاطر نشان رہے کہ ایسے لوگوں سے پہلے لدو گ وٹگنسٹائن۔۔(LUDWIG WITTGENTEIN 188 9- 1951)کہہ چکا ہے کہ زبان سے متعلق متشککانہ نظریے اس جھوٹی علمیات (EPISTEMOLOGY) کا حصہ ہیں جو زبان اور اشیاء میں کسی نہ کسی طرح کا منطقی ربط پیدا کرنا چاہتی ہے۔وٹگنسٹائن نے خود اپنا فلسفیانہ سفر اسی تشکیک سے شروع کیا، لیکن بعد میں وہ اسی نتیجے پر پہنچا کے زبان کے کئی طرح کے استعمال ہیں، جن سے کئی طرح کی گرائمریں پیدا ہوتی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی گرائمر منطق کے صاف شفاف اصولوں کی سطح پر نہیں لائی جاسکتی۔وٹگنسٹائن کا فلسفہ اس بات کی تردید ہے کہ زبان میں لفظ اور شئے میں ایک اور ایک کا رابطہ ہے۔وہ زبان کا تصور ایک ایسے نظام کے طور پر کرتا ہے جس میں طرح طرح کے مقاصد کے لئے طرح طرح کے کھیل کھیلے جاتے ہیں وٹگنسٹائن کا کہنا ہے کہ فلسفے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ زبان کی کثیرالمعنیت کو زیرِ دام نہیں لاسکتا۔ فلاسفہ کو مسائل کے منطقی حل کی ضرورت ہوتی ہے،اور تشکیک تیقن کی کھوج کا نتیجہ ہے کیونکہ معنی کی منطقی تحلیل ممکن نہیں۔ غرض بقول وٹگنسٹائن وہ تمام متشککانہ فلسفے جو زبان ، منطق اور حقیقت کے درمیان مختلف النوع مطابقتوں کو نہیں دیکھ سکتے ،حیرت کا شکار ہونے پر مجبور ہیں۔‘‘(نارنگ،ص، ۲۱۹)۔
اس سے قبل بھی یہ عرض کیا جاچکا ہے کہ نارنگ نے رامن سیلڈن کی کتاب Contemporary Literary Theory میں سے بہت زیادہ سرقہ یا ترجمہ(تسلیم کرنے کی صورت میں) کیا ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق نارنگ نے سیلڈن کی کتاب کا پہلا اور آخری باب چھوڑ کر تقریباََ تمام کتاب کا ترجمہ کردیا ہے۔ایگلٹن، جیمسن، یاؤس اور رفارٹیئر وغیرہ پر لکھا گیا ایک ایک لفظ سیلڈن کی کتاب میں سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ ان ابواب پر نظر ڈالتے ہیں جو اس سے قبل کہیں بھی پیش نہیں کیے گئے۔ اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ شخص سارق ہے یا مترجم؟ سیلڈن لکھتے ہیں۔
Eagleton, like Althusser, argues that criticism must break with its ‘ideological prehistory’ and become a ‘science’. The central problem is to define the relationship between literature and ideology, because in his view texts do not reflect historical reality but rather work upon ideology to produce an effect of the ‘real’. The text may appear to be free in its relation to reality (it can invent characters and situations at will), but it is not free in its use of ideology. ‘Ideology’ here refers not to formulated doctrines but to all those systems of representations (aesthetic, religious, judicial and others) which shapes the individuals mental pictures of lived experience. The meanings and perceptions produced in the text are a reworking of ideologie’s on working of reality. This means that the text works on reality at two removes. Eagleton goes on to deepen the theory by examining the complex layering of ideology from its most general pre-textual forms to the ideology of the text itself. He rejects Althusser’s view that literature can distance itself from ideology; it is a complex reworking of already existing ideological discourses. However, the literary result is not merely a reflection of other ideological discourses but a special production of ideology. For this reason criticism is concerned not with just the laws of literary form or the theory of ideology but rather with ‘the laws of the production of ideological discourses as literature‘.
Eagleton surveys a sequence of novels from George Eliot to D.H Lawrence in order to demonstrate the interrelations between ideology and literary form…. Eagleton examines each writer’s ideological situations and analyses the contradictions which develope in their thinking and the attempted resolutions of the contradictions in their writing. After the destruction of liberal humanism in the first world war Lawrence developed a dualistic pattern of ‘female’ and ‘male’ principles. This antithesis is developed and reshuffled in the various stages of his work, and finally resolves in the characterisation of mellors (Lady Chatterley’s Lover) who combines impersonal ‘male’ power and ‘female’ tenderness. This contradictory combination, which takes various forms in the novels, can be related to a ‘deep-seated ideological crises’ within contemporary society.
The impact of poststructuralist thought produced a radical change in Eagleton’s work in the late 1970s. His attention shifted from the ‘scientific’ attitude of Althusser towards the revolutionary thought of Brecht and Benjamine. This shift had the effect of throwing Eagleton back towards the classic Marxist revolutionary theory of the Thesis on Feuerbach (1845): ‘The question whether objective truth can be attributed to human thinking is not a question of theory but is a practical question…The philosophers have only interpreted the world in various ways; the point is to change it’. Eagleton believes that ‘deconstructive’ theories, as developed by Derrida, Paul de Man and others can be used to undermine all certainties, all fixed and absolute forms of knowledge…………..
Raman Seldon, Contemporary Literary Theory, 3rd ed, Britain, 1993,P, 92-93.
واضح رہے کہ سیلڈن کا ایگلٹن پر یہ مضمون ختم نہیں ہوا(ہم دیکھیں گے کہ نارنگ کا سرقہ بھی ختم نہیں ہوتا)، بلکہ سیلڈن کی کتاب میں صفحہ نمبر ۹۵تک جاتا ہے۔ اس کے بعد سیلڈن نے جیمسن پر بحث کا آغاز کردیا ہے۔یہاں یہ نکتہ بھی ذہن نشیں رہے کہ ایگلٹن کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے یہ سیلڈن کا لکھا ہوا ہے۔ سیلڈن نے ایگلٹن کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور قاری کے لیے چند صفحات پر ہی ’’افہام و ترسیل‘‘ کو کو ممکن بنادیا۔ایسا لگتا ہے کہ نارنگ افہام و ترسیل کا مطلب بھی نہیں جانتے۔ نارنگ کے انتہائی علمی و فکری سطح پر معذور حواری بھی نارنگ کا یہی اقتباس پیش کرتے ہیں۔حقیقت یہ ہے کہ علمی بددیانتی کے تسلسل نے علمی و ادبی روح تک ان کے باطن میں پیدا نہیں ہونے دی۔ ایگلٹن کے حوالے سے نارنگ کے برعکس ، یہ تجزیہ اور’’افہام و ترسیل‘‘ پروفیسر سیلڈن کی ہے۔ نارنگ کے لفظ بہ لفظ ترجمے کو قاری کے سامنے لانا ضروری ہے۔نارنگ کا ’’بے دھڑک‘‘ ہونا ملاحظہ کریں
’’التھیوسے سے اتفاق کرتے ہوئے ایگلٹن کہتا ہے کہ’تنقید کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئیڈیولاجیکل ماضی سے اپنا رشتہ منقطع کرے اور سائنس بن جائے۔‘ اصل مسئلہ ادب اور آئیڈیالوجی کے رشتے کا تعین ہے، کیونکہ ادب تاریخی حقیقت کا عکس پیش نہیں کرتا، بلکہ آئیڈیالوجی کے ساتھ عمل آرا ہوکر حقیقت کا اثر پیدا کرتا ہے۔ متن حقیقت سے اپنے رشتے میں آزاد ہے، وہ کرداروں اور صورتحال کو آزادانہ خلق کرسکتا ہے، لیکن آئیڈیالوجی سے اپنے رشتے میں آزاد نہیں۔ آئیڈیالوجی سے صرف وہ سیاسی تصورات اور اصول و ضوابط مراد نہیں جن کا ہم شعور رکھتے ہیں ، بلکہ بشمول جمالیات، الہیات، عدلیات، وہ تمام نظامات جن کی روح سے فرد ’جھیلے ہوئے تجربے‘ کا ذہنی تصور قائم کرتا ہے۔ متن کے ذریعے رونما ہونے والے معنی اور تصورات دراصل اس تصورِ حقیقت کا بازِ تصور ہوتے ہیں جنھیں آئیڈیالوجی نے قائم کیا ہے۔ اس طرح گویا متن میں حقیقت کا تصور دو طرح سے در آتا ہے۔ ایگلٹن متن سے پہلے کی اور بعدکی آئیڈیالوجی کی شکلوں اور ان کے پیچیدہ رشتوں کا تجزیہ کرکے اپنے نظریے میں مزید وسعت پیدا کرتا ہے۔ اس کا خیال ہے التھیوسے کا یہ کہنا مناسب نہیں کہ ادب آئیڈیالوجی سے فاصلہ پر ہوتا ہے۔بقول ایگلٹن ادب تو آئیڈیالوجی کے مباحث کی بازیافت ہوتا ہے۔بہرحال نتیجتاَ ادب آئیڈیالوجی کے مباح کے عکس کے طور پر نہیں، بلکہ آئیڈیالوجی کی ایک خاص ’پیداوار‘ کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔بس تنقید کا کام صرف ہیئت کے اصول و ضوابط کا یا آئیڈیالوجی کا نظریاتی تعین نہیں، بلکہ ان قوانین کا طے کرنا بھی ہے، جن کی رو سے آئیڈیولاجیکل مباحث ادب کی ’پیداوار‘ میں ڈھلتے ہیں۔
ایگلٹن جارج ایلیٹ سے ڈی ایچ لارنس تک متعدد ناولوں کا مطالعہ کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ آئیڈیالوجی ادبی ہیئت میں کیا رشتہ ہے۔ ایگلٹن ہر مصنف کے آئیڈیولاجیکل موقف کا جائزہ لیتا ہے اور تجزیہ کرکے ان کے افکار کے تضادات کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ کہ بلآخر ان تضادات کو حل کرنے کی کیا کوشش کی گئی۔پہلی جنگ عظیم کے بعد لارنس کے یہاں ’مردانہ‘ اصول اور ’نسوانی‘ اصول کی ثنویت ملتی ہے، بہرحال اس کا ’ردمقدمہ بھی رونما ہوتا ہے‘ اور کئی منزلوں سے گزرتے ہوئے بلآخر ’لیڈی چیٹر لیز لور‘ میں میلرز کے کردار میں حل کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یعنی میلرز کا کردار غیر شخصی سطح پر ’مردانہ‘ قوت اور ’نسوانی‘ نرمی دونوں کا بیک وقت حامل ہے۔بقول ایگلٹن اس طرح کے متضاد ارتباط اس اندرونی آئیڈیولاجیکل کرائسس کو ظاہر کرتے ہیں جس کا سماج شکار ہے۔
۱۹۷۰کے بعد پسِ ساختیاتی فکر کے باعث ایگلٹن کے کام میں بنیادی تبدیلی یہ رونما ہوئی کہ اب اس کی توجہ التھیوسے کے سائنسی رویے سے ہٹ کر بریخت اور بینجمن کی انقلابی فکر پر مرکوز ہوگئی۔ نتیجتاََ ایگلٹن مارکس کے کلاسیکی انقلابی نظریےThesis on Feuerbach (1845).
”THE QUESTION WHETHER OBJECTIVE TRUTH CAN BE ATTRIBUTED TO HUMAN THINKING IS NOT A QUESTION OF THEORY BUT AIS A PRACTICAL QUESTION…. THE PHILOSOPHERS HAVE ONLY INTERPRETED THE WORLD IN VARIOUS WAYS; THE POINT IS TO CHANGE IT”.
ایگلٹن کو اس سے اتفاق ہے کہ نظریہ رد تشکیل جس کو دریدا ، پال دی مان اور دوسروں نے قائم کیا ہے، اس کو پہلے سے طے شدہ معنی کو بے دخل کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے‘‘ (نارنگ، ۲۶۵۔۲۶۴)۔
واضح رہے کہ نارنگ کا سرقہ جاری ہے جو صرف ایگلٹن کی بحث میں ہی صفحہ نمبر ۲۶۷تک چلا جاتا ہے۔ ’’ساختیات پس ساختیات اور مشرقی شعریات ‘‘ کی کتاب دو کے پانچویں باب میں ’’مارکسیت، ساختیات اور پس ساختیات ‘‘ کے عنوان سے ایگلٹن وغیرہ پر لکھا گیا تمام مواد لفظ بہ لفظ اٹھالیا گیا ہے، وہاں پر صفحات کی کوئی تفصیل نہیں دی گئی۔ مصادر میں کتاب دو کے پانچویں باب کی تفصیل صفحہ ۳۳۲پر دی گئی ہیں، وہاں پر بھی صفحات کی تفصیل موجود نہیں ہے۔گوپی چند نارنگ نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ ’’جہاں ضروری تھا وہاں تلخیص اورترجمہ بھی کیاہے۔ بات کا زور بنائے رکھنے کے لئے اصل کے Quotationsبھی جگہ جگہ دیے ہیں۔‘‘ مذکورہ بالا اقتباس پر توجہ مرکوز کرنے سے واضح ہوجاتا ہے کہ نارنگ نے تمام و کمال اس کو سیلڈن کی کتاب سے ترجمہ کردیا ہے، مگر اس اقتباس میں ایک Quotationانگریزی میں دی گئی ہے، جس سے یہ تائثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ صرف یہی ایک اقتباس کسی دوسرے مصنف سے ماخوزذہے، نارنگ نے انٹرویو میں کہا ہے کہ جہاں ضرورت محسوس کی گئی وہاں ’’بات کا زور بنائے‘‘ رکھنے کے لیے Quotationپیش کیے گئے ہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس انداز میں Quotationکا استعمال بات کا ’زور بنائے رکھنے‘ کے لیے نہیں، بلکہ ذہنی طور پر اپاہج حواریوں میں ’اپنا زور بنائے‘ رکھنے کی کوشش ہے، جس میں ان کو خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔مذکورہ بالا اقتباس سے ایسا لگتا ہے کہ اردو میں لکھا گیا ہر لفظ نارنگ کا تجزیہ ہے، یہ کہنا ادبی مفہوم میں کسی گناہِ کبیرہ کا ارتکاب کرنے کے مترادف ہوگا۔
اس کے بعد پروفیسر سیلڈن نے جیمسن پر مختصر بحث کی ہے ، اس کو بھی نارنگ نے جوں کا توں اٹھالیا ہے۔جوں کا توں اٹھانے کا مطلب یہ ہوا کہ ایگلٹن ہی کی طرح نارنگ نے جیمسن کی بھی کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، سیلڈن جیمسن کے حوالے سے بھی مغربی طالب علم کو آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے جو تعارف پیش کرتے ہیں ، نارنگ اس کو لفظ بہ لفظ اٹھاکر سیلڈن کی افہام و ترسیل کو ایک بار پھر اپنی ’’ افہام و ترسیل‘‘ بنا کر پیش کرتے ہیں۔پہلے سیلڈن کی جانب چلتے ہیں:
In America, where the labour movement has been partially corrupted and totally excluded from political power, the appearance of a major Marxist theorist is an important event. Jameson believes that in the post-industrial world of monoply capitalism the only kind of Marxism which has any purchase on the situation which explores the ‘great themes of Hegel’s philosophy – the relationship of part to whole, the opposition between concrete and the abstract, the concept of totality, the dialectic of appearance and essence, the interaction between subject and object’. For dialectical thought there are no fixed and unchanging ‘objects’; an ‘object’ is inextricably bound up with a larger whole, and is also related to a thinking mind which is itself part of a historical situation. Dialectical criticism does not isolate individual literary works for analysis; an individual is always a part of a larger structure (a tradition or a movement) or part of a historical situation. The dialectical critic has no pre-set categories to apply to literature and will always be aware that his or her chosen categories (style, character, image, etc.) must be understood ultimately as an aspect of the critics on historical situation…….. A Marxist dialectical criticism will always recognise the historical origins of its own concepts and will never allow the concepts to ossify and become insensitive to the pressure of reality. We can never get outside our subjective existence in time, but we can try to break through the hardening shell of our ideas ‘into a more vived apprehension of reality itself‘.
His The Political Unconscious (1981) retains the earlier dialectical conceptio of theory but also assimilates various conflicting traditions of thought (structuralism, poststructuralism, Freud, Althusser, Adorno) in an impressive and still recognisably Marxist synthesis. Jameson argues that the fragmented and alienated condition of human society implies an original state of primitive communism in which both life and perception were collective………….. All ideologies are ‘strategies of containment’ which allow society to provide an explaination of itself which suppresses the underlying contradiction of history; it is history itself (the brute reality of economic Necessity) which imposes this strategy of repression. Literary texts work in the same way: the solutions which they offer are merely symptoms of the suppression of history. Jameson cleverly uses A.J Greimas’ structuralist theory (the ‘semiotic rectangle’) as an analytic tool for his own purposes. Textual strategies of containment present themselves as formal patterns. Greimas’ structuralist system provide a complete inventry of possible human relations… which when applied to a text’s strategies, will allow the analyst to discover the posibilities which are not said. This ‘not said’ is the represses history.
Jameson also developes a powerful argument about narrative and interpretation. He believes that narrative is not just a literary form or mode but an essential ‘epistemological category’; reality presents itself to the human mind only in the form of the story. Even a scientific theory is a form of story.
( Seldon, P, 95-97).
نارنگ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں،
’’امریکہ میں فریڈرک جیمیسن جیسے اہم مارکسی نظریہ ساز کا پیدا ہونا خاصا دلچسپ ہے۔۔۔۔ جیمسن کا خیال ہے کہ ’پس صنعتی‘ دنیا میں جہاں اجارہ دارانہ سرمایہ داری کا دور دورہ ہے، مارکسزم کی صرف وہی قسم کامیاب ہوسکتی ہے جو ہیگل کے فلسفے کی عظیم تھیم سے جڑی ہوئی ہو، یعنی جز کا کل سے مربوط ہونا، ٹھوس اور مجرد کا متضاد ہونا، کلیت کا تصور، ظاہری شکل اور اصل میں جدلیانہ کشمکش اور موضوع اور معروض کا عمل در عمل، وغیرہ۔ بقول جیمسن جدلیاتی فکر میں کوئی مقررہ اور تغیر نا آشنا معروض نہیں ہے، اور ہر معروض ایک بڑے کل سے ناقابل شکست طور پر جڑا ہوا ہے، اور سوچنے والے ذہن سے جو خود تاریخی صورتحال سے جڑا ہوتا ہے۔ جدلیاتی تنقید انفرادی فن پاروں کا الگ الگ تجزیہ نہیں کرتی، کیونکہ فرد ایک وسیع تر بڑی ساخت کا حصہ ہے جو ایک روایت یا تحریک بھی ہوسکتی ہے ۔ سچا جدلیاتی نقاد ادب پر پہلے سے طے شدہ زمروں کا اطلاق نہیں کرتا، وہ اس بات کا بھی لحاظ کرتا ہے کہ خود اس کے منتخب کردہ زمرے مثلاََ اسلوب، کردار، امیج وغیرہ بالآخر خود اس کی تاریخی صورتحال کا جُز ہیں۔ مارکسی جدلیاتی تنقید کو ہمیشہ اپنے تاریخی مآخذ کا احساس ہونا چاہیے اور تصورات کو ہرگز جامد نہ ہونے دینا چاہیے تاکہ حقیقت کا صحیح ادراک ممکن ہو۔ بے شک ہم زماں کے اندر اپنی موضوعی حالت سے باہر نہیں آسکتے، لیکن خیالات کے سخت ہوتے ہوئے خول کو توڑ سکتے ہیں تاکہ حقیقت کی بہتر طور پر تفہیم کرسکیں۔
جیمسن کی کتاب THE POLITICAL UNCONSCIOUS, (1981) میں جدلیاتی فکر کے تسلسل کے ساتھ متعدد متضاد عناصر کو سمونے کا عمل ملتا ہے، مثلاََ ساختیات، پسِ ساختیات نو فرائیڈیت، التھیوسے ادورنو وغیرہ۔ جیمسن کا کہنا ہے کہ موجودہ سماج کی پارہ پارہ اور اجنبیانہ حالت میں قدیم زمانے کی اشتراکی زندگی کا تصور مضمر ہے، جس میں زیست اور تصورات سب ملے جھلے اور اجتماعی نوعیت کے تھے، جیمسن کا یہ بھی خیال ہے کہ تمام آئیڈیالوجی اقتدار حاصل کرنے اور قابو میں رکھنے (CONTAINMENT) کے طور طریقوں کی شکل ہے جو سماج کو اس بات کا موقع دیتی ہے کہ تاریخ کے تہہ نشیں تضادات کو دبایا جاسکے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ تاریخ جو ’’اقتصادی ضرورت کی وحشی حقیقت ہے‘‘
”THE BRUTE REALITY OF ECONOMIC NECESSITY”
جبر کے ان طور طریقوں کو خود ہی مسلط کرتی ہے۔ ادبی متن بھی اسی طرح عمل آراہوتا ہے، کیونکہ بالعموم متن جو حل پیش کرتا ہے، وہ خود تاریخ کے جبر کی علامت ہوتا ہے۔جیمسن نے ساختیاتی مفکر گریما کے نشانیاتی مثلث کو اپنے مقاصد کے لیے کامیابی سے برتا ہے۔ تاریخی جبر کے طور طریقے ہیئتی نمونوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ گریما کا ساختیاتی نظام ممکنہ انسانی رشتوں کے گوشواروں پر مبنی ہے۔ اسے اگر متون پر آزمایا جائے تو وہ مقامات ظاہر ہوجاتے ہیں جو نہیں کہے گئے۔ یہ نہ کہے گئے مقامات وہ تاریخ ہیں جو دبا دی گئی۔
جیمسن نے بیانیہ اور اس کی توضیح کے بارے میں بڑی کارآمد بحث کی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ بیانیہ محض ایک ادبی فارم یا طور نہیں ہے بلکہ ایک ’علمیاتی زمرہ‘ (EPISTEMOLOGICAL CATEGORY) ہے، اس لیے کہ حقیقت قابلِ فہم ہونے کے لیے خود اپنے آپ کو کہانی کے فارم میں پیش کرتی ہے۔ اور تو اور ایک سائنسی نظریہ بھی کہانی ہوسکتا ہے‘‘ (۲۶۹۔۲۶۷)۔
نارنگ کا یہ اقتباس یہیں پر ختم نہیں ہوتا۔ اگر قاری کو توفیق ہو تو اسی تسلسل میں دونوں کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے مطالعہ جاری رکھنے سے یہ انکشاف ہوجائے گا کہ لفظ بہ لفظ ترجمے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ گو کہ نارنگ انتہائی عیاری سے مختلف پیراگرافوں کو لفظ بہ لفظ ترجمہ کرنے کے باوجود ان کی ترتیب بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن راقم نے مسروقہ مواد کی شناخت کو آسان کرنے کے لیے تسلسل کو ختم نہیں ہونے دیا۔ مثال کے طور پر نارنگ پہلے ایک صفحے کا ترجمہ کرتے ہیں اس کے بعد اگلے صفحے سے ایک پیراگراف اٹھا کر دوبارہ پہلے صفحے سے ترجمے کو جاری رکھتے ہیں۔ یقیناَ اس طرح کے سرقے کو گرفت میں لانا آسان نہیں ہوتا ،کیونکہ عام قاری جب دیکھتا ہے کہ دو فقرے لفظ بہ لفظ ترجمہ ہیں،لیکن اس کے بعد آٹھ فقرے چھوڑ دیے گئے ہیں، تو وہ سوچ سکتا ہے کہ شاید یہی دو فقرے ترجمہ ہیں اور ان کا حوالہ غلطی سے نہیں دیا گیا۔ اس کے ذہن میں یہ نکتہ آسکتا ہے کہ اس کے بعد اس صفحے سے کوئی اور پیراگراف نہیں اٹھایا گیا تو وہ سرقے کے پہلو کو نظر انداز کرسکتا ہے ۔دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ نارنگ دوبارہ پہلے صفحے کی جانب پلٹتے ہیں، اور تمام و کمال ترجمہ کرکے قاری کو احمق بنانے کی بھر پور کوشش کرتے ہیں۔ قاری کو پیچیدگی سے محفوظ رکھنے کے لیے ،راقم نے یہ کوشش کی ہے کہ نارنگ کی کتاب اور دیگر ترجمہ شدہ کتابوں میں تسلسل کو قائم رکھا جائے۔اوپر والے اقتباس میں دیکھیں کہ کس طرح نارنگ نے اردو میں انگریزی کا حوالہ استعمال کیا ہے اور اسے واوین میں لکھ دیا ہے۔ گو کہ اس انگریزی اقتباس کا صفحہ نمبر نہیں دیا گیا۔ چونکہ یہ واضح ہے اس لیے اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پورا اقتباس جو یہاں پیش کیا گیا ہے، اور اس باب میں جس دیگر مواد کی نشاندہی کی گئی ہے اس کا حوالہ کہیں نہیں ہے۔ایمانداری کا تقاضا تو یہی تھا کہ مکمل باب ہی واوین میں رکھا جاتا، لیکن اس کے لیے خود کو صرف مترجم کی حد تک ہی ظاہر کیا جاسکتا تھا جو نارنگ کو گوارہ نہ ہوسکا۔
ایک بار پھر رامن سیلڈن کی کتاب کے اس باب کا مطالعہ کرنا ہوگا جو نارنگ کے سرقے کی بھینٹ چڑھا ہے۔ آئیں یاؤس پر لکھے گئے باب پر غور کرتے ہیں، سیلڈن کے الفاظ ملاحظہ کریں،
Jauss, an important German exponant of “reception” theory, gave a historical dimension to reader-oriented criticism. He tries to achieve a compromise between Russian Formalism which ignores history, and social theories which ignores the text. Writing during a period of social unrest at the end of the 1960, Jauss and others wanted to question the old canon of German literature and to show that it was perfectly reasonable to do so…. He borrows from the philosophy of science (T.S Kuhn) the term “paradigm” which refers to the scientific framework of concepts and assumptions operating in a particular period. “Ordinary science” does its experimental work within the mental world of a particular paradigm, until a new paradigm displaces the old one and throws up new problems and establishes new assumptions. Jauss uses the term “horizon of expectations” to describe the criteria readers use to judge literary texts in any given period…. For example, if we consider the English Augustan period, we might say that Popes’s poetry was judged according to criteria, naturalness, and stylistic decorum (the words should be adjusted according to the dignity of the subject) which were based upon values of Popes’s poetry. However this does not establish once and for all the value of Pope’s poetry. During the second half of the eighteenth century, commentators began to question whether Pope was a poet at all and to suggest that he was a clever versifies who put prose into ryrhyming couplets and lacked the imaginative power required of true poetry. Leapfrogging the ninteenth century, we can say that modern readings of Pope work within a changed horizon of expectations: we now often value his poems for their wit, complexity, moral insight and their renewal of literary tradition.
In Jauss’s view it would be equally wrong to say that a work is universal, that its meaning is fixed forever and open to all readers in any period: ‘A literary work is not an object which stands by itself and which offers the same face to each reader in each period. It is not a monument which reveals its timeless essence in a monologue.’ This means, of course, that we will never be able to survey the successive horizons which flow from the time of a work down to the present day and then, with an Olympian detachment. to sum up the works final value or meaning. To do so would be to ignore the historical situation. Whose authority are we to accept? That of the readers? The combined opinion of readers over time? (Raman Seldon. P,52-53).
اس اقتباس کے بعد پروفیسر سیلڈن ویلیمز بلیک کی مثال دینے لگتے ہیں اور نارنگ بھی اپنے سرقے کا کام جاری رکھتے ہیں، آئیں نارنگ کے مجرمانہ فعل کو دیکھتے ہیں،
’’روبرٹ یاؤس نے نظریہ قبولیت کے ذریعے ’قاری اساس تنقید‘ کو تاریخی جہت عطا کی ہے۔ یاؤس نے روسی ہیئت پسندی (جس نے بڑی حد تک تاریخ کو نظر انداز کیا تھا) اور سماجی نظریوں میں (جو متن کو نظر انداز کرتے ہیں)ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔۔۔۱۹۶۰میں جب جرمنی میں اضطراب کا دور تھا۔ یاؤس اور اس کے ساتھیوں نے جرمن ادب کو پھر سے کھنگالا، اور جرمن ادبی روایت پر نئی نظر ڈالنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یاؤس کی اصطلاح ’ زمرہ‘ (PARADIGM) دراصل سائنس کے فلسفی ٹی ایس کوہن سے مستعار ہے اس سے یاؤس تصورات اور معروضات کا وہ مجموعہ مراد لیتا ہے جو کسی بھی عہد میں کارفرما ہوتا ہے۔ سائنس میں ہمیشہ تجرباتی کام کسی ایک خاص ’زمرے‘ کی ذہنی دنیا میں انجام پاتا رہتا ہے حتٰی کہ تصورات کا کوئی دوسرا ’زمرہ‘ پہلے ’زمرے‘ کو بے دخل کردیتا ہے، اور اس طرح نئے تصورات اور نئے مفروضات قائم ہوجاتے ہیں۔ کسی بھی عہد کے قارئین متن کی پرکھ کے لیے جن قوانین کا استعمال کرتے ہیں، یاؤس ان کے لیے ’افق اور توقعات‘ (HORIZON AND EXPECTATIONS) کی اصطلاحیں استعمال کرتا ہے جو’ زمرے‘ کے سائنسی تصور پر مبنی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم انگریزی شاعری کے آگسٹن دور پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ پوپ کی شاعری اس وقت کے ادبی افق اور توقعات کے عین مطابق تھی۔ چنانچہ اس وقت اس کی سلاست و قدرت، شائستگی اور شکوہ، اور اس کے خیالات کے فطرت کے مطابق ہونے کی داد دی گئی۔تاہم اس زمانے کے ادبی افق اور توقعات کی رو سے پوپ کی شاعری کی قدر و قیمت ہمیشہ کے لیے طے نہیں ہوگئی۔ چنانچہ اٹھارویں صدی کے نصف دوئم کی انگریزی تنقید میں اکثر یہ سوال اٹھایا جانے لگا کہ کیا پوپ واقعی شاعر تھا، یا وہ محض ایک قادر الکلام ناظم تھا جس نے نظم میں قافیے ڈال کر اسے منظوم کردیا۔سچی شاعری کے لیے جو تخیل شرط ہے، کیا وہ پوپ کے یہاں ہے یا نہیں۔ بیسویں صدی میں اس بارے میں پھر تبدیلی ہوئی۔ ادھر دیکھیں تو پوپ کی جدید قرأتیں ایک بدلے ہوئے ذہنی افق اور دوسری طرح کی توقعات کے ساتھ ملتی ہیں۔ آج کل پوپ کی شاعری کو ایک ہی رنگ میں دیکھا جارہا ہے۔ یعنی صناعی کے علاوہ اس میں مزاح، اخلاقی بصیرت اور روایت کی علم برداریت، یہ سب خوبیاں تلاش کرلی گئی ہیں، اور قدر کی نگاہوں سے دیکھی جانے لگی ہیں‘‘( نارنگ، ص، ۳۰۴۔۳۰۳)۔
نارنگ کا سرقہ ابھی جاری ہے، صرف صفحہ تبدیل کرنے سے عیاں ہوجاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، اور اس کے بعد نارنگ کی تعریفوں کے پل باندھنے کی بجائے اس حرکت کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کی اخلاقی و ادبی جرأت پیدا کریں۔ سیلڈن کا پیراگراف وہی ہے جو اوپر پیش کیا گیا ہے۔نارنگ کا سرقہ اسی کا تسلسل ہے۔
’’یاؤس کہتا ہے کہ یہ سوچنا غلط ہے کہ کوئی بھی فن پارہ تمام زمانوں کے لیے ہے یا آفاقی ہے، یا اس کے جو معنی خود اس کے زمانے میں متعین ہوگئے، وہی معنی ہر عہد میں قاری پر واجب ہیں۔ ادبی فن پارہ ایسی چیز نہیں جو قائم بالذات ہو، اور جو ہر عہد میں قاری کو ایک ہی چہرہ دکھاتا ہو۔ بقول یاؤس فن پارہ کوئی یاد گار تاریخی عمارت نہیں، جو تمام زمانوں سے ایک ہی زبان میں بات کرئے گی۔ گویا ادب کی دنیا میں ہم کسی ایسے’ افق اور توقعات‘ کا تصور قائم نہیں کرسکتے جو سب زمانوں کے لیے ہو۔ ایسا کرنا تاریخی حالت کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ یعنی ہم کس کو صحیح مانیں، سابقہ قارئین کی رائے کو، یا مابعد کے قارئین کی رائے کو، یا خود اپنے دور کی قارئین کی رائے کو‘‘ ( نارنگ ،ص ۳۰۶۔ ۳۰۵)۔ اس کے بعد ویلیمز بلیک کے ذکر سے نارنگ نے سرقہ جاری رکھا ہوا ہے۔واضح رہے کہ کہیں بھی صفحہ نمبر نہیں دیا گیا۔ایک بار پھر رامن سیلڈن کی جانب چلتے ہیں،
The French semiotician Michael Riffaterre agrees with the Russian Formalists in regarding poetry as a special use of language. Ordinary language is practical and is used to refer to some sort of ‘reality’, while poetic language focuses on the message as an end in itself. He takes this formalist view from Jakobson, but in a well-known essay he attacks Jakobson’s and Levi-Strauss’s interpretation of Baudelaire’s ‘Les Chats’. Riffaterre shows that the linguistic features they discover in the poem could not possibly be perceived even by an in formed reader. All manner of grammatical and phonemic patterns are thrown up by their structuralist approach, but not all the features they note can be part of the poetic structure for the reader.
However, Riffaterre has some difficulty in explainig why something perceived by Jakobson does not count as evidence of what readers perceive in a text.
Riffaterre developed his theory in Semiotics of Poetry (1978), in which he argues that competent readers go beyond surface meaning. If we regard a poem as a string of statements, we are limiting our attention to its ‘meaning’, which is merely what it can be said to represent in units of information. If we attend only to a poem’s ‘meaning’ we reduce it to a (possibly nonsensical) string of unrelated bits. A true response starts by noticing that the elements (signs) in a poem often appear to depart from normal grammar or normal representation: the poem seemes to be establishing significance only indirectly
and in doing so ‘ threatens the literary representation of realty’. It requires only ordinary linguistic competence to understand the poem’s ‘meaning’, but the reader requires’literary competence’ to deal with the frequent ‘ ungrammaticalities’ encountered in reading a poem. Faced with the stumbling-block of ungrammaticalness the reader is forced, during the process of reading, to uncover a second (higher) level of significance which will explain the grammatical features of the text. What will ultimately be uncovered is a strcutural ‘matrix’, which can be reduced to a single sentence or even a single word. The matrix can be deduced only indirectly and is not actually present as a word or statement in the poem. The poem is conected to its matrix by actual versions of the matrix in the form of familiar statements, cliches, quotations, or conventional associations. it is the matrix which ultimately gives a poem unity. this reading process can be summarised as follows:
1. Try to read it for ordinary ‘meaning‘:
2. Highlight those elements which appear umgrammatical and which obstruct on ordinary mimetic interpretation:
3. Discover the ‘hypograms’ (or commonplaces) which receive expanded or unfamiliar expression in the text;
4. Derive the ‘matrix’ from the ‘ hypograms’; that is, find a single statement or word capable of generating the ‘ hypograms’ and the text.
(Seldon, P,60-61).
نارنگ کے سرقے کی جانب چلتے ہیں،
’’مائیکل رفاٹیر شعری زبان کے بارے میں روسی ہئیت پسندوں کا ہم نوا ہے کہ شاعری زبان کا خاص استعمال ہے۔ عام زبان اظہار کے عملی پہلو پر مبنی ہے، اور کسی نہ کسی حقیقت (REALTY) کو پیش کرتی ہے، جبکہ شعری زبان اس ’اطلاع‘ پر مبنی ہے جو ہئیت کا حصہ ہے اور مقصود بالذّات ہے۔ ظاہر ہے اس معروضی ہئیتی رویے میں رفاٹیر، رومن جیکبسن سے متاثر ہے ، لیکن وہ جیکبسن کے ان نتائج سے متفق نہیں جو جیکبسن اور لیوی سٹراس نے بودلئیر کے سانٹ Les Chatکے تجزیے میں پیش کیے تھے۔ ریفا ٹیر کہتا ہے کہ وہ لسانی خصائص جن کا ذکر جیکبسن اور سٹراس کرتے ہیں، وہ کسی عام ’باصلاحیت قاری‘ کے بس کے نہیں۔ ان دونوں نے اپنے ساختیاتی مطالعے میں جس طرح
کے لفظیاتی اور صوتیاتی نمونوں کا ذکر کیا ہے، یہ خصائص کسی بھی ’ جانکار قاری‘ کی ذہنی صلاحیت کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ ایک تربیت یافتہ قاری سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ متن کو اس خاص طریقے سے پڑھے ۔ تاہم رفاٹیر یہ بتانے سے قاصر ہے کہ جیکبسن کا مطالعہ اس بات کی شہادت کیوں فراہم نہیں کرتا کہ قاری متن کا تصوّر کس طرح کرتا ہے۔رفاٹیر کے نظریے کی تشکیل اس کی کتاب:semiotics of poetry (1978) میں ملتی ہے۔ اس میں رفاٹیر نے اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے کہ باصلاحیت قاری متن کی سطح پر پیدا ہونے والے معنی سے آگے جاتا ہے۔ اگر ہم نظم کو محض معلومات کا مجموعہ سمجھتے ہیں توہم صرف اس معنی تک پہنچ پائے ہیں جو معلومات سے متعلق ہیں۔ ایک صحیح قرات ان نشانات (signs) پر توجہ کرنے سے شروع ہوتی ہیں جو عام گرامر یا عام معنی کی ترجمانی سے ہٹے ہوئے ہوں۔ شاعری میں معنی خیزی بالواسطہ طور پر عمل آرا ہوتی ہے، اور اس طرح وہ حقیقت کی لغوی ترجمانی سے گریز کرتی ہے، متن کی سطح پر کے معنی جاننے کے لیے معمولی لسانی اہلیت کافی ہے،لیکن ادبی اظہار کے رموزو نکات اور عام گرامر سے گریز کو سمجھنے اور اس کی تحسین کاری کے لیے خاص طرح کی اَدبی اہلیت شرط ہے۔ ایسے لسانی خصائص جن میں استعمالِ عام سے انحراف کیا گیا ہو، قاری کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ معنی خیزی کی داخلی سطح کو بھی دیکھے، جہاں اظہار کے اجنبی خصائص معنی سے روشن ہوجاتے ہیں ۔ نیز ان تمام مقامات پر بھی نگاہ رکھے جن میں زبان و بیان کے بعض خصائص کی تکرار ہوئی ہے۔ ریفاٹیر اسے نظم کا ساختیاتی MATRIXکہتا ہے جسے مختصر کرکے ایک کلمے یا ایک لفظ میں بھی سمیٹا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ MATRIXایک کلمے یا ترکیب کی صورت میں نظم میں موجود ہو، چناچہ اس کو متن سے اخذ کرسکتے ہیں۔ نظم اپنے ظاہریMATRIXکے ذریعے داخلیMATRIXسے جڑی ہوتی ہے۔ ظاہری MATRIX بالعموم جانے پہچانے بیانات، کلیشے، یا عمومی تلازمات اور مناسبات سے بُنا ہوتا ہے۔ نظم کی وحدت اس کے داخلی MATRIXکی دین ہے۔۔۔۔
۱۔ سب سے پہلے متن کو عام معنی کے لیے پڑھنا چاہیے۔
۲۔پھر ان عناصر کو نشان زد کرنا چاہیے، جن میں زبان کے عام گرامری چلن سے گریز ہے، اور جو حقیقت کی عام ترجمانی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔
۳۔اس کے بعد ان عام اظہارات پر نظر رکھی جائے جن کو متن میں اجنبیایا گیا ہے۔
۴۔ آخراَ ان تمام اظہارات سے داخلی Matrixاخذ کیا جائے، یعنی وہ کلیدی کلمہ یا لفظ یا ترکیب جو تمام اظہارات یا متن کو خلق generateکرتی ہو‘‘( نارنگ،ص، ۳۱۸۔۳۱۶)۔
The notion of ‘structure’, he argues, even in ‘structuralist’ theory has always presupposed a ‘centre’ of meaning of some sort. This ‘centre’ governs the structure but is itself not subject to structural analysis (to find the structure of the centre would be to find another centre). People desire a centre because it guarantees being as presence. For example, we think of our mental and physical life as centred on an ‘I’; this personality is the principle of unity which underlies the structure of all that goes on in this space. Freud’s theories completely undermine this metaphysical certainty by revealing a division in the self between conscious and unconscious. Western thought has developed innumerable terms which operate as centring principles: being, essence, substance, truth, form, begining, end, purpose, consciousness, man, God, and so on. It is important to not that Derrida does not assert the possibility of the thinking outside such term; any attempt to undo a particular concept is to become caught up in the terms which the concept depends on. For example if we try to undo the centring concept of consciousness by asserting the disruptive counter force of the ‘unconscious’, we are in danger of introducing a new centre, because we can not choose but enter the conceptual system (conscious/unconscious) we are trying to dislodge. All we can do is to refused to allow either pole in a system (body/soul, good/bad, serious/unserious) to become the centre and guarantor of presence. This desire for a centre is called ‘Logocentrism’ in Derrida’s classical work Of Grammatology. ‘Logos’ (Greek for ‘word’) is a term which in the New Testament carries the greatest possible concentration of presence: ‘ In the begning was the word’……… Phonocentrism treats writing as a contaminated form of speech. Speech seems nearer to originating thought. When we hear speech we attribute to it a presence which we take to be lacking in writing. The speech of the great actor, orator, or politician is thought to posses presence; it incarnates, so to speak, the speaker’s soul. Writing seems relatively impure and obtrudes its own system in physical marks which have a relative permanence; writing can be repeated (printed, reprinted, and so on) and this repition invites interpretation and reinterpretation. Even when a speech is subjected to interpretation it is usually in written form. Writing does not need the writer’s presence, but speech always implies an immediate presence. The sounds made by a speaker evaporate in the air and leave no trace (unless recorded), and therefore do not appear to contaminate the originating thought as in writing. Philosophers have often expressed there dislike of writing; they fear that it will destroy the authority of philosophic truth. This Truth depends upon pure thought ( logic, ideas, propositions) which risk contamination when written. Francis bacon ………… (Seldon, 144-145).
اس وقت ضروری یہ ہے کہ نارنگ کے سرقے کی نشاندہی کی جائے:
’’ساختیات سے بحث کرتے ہوئے دریدا کہتا ہے کہ ساختیاتی فکر میں ساخت (سٹرکچر) کا تصور اس مفروضے پر قائم ہے کہ معنی کا کسی نہ کسی طرح کا مرکز ((Centreہوتا ہے۔ یہ مرکز ساخت کو اپنے تابع رکھتا ہے، لیکن خود اس مرکز کو تجزیے کے تابع نہیں لایا جاسکتا ( ساخت کے مرکز کی نشاندہی کا مطلب ہوگا دوسرا مرکز تلاش کرنا) انسان ہمیشہ مرکز کی خواہش کرتا ہے اس لیے کہ مرکز ’موجودگی‘ کی ضمانت ہے:
CENTRE GUARANTEES BEING AS PRESENCEمثال کے طور پر ہم اپنی ذہنی اور جسمانی زندگی کو مرکزیت عطا کرتے ہیں ضمیر ’میں‘ کے استعمال سے ضمیر’میں‘ یا ’ہم‘ کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ فرض کیجیے زبان میں ضمیر ’میں‘ یا ’ہم‘ نہ ہوں تو ہم اپنی ’ موجودگی‘ کا اثبات کیسے کریں گے۔ الغرض ’موجودگی‘ اس وحدت کا اصول ہے جو دنیا کی تمام سرگرمیوں کی ساخت کی تہہ میں کارفرما ہے۔ دریدا کا کہنا ہے کہ فرائڈ نے شعور اور لاشعور کی تقسیم کو بے نقاب کرکے وجود کی وحدت کے مابعد الطبیعاتی اعتقاد کی جڑ کھوکھلی کردی۔ غور سے دیکھا جائے تو فلسفے کی بنیاد ہی ایسے تصورات پر ہے جو معنی کو ’مرکز‘ عطا کرنے کے اصول پر قائم ہے، مثلاََ خدا، انسان، وجود، وحدت، ’شعور‘، حق، خیر، شر، جوہر، اصل۔ دریدا یہ دعوٰی نہیں کرتا کہ ان اصطلاحات سے باہر ہوکر سوچنا ممکن ہے۔ بلکہ یہ اصطلاحات معنی کے جس ’مرکز‘ پر قائم ہیں، وہ ان میں نہیں ہے۔ فرض کیجیے کہ اگر یہ بھی کہیں کہ یہ تصورات قائم بالذات نہیں ہیں، بلکہ قائم بالغیر ہیں تو معنی کا مرکز ’غیر‘ میں بھی نہیں ہے۔ ’غیر‘ کو مرکز تسلیم کرنے کا مطلب ہوگا پھر سے اصطلاحوں میں گرفتار ہونا یا نیا مرکز تسلیم کرنا کیونکہ ’غیر‘ بھی تو قائم بالذات نہیں ہے۔ مثلاََ اگر ’شعور‘ کے مرکز کو یہ کہہ کر ختم کیا جائے کہ لاشعور کی تخریبی قوت انسانی شخصیت میں ایک رد کرنے والے معمل کے طور پر کارفرما رہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ایک نئے مرکز کو تسلیم کررہے ہیں،کیونکہ تصور کے جس نظام(شعور/لاشعور) کو ہم بے دخل UNDOکررہے ہیں۔ اس سے ہم انتخاب نہیں کرسکتے، بلکہ اس میں ہمیں خود داخل ہونا پڑے گا۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کرسکتے ہیں کہ طرفین ( شعور/لاشعور،جسم/روح، حق/باطل) میں سے کسی ایک کو مرکز بننے یا ’موجودگی‘ (PRESENCE) کا ضامن بننے کی اجازت نہ دیں۔۔۔۔۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ دریدا کے کلاسیکی کارنامے OF GRAMMATOLOGY میں لفظوں پر تصورات کے قائم ہونے کو) (LOGOCENTRISM، لفظ مرکزیت کہا گیا ہے۔LOGOSیونانی لفظ ہے نیا عہد نامہ میں LOGOSایسی اصطلاح ہے جو ’موجودگی‘ کے تصور سے لبا لب بھری ہوئی ہے۔۔۔۔ ‘IN THE BEGINING WAS THE WORD‘ (نارنگ، ص، ۲۰۸۔۲۰۷)۔
’’صوت مرکزیت PHONOCENTRISM) ) کی رو سے تحریر دراصل تقریر (تکلم) کی وہ شکل ہے جو تقریر کی ملاوٹ لیے ہوئے ہے۔ تقریر ہمیشہ اصل خیال سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ جب ہم تقریر (تکلم) سنتے ہیں تو ہم اسے ’موجودگی‘ PRESENCE) ) سے منسوب کرتے ہیں جس کی تحریر میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ کسی بھی بڑے خطیب، اداکار یا سیاست داں کی تقریر کے بارے میں برابر محسوس ہوتا ہے کہ یہ ’موجودگی‘ رکھتی ہے، یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ تقریر بولنے والے کی روح کی تجسیم ہے۔ تقریر کے مقابلے میں تحریر غیر خالص ہے اور اپنے نظام کو تحریری نشانات سے آلودہ کرتی ہے جو بے شک نسبتاََ مستقل ہیں۔ تحریر کو دہرا سکتے ہیں، محفوظ کرسکتے ہیں، بار بار چھاپ سکتے ہیں۔ اور یہ تکرار تفہیم اور باز تفہیم کے لامتناہی سلسلے کو راہ دیتی ہے۔ تقریر کی بھی جب تفہیم کی جاتی ہے تو بالعموم ایسا اس کو ضبطِ تحریر میں لاکر ہی ممکن ہے۔ تحریر کے لیے مصنف کی ’موجودگی‘ ضروری نہیں۔ اس کے برعکس تقریر سے مراد متکلم کی فوری ’موجودگی‘ ہے۔ مقرر کی آواز فوری ہوا میں تحلیل ہوجاتی ہے اور اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے تقریر کے خیال میں ملاوٹ کا شائبہ نہیں، جو تحریر میں ممکن ہے۔ قدیم فلسفہ دانوں نے اسی لیے تحریر کی مخالفت کی ہے، کیونکہ وہ خائف تھے کہ تحریر سے فلسفیانہ صداقت کا تحکم ختم ہوجائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ صداقت خالص فکر پر مبنی ہے (منطق،خیالات،قضایا) ان کو تحریر سے آلودگی کا خدشہ تھا۔ فرانسس بیکن ۔۔۔۔۔۔ ۔۔ ‘‘ جاری ہے (نارنگ،ص،۲۱۰)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ڈاکٹر نارنگ کاایک اور سرقہ شدہ اقتباس
جوعمران کے پہلے چار مضامین میں پیش کردہ اقتباسات کے بعد کا ہے
In the context of his own concept of ideology, and also of the work of Roland Barthes on literature and Jacques Lacan on psychoanalysis, it is possible to construct an account of some of the implications for critical theory and practice of Althusser’s position. The argument is not only that literature re-presents the myths and imaginary versions of real social relationships which constitutes ideology, but also that classic realist fiction, the dominant literary form of the nineteenth century and arguably of the twentieth, ‘interpellates’ the reader, addresses itself to him or her directly, offering the reader as the place from which the text is most ‘obviously’ intelligible, the position of the subject (and of) ideology.
According to Althusser’s reading (rereading) of Marx, ideology is not simply a set of illusions, as The German Ideology might appear to argue, but a range of representations (images, stories, myths) concerning the real relations in which people live. But what is represented in ideology is ‘not the system of the real relations which govern the existence of individuals, but the imaginary relation of those individuals to the real relations in which they live’ (Athusser, 1971: 155). In other words, ideology is both a real and an imaginary relation to the world-real in that it is the way that people really live there relationship to the social relations which govern their existence, but imaginary in that it discourages a full understanding of these conditions of existence and the ways in which people are socially constituted within them. It is not, therefore, to be thought of as a system of ideas in people’s heads, nor as the expression at a hihger level of real material relationships, but as the necessary condition of action within the social formation. Althusser talks of ideology as a ‘material practice’ in this sense: it exists in the behaviour of people acting according to their beliefs (155-9).
It is important to stress of course, that ideology is by no means a set of deliberate distortions foisted upon a helpless populace by a corrupt and a cynical bourgeoise. If there are sinister groups of men in shirt-sleeves purveying illusions to the public, these are not the real makers of ideology. In that sense, it has no creators. But, according to Althusser, ideological practices are supported and reproducedin the institutions of out society which he calls Ideological State Apparatuses (ISAs). Unlike the Repressive State Apparatus, which works by force (the police, the penal system and the army), the ISAs pursuade us to consent to the existing mode of production.
The central ISA in contemporary capitalism is the educational system, which prepares the childer to act in accordance with the values of society, by inculcating in them the dominant versions of appropriate behaviour as well as history, social studies and, of course, literature. Among the allies of the educational ISA are the family, the law, the media and the arts, each helping to represent and reproduce the myths and beliefs necessary to induce people to work within the existing social formation.
The destination of all ideology is the subject. The subject is what speaks, or signifies, and it is the role of ideology to construct people as subject:
The obviousness of subjectivity as the origin of meaning and choice has been challenged by the linguistic theory which has developed on the basis of Saussure’s. As Emile Benveniste argues, it is language which provides the possibility of subjectivity, because it is language which enables the speakers to posit himself or herself ‘I’, as the subject of a sentense. It is in language, inother words, that people constitute themselves as subjects. Consciousness of self is possible only on the basis of the differentiation: ‘I’ can no be signified or concieved without the conception ‘non-I’, ‘You’, and dialogue, the fundamental condition of language, implies a reversible polarity between ‘I’ and ‘You’. ‘Language is possible only because each speaker sets himself up as a subject by referring to himself as I’ (Benveniste 1971:225). But if in language there are only differences with no positive terms, as Saussure insists, ‘I’ designates only the subject of a specific utterence.
‘It is literally true that the basis of subjectivity is in the exercise of language’ (226) (Belsey, 52-55).
اس سے پہلے کہ میں نارنگ کا سرقہ کیا ہوا اقتباس پیش کروں چند نکات ذہن میں رہنے ضروری ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ بیلسی نے جہاں کہیں آلتھیوسے یا ایمیلی بن ونستے کا حوالہ استعمال کیا ہے، وہاں نہ صرف یہ کہ کتاب کا نام بھی دیا ہے بلکہ صفحہ نمبر کا حوالہ بھی دیا ہے۔بیلسی کا آخری اقتباس بن ونستے کی کتاب سے لیا گیا ہے، بیلسی کی کتاب میں اسے اقتباس کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ نارنگ نے بھی یہ اقتباس اٹھایا ہے مگر بن ونستے کا کہیں کوئی حوالہ نہیں ہے۔نارنگ نے تو ۱۹۵۸میں پی ایچ ڈی کرلی تھی، انھیں تو اقتباسات پیش کرتے وقت ادبی اصولوں کو ملحوظِ خاطر رکھنا چاہیے۔ تاہم نارنگ ایسا نہیں کرتے۔ نارنگ کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ نارنگ نے جہاں انگریزی اقتباس استعمال کیا ہے وہاں نہ ہی صفحہ نمبر ہے اور نہ ہی اس اصل مآخذ کا کہیں ذکر ہے، جس سے یہ تمام اقتباس چرایا گیا ہے۔پہلے نارنگ کے چرائے ہوئے اقتباس کی جانب چلتے ہیں۔
’’آلتھیوسے کے آئیڈیولوجی کے اس تصوّر کو اگر ژاک لاکاں کی ’نوفرائیڈیت‘ اور رولاں بارتھ کی ’نئی ادبیت‘ کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو ادب اور ادبی روےّوں کے مضمرات کے بارے میں آلتھیوسے کا موقف اور کُھل کر سامنے آتا ہے۔ دلیل صرف یہ نہیں کہ ادب اُن حقیقی سماجی رشتوں کی مِتھ یا اُن کا تخیئلی مثنٰی ہے جو آئیڈیولوجی کی تشکیل کرتے ہیں، بلکہ حقیقت پسندانہ فکشن جو اُنیسویں صَدی بلکہ بڑی حد تک بیسویں صدی کا بھی حاوی رجحان ہے، قاری سے براہِ راست خطاب کرتا ہے، اور قاری کو ایسی حیثیت عطا کرتا ہے جس سے ادب آسانی سے سمجھ میں آنے والی چیز بن جاتا ہے، اور یہ حیثیت بطور’موضوع‘ نہ صرف آئیڈیولوجی کے اندر ہے بلکہ آئیڈیولوجی کی رو‘ سے ہے۔ آلتھیوسے کی مارکس کی نئی تعبیرکے مطابق آئیڈیولوجی محض تجریدی تصوّرات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ڈسکورس(مدلل بیانات)، امیجز، اور مِتھ کی نمائندگیوں کا وہ نظام ہے جو ان حقیقی رشتوں سے متعلق ہے جن میں لوگ زندگی کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آئیڈیولوجی اُن حقیقی رشتوں سے عبارت نہیں ہے افراد کا وجود جن کے تابع ہے، بلکہ یہ عبارت ہے اُس خیالی رشتے سے جو افراد اُن ٹھوس حقیقی رشتوں سے رکھتے ہیں جن کے اندر وہ زندگی کرتے ہیں۔ گویا آئیڈیولوجی دُنیا سے حقیقی رشتہ بھی رکھتی ہے اور تصوّراتی بھی، حقیقی اس لیے کہ یہ وہ طریقہ ہے جس کی رُو سے افراد اُن رشتوں کو جیتے ہیں جو وہ اُن سماجی رشتوں سے رکھتے ہیں جو اُن کے وجود کی حالتوں کا تعین کرتے ہیں۔ اور خیالی اس لیے کہ افراد خود اپنے وجود کی حالتوں کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے اور نہ ہی اُن عوامل کو جن کی رو سے وہ سماجی طور پر اُن حالتوں کے اندر مقےّد ہیں۔ آلتھیوسے کا کہنا ہے کہ آئیڈیولوجی تصورات کا ایسا نظام نہیں ہے جسے افراد اپنے ذہنوں میں لیے پھرتے ہوں، یا جس کا اظہار مادیاتی رشتوں کی کسی اعلیٰ سطح پر ہوتا ہو، بلکہ یہ ’سماجی تشکیل‘ کے اندر افراد کے عمل کی ضروری حالت ہے: ۔۔۔۔۔۔۔
آلتھیوسے نے اپنے نظریہء آئیڈیولوجی میں اس نکتے پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ آئیڈیولوجی لازماََ کوئی ایسی شئے نہیں ہے جسے بورژوازی نے محنت کش طبقے پر لاد دیا ہو۔ آئیڈیولوجی اس اعتبار سے پیدا کی نہیں جاتی کہ یہ ضرورتاََ موجود ہے۔ البتہ آئیڈیولوجیکل’معمولات‘ سماجی اداروں میں پیدا کیے جاتے ہیں، اور پروان چڑھائے جاتے ہیں۔ آلتھیوسے ان اداروں کو
IDEOLOGICAL STATE APPARATUSES
کہتا ہے۔ اس طرح وہ ان میں اور ریاستی جبر کے آلہ ہوئے کار(REPRESSIVE STATE APPARATUSES) مثلاََ پولیس، فوج، عدلیہ وغیرہ میں فرق کرتا ہے۔ ریاستی آئیڈیولوجیکل آلہ ہائے کار میں وہ سرمایہ دارانہ ماحول کے نظامِ تعلیم کو مرکزی حیثیت دیتا ہے جس کی رُو سے بچّے کے ذہن میں تاریخ ، سماجی مطالعات، اور ادبی تربیت کے ذریعے شروع ہی سے اُن اقدار کو بٹھادیاجاتا ہے جن کی سماج اجازت دیتا ہے اور جو سماج کے نظام سے ہم آہنگ ہیں۔ اس ضمن میں جو ادارے نظام تعلیم کا ساتھ دیتے ہیں یا اُس کے ساتھ کار گر رہتے ہیں، وہ ہیں خاندان، قانون، میڈیا اور آرٹ۔ یہ سب کے سب اُن ایقانات اور متھ کو رواج دیتے اور اُنھیں مضبوط بناتے ہیں، جن کی رو سے موجود’سماجی تشکیل‘ کے اندر انسان عمل پیرا ہوتا ہے۔ آئیڈیولوجی کا اصل مقام’موضوع‘ ہے، (یعنی’فرد‘ سماج کے اندر) اوراس کا اصل کام عوام کو بطور’موضوع‘ تشکیل دیتا ہے:’TO CONSTRUCT PEOPLE AS SUBJECT‘
ؒلیکن’موضوعت‘(SUBJECTIVITY) کے اس تصوّر کو اُس لسانیاتی ماڈل نے تہس نہس کر دیا ہے جو سو سیئر کے خیالات کی رو سے وجود میں آیا ہے۔ ایمیلی بن وے نستے(EMILE BENVENISTE) کے مطابق وہ زبان ہی ہے جو موضوعیت کا امکان پیدا کرتی ہے، یعنی زبان ہی کی رو سے متکلم خود کو’میں‘ کہہ کر قائم کرتا ہے جو کلمے کا موضوع ہے۔ زبان ہی کے ذریعے عام انسان بطور موضوع تشکیل پاتا ہے۔ نفسِ انفرادی کا شعور قائم ہی اس فرق پر ہے۔ ’میں‘ کا کوئی تصوّر’غیر میں‘ کے بغیر ممکن نہیں۔ اور مکالمے میں جو زبان کی بنیادی شرط ہے ، ’مَیں‘ اور ’تم‘ کے فرق کی طرفیں بدل بھی سکتی ہیں۔ زبان ممکن ہی اسی لیے ہے کہ ڈسکورس میں ہر متکلم خود کو’میں‘ کہہ کر ’موضوع‘ ہوسکتا ہے۔ لیکن اگر زبان سوسیئر کے مشہور قول کے مطابق افتراقات کا نظام ہے بغیر اثباتی عناصر کے ، تو’میں‘ کی موضوعیت فی نفسہِ قائم ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ’میں‘ محض مخصوص کلمے کا موضوع ہے۔ پس ثابت ہے کہ موضوعیت قائم ہوتی ہے زبان کے استعمال سے‘‘ (نارنگ،۲۵۸۔۲۵۶)۔
فکری سطح پر بددیانتی کی شاید ہی اس سے بدترین مثال کہیں دکھائی دے۔قاری اگر اندھا نہ ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح نارنگ نے صفحات کے صفحات محض ترجمہ کرکے اپنے نام سے شائع کرالیے ہیں۔ اوپر دیکھیں کہ کس طرح نارنگ نے یہ فقرہ انگریزی میں پیش کیا ہے، ‘TO CONSTRUCT PEOPLE AS SUBJECT‘ ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نارنگ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ صرف یہی ایک فقرہ انھوں نے انگریزی سے لیا ہے۔ ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباََ دو صفحات بیلسی کی کتاب سے دیگر ابواب کی طرح انتہائی بدیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چرائے گئے ہیں۔ نارنگ کے حواری یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ کتاب کا نام حواشی میں درج ہے۔ ایسا کہتے وقت وہ بھول جاتے ہیں کہ ترجمہ کرکے کتاب کا نام دینے سے کوئی مصنف نہیں کہلا سکتا۔ جب الفاظ کو جوں کا توں نقل کیا جاتا ہے، تو انھیں واوین میں رکھا جانا چاہیے۔ بیس مختلف کتابوں سے بیس ابواب ترجمہ کرکے کوئی مصنف نہیں کہلا سکتا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
خلاصۂ کلام اور حامیانِ نارنگ صاحب کو چیلنج کہ اسے غلط ثابت کریں
۱۔نارنگ صاحب کی کتاب کے صفحہ نمبر ۳۳سے لے کر ۳۳۴تک صرف بیس صفحات بھی ایسے نہیں ہیں جو انگریزی کتابوں کا لفظ بلفظ ترجمہ نہ ہوں۔
۲۔ ٹیرنس ہاکس کی کتاب Structuralism and Semiotics پیراگرافس کے معمولی ادل بدل کے ساتھ پوری کی پوری اپنی کتاب میں شامل کر لی ہے۔
۳۔رامن سیلڈن کی کتاب Contemporary Literary Theoryسے جو سرقہ کیا گیا ہے ،اس کی ایک جھلک۔
رامن سیلڈن کی کتاب کے صفحات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ گوپی چند نارنگ کی کتاب کے صفحات
2 7- 42۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 7 9-106
4 9- 70۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔28 8- 329
14 9- 158 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔23 4- 240
8 6- 103 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔24 3- 267
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
اس کتاب کے پہلے ایڈیشن میں بارہ صفحات پر مشتمل انگریزی حصہ شامل تھا۔
اب اُس حصہ کے مطالعہ کے لیے ’’ڈاکٹر گوپی چند نارنگ اور مابعد جدیدیت‘‘
کے پہلے ایڈیشن تک ہی رسائی حاصل کرنا ہو گی۔۔یہاں کتاب کی اشاعت
کے بعد اسی حوالے سے لکھے گئے اپنے دو مضامین شامل کر رہا ہوں اور اس کی
ساتھ اپنی کتاب’’ہمارا ادبی منظر نامہ‘‘کے اختتامیہ کا وہ حصہ بھی شامل کر رہا ہوں
جس میں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ صاحب کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ان
مضامین کے ساتھ جدید ادب کا ایک متعلقہ اداریہ بھی شامل کر لیا گیا ہے۔