تازہ ترین
کتب

اُردو زبان میں لکھا گیا محترمہ پریشے گل کا ناول ’’یوں ملے ہم‘‘ اب پنجند ویب سائٹ اور پنجند بُکس ایپ سے گُوگل پلے سٹور اور ایپل ایپ سٹور پر مفت حاصل کریں۔ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی بانٹیں۔ اردو زبان اور اپنی دیگر مقامی زبانوں کو فروغ دینے میں اپنا حصہ ڈالیں۔
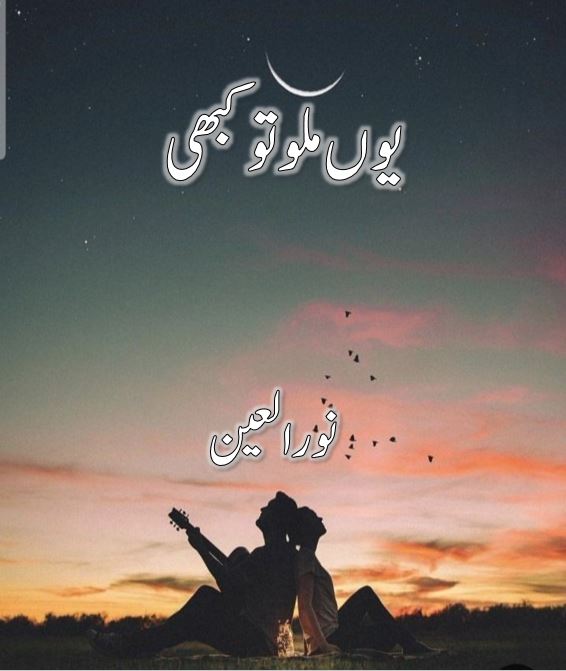
اُردو زبان میں لکھا گیا محترمہ نورالعین کا ناول ’’یوں ملو تو کبھی‘‘ اب پنجند ویب سائٹ اور پنجند بُکس ایپ سے گُوگل پلے سٹور اور ایپل ایپ سٹور پر مفت حاصل کریں۔ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی بانٹیں۔ اردو زبان اور اپنی دیگر مقامی زبانوں کو فروغ دینے میں اپنا حصہ ڈالیں۔
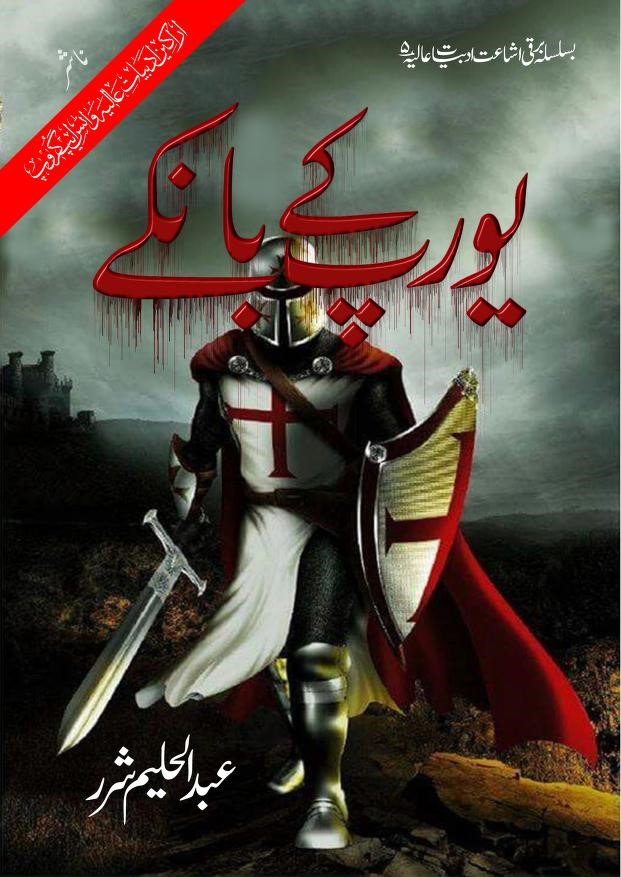
اُردو زبان میں لکھی گئی محترم عبدالحلیم شرر کی کتاب’’یورپ کے بانکے‘‘ اب پنجند ویب سائٹ اور پنجند بُکس ایپ سے گُوگل پلے سٹور اور ایپل ایپ سٹور پر مفت حاصل کریں۔ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی بانٹیں۔ اردو زبان اور اپنی دیگر مقامی زبانوں کو فروغ دینے میں اپنا حصہ ڈالیں۔

اُردو زبان میں لکھا گیا محترمہ فریحہ چوہدری کا ناول ’’یہ کھیل قسمت کے‘‘ اب پنجند ویب سائٹ اور پنجند بُکس ایپ سے گُوگل پلے سٹور اور ایپل ایپ سٹور پر مفت حاصل کریں۔ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی بانٹیں۔ اردو زبان اور اپنی دیگر مقامی زبانوں کو فروغ دینے میں اپنا حصہ ڈالیں۔

اُردو زبان میں لکھا گیا محترمہ زرنیلا خان کا ناول ’’یہ عشق نہیں آساں‘‘ اب پنجند ویب سائٹ اور پنجند بُکس ایپ سے گُوگل پلے سٹور اور ایپل ایپ سٹور پر مفت حاصل کریں۔ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی بانٹیں۔ اردو زبان اور اپنی دیگر مقامی زبانوں کو فروغ دینے میں اپنا حصہ ڈالیں۔
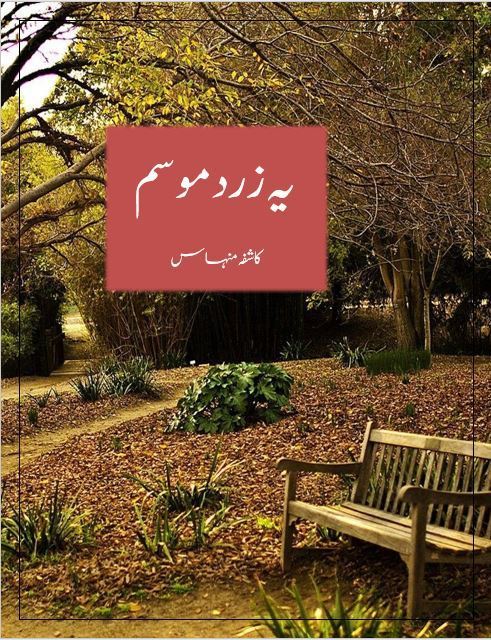
اُردو زبان میں لکھا گیا محترمہ کاشفہ منہاس کا ناول ’’یہ زرد موسم‘‘ اب پنجند ویب سائٹ اور پنجند بُکس ایپ سے گُوگل پلے سٹور اور ایپل ایپ سٹور پر مفت حاصل کریں۔ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی بانٹیں۔ اردو زبان اور اپنی دیگر مقامی زبانوں کو فروغ دینے میں اپنا حصہ ڈالیں۔

اُردو زبان میں لکھا گیا محترمہ عاتکہ کا ناول ’’یہ رنگ کچے نہیں‘‘ اب پنجند ویب سائٹ اور پنجند بُکس ایپ سے گُوگل پلے سٹور اور ایپل ایپ سٹور پر مفت حاصل کریں۔ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی بانٹیں۔ اردو زبان اور اپنی دیگر مقامی زبانوں کو فروغ دینے میں اپنا حصہ ڈالیں۔
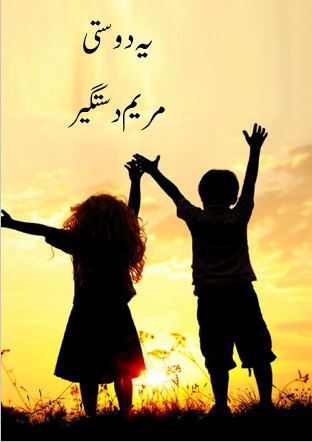
اُردو زبان میں لکھا گیا محترمہ مریم دستگیر کا ناول ’’یہ دوستی‘‘ اب پنجند ویب سائٹ اور پنجند بُکس ایپ سے گُوگل پلے سٹور اور ایپل ایپ سٹور پر مفت حاصل کریں۔ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی بانٹیں۔ اردو زبان اور اپنی دیگر مقامی زبانوں کو فروغ دینے میں اپنا حصہ ڈالیں۔

