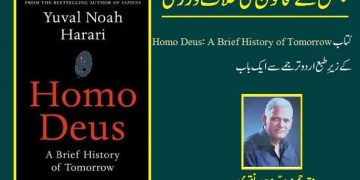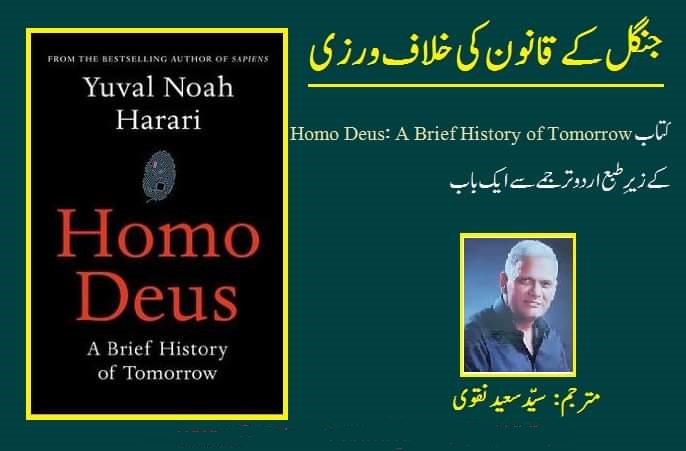(کتاب Homo Deus: A Brief History of Tomorrow کے زیرِطبع اردو ترجمے سے ایک باب)
تیسری اچھی خبر یہ ہے کہ اب جنگیں بھی نظر نہیں آتیں۔تمام تاریخ انسان جنگوں کو لازمی سمجھتے رہے، جب کہ امن کو ایک نازک اور عارضی صورت سمجھا جاتا۔بین الاقوامی تعلقات پر جنگل کا قانون لاگو تھا، جس کے مطابق اگر دو حکومتیں پر امن رہ رہی ہوں تب بھی جنگ ہمیشہ ایک امکان تھا۔ مثال کے طور پر اگرچہ جرمنی اور فرانس 1913 میں پر امن تھے، لیکن سب ہی جانتے تھے کہ وہ 1914 تک دست و گریباں ہوسکتے ہیں۔ جب بھی سیاست دان، جرنیل، تاجر اور عام شہری مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے تو اس میں ہمیشہ جنگ کے امکان کو مد نظر رکھا جاتا۔ پتھر کے دور سے بھاپ کے زمانے تک، اور آرکٹک سے صحارا تک، زمین کا ہر باشندہ جانتا تھا کہ کسی بھی وقت اس کا ہمسایہ اس کی زمین پر حملہ آور ہوسکتا تھا، اس کی فوج کو شکست دے کر، اس کی آبادی کوختم کرکے ، اس کے علاقے پر قابض ہوسکتا تھا۔
بیسویں صدی کے وسط میں جنگل کا یہ قانون اگر ختم نہیں ہوا تو توڑ ضرور دیا گیا ہے۔ بیشتر علاقوں میں جنگ پہلے کی نسبت کمیاب ہوگئی۔ جب کہ قدیم زرعی معاشروں میں تشددپندرہ فیصد اموات کا ذمہ دار تھا، بیسویں صدی میں تشدد صرف پانچ فیصد اموات کا اور اکیسویں صدی کی ابتدا میں عالمی اموات کا صرف ایک فیصد تشدد کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ 2012 میں تقریبا پانچ کروڑ ساٹھ لاکھ افراد ساری دنیا میں فوت ہوئے، ان میں سے چھ لاکھ بیس ہزار انسانی تشدد کے ہاتھوں ہلاک ہوئے (ایک لاکھ بیس ہزار افراد جنگ میں اور پانچ لاکھ افراد جرائم پیشہ کے ہاتھوں)۔ اس کے مقابلے میں آٹھ لاکھ افراد نے خود کشی کی تھی، جب کہ پندرہ لاکھ افراد ذیابطیس کے ہاتھوں مرے۔ اب شکربارود سے زیادہ خطرناک ہوگئی ہے۔
زیادہ اہم بات یہ ہے کہ نوع انساں کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد اب جنگ کو ناقابل فہم سمجھنے لگی ہے۔ تاریخ میں پہلی بار جب حکومتیں، کارپوریشن اور نجی افراد مستقبل قریب کی منصوبہ بندی کرتے ہیں تو ان میں سے اکثر جنگ کا امکان نہیں گردانتے۔ جوہری ہتھیاروں نے عالمی طاقتوں کے درمیان جنگ کو ایک اجتماعی خود کشی بنا دیا ہے۔ جس سے دنیا کی طاقت ور ترین قومیں اب تنازعات کو حل کرنے کے دوسرے طریقے تلاش کرتی ہیں۔ساتھ ہی عالمی اقتصادیات اب اشیا پر مبنی اقتصادیات کے بجائے علم پر مبنی اقتصادیات میں تبدیل ہوگئی ہے۔ پہلے تمول کی بنیاد اشیا کی ملکیت پر ہوتی تھی مثلا سونے کی کانیں، گندم کے کھیت اور تیل کے کنویں۔ آج تمول کی اہم بنیاد علم ہے۔ گو آپ تیل کے کنوئوں پر جنگ کے ذریعے قابض ہوسکتے ہیں، آپ اس طرح علم حاصل نہیں کرسکتے۔ لہذا جب علم تمول کا سب سے اہم عنصر بن گیا تو جنگوں کا فائدہ کم ہوگیا، اور جنگیں دنیا کے ان علاقوں تک محدود ہوگئیں جہاں اقتصادیات اب بھی قدیم اشیا کی ملکیت پر مبنی ہے، مثلا مشرق وسطی اور وسطی افریقہ۔
1988ء میں روینڈا کا ہمسایہ کانگو کی کولٹن کانوں پر قبضہ کرکے لوٹ مار کرنا قابل فہم ہے۔ کیوں کہ یہ دھات موبائل فون اور گودی کمپیوٹر (Laptop)کی تعمیر میں استعمال ہوتی ہے، اور کولٹن کے اسی فیصد ذخائر کانگو میں پائے جاتے ہیں۔ روانڈا نے اس لوٹے ہوئے کولٹن سے چوبیس کروڑ ڈالر سالانہ کی آمدنی حاصل کی۔ غریب روانڈا کے لیے یہ بہت خطیر رقم تھی۔ اس کے مقابلے میں چین کا کیلی فورنیا پر حملہ کرکے سلی کون وادی پر قابض ہوجانا فضول ہوگا۔ کیوں کہ اگر کسی طرح چین میدان جنگ میں حاوی ہو بھی جائے تب بھی اس وادی سلی کون وادی پر قابض ہوجانا فضول ہوگا۔ کیوں کہ اگر کسی طرح چین میدان جنگ میں حاوی ہو بھی جائے تب بھی اس وادی سلی
لیکن ہمیں اہلیت اور نیت کے درمیان فرق کو یاد رکھنا چاہیے۔اگرچہ سائبر جنگ سے تباہی کے نئے امکانات نے جنم لیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے ان کے استعمال کی خواہش بھی پیدا ہوئی ہے۔گزشتہ ستر سالوں میں نوع انساں نے نہ صرف جنگل کے قانون کو توڑا ہے بلکہ چیخوف کے قانون کو بھی۔اینٹون چیخوف کا قول مشہور ہے کہ اگر پہلے ایکٹ میں بندوق نظر آئے، تو تیسرے ایکٹ تک وہ یقینا استعمال بھی ہوگی۔تمام تاریخ میں اگر شہنشاہ اور بادشاہ کوئی نیا ہتھیار اپنانے میں کامیاب ہوئے تو جلد یا بدیر انہیں اس کے استعمال کی خواہش بھی ہوئی، لیکن 1945 سے بہر حال نوع انساں کو اس خواہش پر قابو پانا آگیا ہے۔ وہ بندوق جو سرد جنگ میں پہلی بار نمودارہوئی تھی کبھی استعمال نہیں ہوئی۔ اب ہم ایسی دنیا میں رہنے کے عادی ہوگئے ہیں جو بغیر چلے بموں اور بغیر داغے میزائلوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم چیخوف اور جنگل دونوں کے قوانین کو توڑنے میں ماہر ہوگئے ہیں۔ اگر کبھی ہمیں ان قوانین نے اپنی پابندی پر مجبور کیا تو یہ ہماری اپنی غلطی ہوگی، ہماری لازمی بدقسمتی کی کہانی نہیں۔
تو پھر دہشت گردی کا کیا کریں؟ اگر مرکزی حکومتیں اور طاقتور ریاستیں یہ صبر کرنا سیکھ بھی لیں، تب بھی دہشت گردوں کو نئے اورتباہ کن ہتھیاروں کے استعمال میں کوئی تامل نہیں۔یہ یقینا ایک پریشان کن امکان ہے۔ لیکن دہشت گردی کمزوری سے پیدا ہونے والی حکمت عملی ہے، جن کے پاس اصل طاقت کا فقدان ہے۔ کم از کم ماضی میں حقیقی مادی تباہی کے بجائے دہشت خوف پیدا کرکے پھیلائی جاتی تھی۔ دہشت گردوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ایک فوج کا مقابلہ کرسکیں، کسی بھی ملک پر قبضہ کریں یا پورے شہروں کو تباہ کرسکیں۔ جب 2010 میں مٹاپے اور اس سے وابستہ بیماریوں سے تیس لاکھ افراد مارے گئے تو دہشت گردی سے ساری دنیا میں 7697 افراد ہلاک ہوئے، اور ان میں سے بیشتر ہلاکتیں بھی ترقی پذیر ممالک میں ہوئیں۔ایک اوسط درجے کے امریکی یا یورپین کے لیے کوکاکولا القاعدہ سے زیادہ مہلک ہے۔
تو پھر دہشت گرد کیسے سرخی بنتے رہتے ہیں اور ساری دنیا کا منظر نامہ بدل دیتے ہیں؟ اپنے دشمنوں کو غیر ضروری رد عمل پر اکسا کر۔ اصل میں دہشت گردی ایک ڈرامہ ہے۔ دہشت گرد تشدد کا ایسا خوفناک کھیل سجاتے ہیں جو ہماری سوچ پر حاوی ہوجائے اور ہمیں یہ خوف لاحق ہو کہ ہم شاید قدیم افراتفری کی جانب لوٹ رہے ہیں۔ لہذا ریاستیں اسے اپنا فرض سمجھتی ہیں کہ وہ دہشت گردی کے ڈرامے پر ایسے تحفظ کا رد عمل کریں جس میں بھرپور قوت کا اظہار ہو، مثلا کسی مکمل آبادی کو اجتماعی سزا یا بیرونی ملک پر حملہ۔ بیشتر موقعوں پر دہشت گردی کے خلاف یہ غیر ضرور ی ردعمل ہمارے تحفظ کے لیے خود دہشت گردی سے زیادہ بڑا خطرہ ہے۔
دہشت گرد تو ایک مکھی کی مانند ہیں جو کسی برتنوں کی دکان کو تباہ کرنے کے درپے ہو۔ یہ مکھی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ ایک پیالی بھی نہیں ہلا سکتی۔ لہذا وہ ایک بیل ڈھونڈ کر اس کے کان میں بھنبھنانا شروع کردیتی ہے۔ یہ بیل غصے اور خوف سے پاگل ہوجاتا ہے اور برتنوں کی دکان تباہ کردیتا ہے۔مشرق وسطیٰ میں گزشتہ دہائی میں یہی ہوا ہے۔ اسلامی بنیاد پرست خود کبھی صدام حسین کا تختہ نہیں الٹ سکتے تھے۔ لہذا انہوں نے گیارہ ستمبر کے حملے سے امریکہ کو جنون میں مبتلا کردیا جس نے ان کے لیے برتنوں کی دکان تباہ کردی۔ ازخود یہ دہشت گرد اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں واپس قرون وسطی میں دھکیل کر دوبارہ جنگل کا قانون نافذ نہیں کرسکتے۔ وہ ہمیں اکساتے ضرور ہیں ، لیکن بالآخر ان کی کامیابی کا دارومدار ہمارے رد عمل پر ہے۔ اگر جنگل کا قانون واپس لوٹ آیا تو اس میں دہشت گردوں کا قصور نہیں ہوگا۔
آنے والی دہائیوں میں بھی شاید قحط، وبائیں اور جنگیں لاکھوں جانیں تلف کرتی رہیں گی۔ لیکن بہرحال اب وہ ناقابل گریز سانحے نہیں ہیں جو ایک بے بس نوع انسانی کی سمجھ سے باہر ہوں۔بلکہ وہ قابل دست اندازی رکاوٹیں ہیں۔ اس سے ان کروڑوں مفلس انسانوں کی مصیبتوں کو کم سمجھنا مقصود نہیں، نہ ہی وہ کروڑوں جو ہر سال ملیریا، ایڈز یا تپ دق کا شکار ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ کروڑوں جو شام، کانگو اور افغانستان میں تشدد کے خود افزائشی دائروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہاں پیغام یہ نہیں کہ قحط، وبا اور جنگ زمین سے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے ہیں اور اب ہمیں ان کے بارے میں فکر مند ہونا چھوڑ دینا چاہیے بلکہ اس کے بالکل متضاد ہے۔ تمام تاریخ لوگ انہیں ناقابل حل مسائل سمجھتے رہے لہذا انہیں ختم کرنے کی کوشش بھی نہیں ہوئی۔ لوگ خدا سے معجزوں کے لیے دعا تو مانگتے رہے، لیکن خود قحط، وبا اور جنگ کو روکنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ 2016 کی دنیا بھی اتنی ہی پر تشدد، بھوکی اور بیمار ہے جتنی کہ 1916 میں تھی، وہ اسی پرانی شکست خوردہ سوچ کو پرورش دے رہے ہیں۔ان کے مطابق انسانوں نے بیسویں صدی میں جو زبردست کوششیں کیں ان سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔طبی تحقیق، اقتصادی اصلاحات اور امن کی کوششیں سب بے کار رہی ہیں۔ اگر یہ درست ہے تو طبی تحقیق ، انوکھی ا قتصادی اصلاحات اور امن کی نئی کوششوں پر وقت اور وسائل ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہے؟
گزشتہ کامیابیوں کا اعتراف امید کا پیغام ہے۔ تاریخ خلا کو برداشت نہیں کرتی۔اگر قحط، جنگ اور وبائوں کی تعداد کم ہورہی ہے تو انسانی قاعدے میں یقینا کوئی چیز ان کی جگہ لے لے گی۔ ہمیں بہت سوچ کر یہ طے کرنا چاہیے کہ ان کی جگہ کون لے گا۔ ورنہ ممکن ہے کہ ہم جنگ کے پرانے میدانوں میں تو فتح حاصل کرلیں، مگر اپنے آپ کو نئے محاذوں پر الجھا دیکھیں۔ اکیسویں صدی میں انسانی قاعدے کے وہ کون سے منصوبے ہیںجو قحط، وبا اور جنگ کی جگہ لے سکیں۔
ایک اہم منصوبہ تو نوع انساں اور سیارے کو خود اپنی ہی طاقت کے خطرات سے محفوظ رکھنا ہے۔ شاندار اقتصادی ترقی کی وجہ سے ہم جنگ، وبا اور قحط پر قابو پا سکے ہیں، جس سے ایندھن، غذا ، دوائیں اور خام مال فراواں ہوگیا ہے۔ لیکن یہی ترقی سیارے کے ماحولیاتی توازن کو کئی متنوع طریقوں سے متاثر کررہی ہے، جس کا اندازہ لگانا تو ابھی ہم نے شروع کیا ہے۔نوع انساں نے اس خطرے کا بہت دیر سے احساس کیا ہے اور ابھی تک اس کے سدباب کے لیے زیادہ کچھ کیا بھی نہیں ہے۔ ماحولیاتی آلودگی، ماحولیاتی حرارت اور بدلتے موسموں کی تمام تر بحث کے باوجود بیشتر ممالک نے ابھی تک کوئی سنجیدہ سیا سی یا اقتصادی قربانی نہیں دی کہ جس سے حالات بہتر ہوسکیں۔ جب بھی وقت آتا ہے کہ اقتصادی ترقی یا ماحولیاتی آلودگی میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جائے تو سیاست دان، کمپنیوں کے سربراہ اور رائے دہندگان ہمیشہ ترقی کو ترجیح دیتے ہیں۔اکیسویں صدی میں اگر ہم تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے بہتر کارکردگی دکھانی ہوگی۔
انسانیت اس کے علاوہ کس چیز کی تمنا کرے گی؟ کیا ہم محض اپنی کامیابیوں پر ہی مطمئن رہیں گے۔ قحط، وبا اور جنگ سے بچائو ہی ممکن رکھیں گے، اور ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھیں گے؟ یہی شاید سب سے بہتر راستہ ہے، لیکن نوع انساں کا اس پر سفر کا امکان نہیں۔ انسان کبھی حال سے مطمئن نہیں ہوتا۔ کسی بھی کامیابی کے حصول پرانسانی ذہن کا سب سے عام ردعمل مزید کی تلاش ہے۔ انسان ہمیشہ بہتر، زیادہ اور خوبصورت کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب نوع انساں کو یہ زبر دست نئی طاقت حاصل ہوچکی ہوگی، اور جب قحط، جنگ اور وبا آخر کار بالکل خٹم ہوجائیں گے تو ہم اپنے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ پھر سائنس داں، سرمایہ کار، بینکر اور سربراہاں مملکت سارا دن کیا کریں گے؟ شاعری کریں گے؟
کامیابی امنگوں کو جنم دیتی ہے۔ ہماری جدید کامیابیاں نوع انساں کو اور زیادہ جرات مندانہ مقاصد کے حصول پر اکسا رہی ہیں۔تمول، صحت اور امن کے حصول میں بے مثال کامیابیوں کے بعد، اپنی پرانی تاریخ اور موجودہ اخلاقیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسانیت کے آئندہ نصب العین یقیناـ ابدیت، مسرت اور خدائی کا حصول ہوگا۔ اب قحط،بیماری اور تشدد پر قابو پالینے کے بعدہمارا نصب العین بڑھاپے اور خود موت پر قابو پانا ہوگا۔افراد کو انتہائی مصائب سے چھٹکارہ دلانے کے بعد اب ہم انہیں شادمانی دلانے کی کوشش کریں گے۔ انسانیت کو اپنی بقا کی جہد مسلسل سے نکالنے کے بعد اب ہمارا مقصد انہیں خدائی کے درجے پر فائز کرنا ہوگا، انہیں ہومو سیپین سے بلند کرکے ہومو ڈیوس (Homo Deus)بنانا ہوگا۔
**
Homo Deus: A Brief History of Tomorrow
Book by Yuval Noah Harari
اردو ترجمہ بعنوان “مستقبل کی تاریخ” (مترجم : سیّد سعید نقوی)